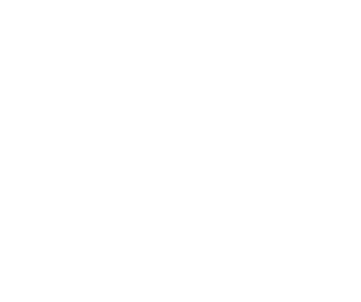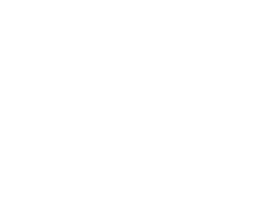اسے دیکھنا۔ کہانی کار: نکول کروث (ترجمہ: محمد ابراہیم)
مجھے طائفے میں ایک برس سے زیادہ ہو گیا تھا۔ جب سے میں نے اس رقصگر کا کام دیکھا تھا میری خواہش تھی کہ اس کے ساتھ کام کروں اور اس مقصد کا حصول پوری ایک دہائی سے میری امنگوں کا محور تھا۔ برسوں کی ریاضت کے دوران میں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا تھا۔ جب میرے آڈیشن کے بعد مجھے بلاوا آیا تو میں نے سب چھوڑ چھاڑ کر تل ابیب کی پرواز پکڑی۔ ہم دوپہر سے شام پانچ تک ریاض کیا کرتے تھے، میں نے رقص گر کے نظم اور اس کے تصورِ رقص کیلیے اپنا آپ مکمل طور پر وقف کر دیا اور پوری طرح سے جان کھپا دی۔ بعض اوقات کوئی شے تیزی سے اٹھان لیتی، پھوٹ پڑتی، اور آنسو آپ ہی آپ امنڈ آتے۔ شراب خانے یا قہوہ گھر میں لوگوں سے ملنا ہوتا تو میں بڑے جوش و خروش سے اپنے رقصگر کے ساتھ کام کے تجربے کے بارے میں بتاتی، کہتی کہ مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں عرفان کی دہلیز پر کھڑی ہوں۔ پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ مجھے خبط ہو چکا تھا، جسے میں ریاضت سمجھی تھی وہ حد سے گزر کر کچھ اور ہی بن چکا تھا۔ یہ احساس ایسا تھا جیسے میری تب تک کی بسیط شادمانی پر ایک سیاہ دھبا لگ گیا ہو، لیکن اس احساس کا کیا کیا جائے، یہ مجھے معلوم نہ تھا۔
مشق کرنے کے بعد تھکی ہاری میں ساحل پر چلی جاتی، یا گھر جا کر کوئی فلم دیکھتی جب تک کہ باہر جا کر لوگوں سے میل جول کا وقت نہ ہو جاتا۔ میں جی بھر ساحل کی سیر پر نہ جا پاتی تھی کیونکہ رقصگر کا مطالبہ تھا کہ ہمارے پورے بدن کی جلد اتنی ہی گوری ہونی چاہیے تھی جتنی ہماری زیریں پشت گوری تھی۔ میرے ٹخنے میں سوزش ہو گئی تھی جس کے وجہ سے ناچنے کے بعد اس پر برف کی ٹکور کرنا ضروری ہو جاتا، اور یوں میں خود کو ایک پاؤں اٹھائے، کمر کے بل لیٹ کر بیسیوں فلمیں دیکھنے میں مصروف پانے لگی۔ میں نے جاں لوئی تراتینیاں (Jean-Louis Trintignant) کا سبھی کام دیکھ ڈالا، پھر وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی قریب الوقوع موت کے خیال سے جی بوجھل ہونے لگا۔ پھر میں نے لوئی گیرل (Louis Garrel) کا انتخاب کیا، اس کا حسن ہی اسے امر رکھنے کیلیے کافی ہے۔ کبھی میری سہیلی رومی فارغ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ آ ملتی۔ گیرل کی فلمیں ختم ہوئیں تو سردی آ چکی تھی، سو تیراکی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لہذا میں دو ہفتے انگمار برگمن (Ingmar Bergman) کو لے کر اندر پڑی رہی۔ جب نیا سال شروع ہوا تو میں نے برگمن اور ہر رات چرس پھونکنے کی جان چھوڑنے کا تہیہ کیا۔ اور ایرانی ہدایتکار عباس کیاروستامی کی فلم ’چیری کا ذائقہ‘ ڈاؤن لوڈ کی، ایک تو فلم کا نام بڑا جاذب تھا دوسرے یہ سویڈن سے بہت دور بنائی گئی تھی۔
فلم کا آغاز اداکار ہمایوں ارشادی کے چہرے سے ہوتا ہے۔ وہ آقائے بدیعی کا کردار ادا کرتا ہے، ایک ادھیڑ عمر آدمی جو تہران کی سڑکوں پر کسی کی تلاش میں آہستگی سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے۔ وہ مزدوری کی خاطر غل مچاتے مزدوروں کے ہجوم پر نگاہ ڈالتا جاتا ہے۔ جب اسے اپنے مطلب کی چیز نہیں ملتی تو وہ شہر کے باہر کی جھلسی ہوئی پہاڑیوں کا رخ کرتا ہے۔ اسے سڑک کنارے ایک آدمی ملتا ہے، وہ گاڑی کی رفتار کم کرتا اور اسے گاڑی میں بیٹھنے کی پیشکش کرتا ہے، وہ آدمی انکار کر دیتا ہے اور جب آغائے بدیعی مسلسل اصرار کرتا ہے تو وہ شخص طیش میں آ کر نکل چلتا ہے، اور پلٹ پلٹ کر اسے شکی نگاہوں سے تکتا جاتا ہے۔ پانچ سات منٹ مزید گاڑی چلانے کے بعد، جو کہ فلموں میں ازل کے دورانیے کے مساوی ہوتا ہے، ایک جواں سال فوجی آتا ہے جو کہ لفٹ مانگ مانگ کر سفر کر رہا ہوتا ہے، بدیعی اسے چھاؤنی تک لے چلنے کی پیشکش کرتا ہے۔ وہ لڑکے سے فوجی زندگی اور کردستان میں مقیم اس کے اہل خانہ کے متعلق پوچھنے لگتا ہے۔ جیسے جیسے سوال بے تکلف اور ذاتی قسم کے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے فوجی جز بز ہوتا جاتا ہے، جلد ہی وہ سیٹ میں بیٹھے بیٹھے پہلو بدلنے لگتا ہے۔ تقریباً بیس منٹ کے بعد بالآخر بدیعی اپنے دل کی بات کہہ ڈالتا ہے، وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو اسے دفنا دے۔ اس نے ان بے آب و گیاہ پہاڑیوں میں سے ایک کے پہلو میں اپنی قبر کھود رکھی ہے، آج رات اس کا خواب آور گولیاں کھا کر اس میں جا لیٹنے کا ارادہ ہے۔ اسے بس ایسا کوئی درکار ہے جو صبح جا کر دیکھ آئے کہ وہ واقعی مر چکا ہے، اور پھر بیس بیلچے مٹی سے اسے ڈھک دے۔
سپاہی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کود پڑتا ہے اور پہاڑیوں کی جانب بھاگ جاتا ہے۔ چونکہ خودکشی قرآن کی رو سے سراسر حرام ہے، آقائے بدیع کی پیشکش کا مطلب ہے ایک سنگین جرم میں سہولت کاری کرنا۔ کیمرہ سپاہی کا پیچھا کرتا ہے، اس کا پیکر چھوٹا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دور کہیں جا کر اوجھل ہو جاتا ہے۔ پھر کیمرا آغائے بدیع کے انوکھے چہرے کی جانب مڑ جاتا ہے۔ وہ چہرہ جو تقریباً ساری فلم میں جذبات سے عاری رہتا ہے مگر پھر بھی اس سے ایک ایسا رعب اور جذبات کی گہرائی ٹپکتی ہے جو نری اداکاری سے کبھی آ ہی نہیں سکتی، جو ناامیدی کی انتہا پر دھکیلے جانے کے احساس کی عمیق معرفت سے ہی آ سکتی ہے۔ پوری فلم میں ہمیں ایک بار بھی آقائے بدیع کی زندگی کے بارے میں کوئی بات بتائی جاتی ہے نہ ہی یہ کہ اس کے اس فیصلے کے پیچھے کیا عوامل رہے ہونگے۔ نہ ہی ہم اس کی نومیدی کا مشاہدہ کر پاتے ہیں۔ اس کے باطن میں موجود گہرائی کے بارے میں ہم جو کچھ بھی جان پاتے ہیں وہ اس کا چہرہ بتاتا ہے، اور وہی چہرہ ہمیں اداکار کے باطن کی گہرائی کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ ہمایوں ارشادی، جس کی زندگی کے بارے میں ہم اور بھی کم معلومات رکھتے ہیں۔ کچھ تحقیق کرنے پر میں نے دریافت کیا کہ وہ ایک ماہر تعمیرات تھا جسے بطور اداکار کوئی مشق یا تجربہ حاصل نہ تھا، جب کیاروستامی نے اسے ٹریفک کی بھیڑ میں اپنی گاڑی میں کسی خیال میں ڈوبا ہوا پایا، اور اس کی گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ اور اس کا چہرہ دیکھ کر ہی ساری بات سمجھ آ جاتی تھی، کہ کیسے دنیا ارشادی کی جانب مڑ آتی تھی، جیسے اسے ارشادی کی جتنی ضرورت ہو، ارشادی کو اس کی اتنی طلب نہ ہو۔
اس کے چہرے نے مجھ پہ کچھ کر دیا۔ بلکہ اس فلم نے، اپنی دردمندی اور چونکانے دینے والے اختتام سے (جو میں نہیں بتانے والی) مجھ پہ کچھ کر دیا۔ مگر پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرح سے فلم بس اس کا چہرہ ہی تھی۔ اس کا چہرہ اور وہ سنسان پہاڑیاں۔
کچھ عرصہ بعد پھر گرمی ہو گئی، میں جب کھڑکیاں کھولتی تو بلیوں کی باس اندر آتی، مگر ساتھ ہی دھوپ، نمک اور مالٹے کی بھی۔ چوڑی گلیوں کے کنارے کنارے انجیر کے درخت تازہ شادابی دکھانے لگے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ اس احیا سے کچھ حاصل کر لوں، اس کا ایک چھوٹا سا جزو بن جاؤں، مگر سچ یہ ہے کہ میرے بدن میں مرمت کا کام بڑھتا جا رہا تھا۔ جتنا ٹخنے کے زور پر ناچتی وہ اتنا ہی بگڑتا جاتا۔ میں ہفتے میں ایڈول دوائی کی ایک بوتل ختم کر ڈالتی تھی۔ جب طائفے کے دوبارہ دورے پر جانے کا وقت آیا تو میرا جانے کو جی نہیں چاہا، حالانکہ جاپان کا دورہ تھا، جہاں میں ہمیشہ سے جانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ پیچھے رہ جاؤں اور کچھ آرام کروں، دھوپ کی تمازت محسوس کروں۔ میں رومی کیساتھ ساحل پر لیٹ کر سیگرٹ پینا اور لڑکوں کی باتیں چھیڑنا چاہتی تھی، مگر میں نے اپنا سامان باندھا اور دو تین اور رقاصاؤں کے ساتھ ائیرپورٹ جا پہنچی۔
ٹوکیو میں ہم نے تین ناچ کیے، اس کے بعد دو دن کا وقفہ تھا تو ہماری ایک ٹولی نے کیوٹو جانے کی ٹھانی۔ جاپان میں اب تک سردی تھی۔ ٹوکیو سے ٹرین چلی، بھاری ٹائل کی چھتیں برابر سے گزرتی جاتیں، ننھی ننھی کھڑکیوں والے گھر۔ ہمیں ٹھہرنے کیلیے ایک ریوکان سرائے مل گیا، جو چٹائیوں اور چقوں سے مزین تھا۔ دیواروں کی سطح اور رنگت ریتیلی تھی۔ یہاں مجھے سب کچھ بالکل ناقابلِ فہم لگ رہا تھا۔ میں قدم قدم پر غلطیاں کر رہی تھی۔ میں غسل خانے کیلیے مخصوص چپل پہن کر غسل خانے سے باہر، اور کمرے میں پھرتی رہی۔ جب میں نے رات کا پرتکلف کھانا لانے والی عورت سے پوچھا کہ اگر تاتامی چٹائی پر کچھ الٹ جائے تو کیا ہوگا تو اس کی ہنستے ہنستے چیخ نکل پڑی۔ اگر وہ اپنی کرسی سے نیچے گر پاتی تو ضرور گر جاتی مگر کمرے میں کرسیاں تھیں کہاں؟ اس نے اتنا کیا کہ میرے گرم تولیے کا لفافہ لیکر اپنے ’کیمونو‘ کی چوڑی آستین میں ڈال لیا، مگر بڑے سلیقے سے، کہ دیکھنے والا بھول جاتا کہ وہ کچرا اٹھا رہی ہے۔
جاپان میں ہماری آخری صبح تھی، میں جلدی جاگ گئی اور ایک نقشہ تھامے باہر نکل گئی، نقشے پر میں نے ان سب دھرمشالاوں کو نشان زد کیا ہوا تھا جہاں میں جانا چاہتی تھی۔ سب کچھ ٹنڈ منڈ تھا، حتی کے خوبانی کے درخت پر بھی بہار نہیں آئی تھی، سو کیمرا بردار جتھوں کے آن وارد ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی ۔ مجھے دھرمشالاوں اور باغیچوں میں اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی تھی، اور ایسے سناٹے کی بھی جو کووؤں کی کائیں کائیں سے مزید گمبھیر ہو جاتا تھا۔ اسی لیے جب نانزنجی (مخصوص جاپانی عمارت) کے دیو قامت داخلی دروازے سے گزرنے کے بعد راج پروہت کی اقامت گاہ کو جانے والے چھتے ہوئے رستے پر مجھے جاپانی عورتوں کا ایک بڑا گروہ لہکتی ہوئی آوازوں میں خوش گپیاں کرتا دکھائی دیا تو مجھے خاصی حیرت ہوئی۔ وہ سب ریشم کے نفیس کیمونو پہنے ہوئے تھیں۔ ان کے بالوں میں آویزاں کندہ کاری والی مرصع کنگھیوں سے لیکر ان کے کمربندوں اور نقاشی والے ڈوری دار بٹووں تک، ان کے رنگ ڈھنگ کسی گزشتہ زمانے کے تھے۔ بس ایک چیز مستثنیٰ تھی، یعنی ان کے پیروں میں پھیکے بھورے رنگ کی چپلیں، جیسی کیوٹو کی ہر دھرمشالا میں داخلے پر پیش کی جاتی تھیں۔ یہ چپلیں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں، انہیں دیکھ کر مجھے وہ جوتے یاد آ گئے جو پیٹر ریبٹ (Peter Rabbit) نے سلاد کے باڑے میں کھو دیے تھے۔
ایک دن پہلے میں نے خود بھی انہیں پہن کر دیکھا تھا، میں اپنے پیر ان میں ٹھونس کر پیروں کی انگلیاں جکڑ جکڑ کر لکڑی کے چکنے فرشوں پر کھسکنے کی کوشش کرتی رہی مگر ان کو پہن کر سیڑھیاں چڑھنے کے چکر میں قریب قریب گردن تڑوا ہی دینے کے بعد میں نے ان یخ بستہ تختوں پر جرابیں پہن کر چلنا شروع کر دیا۔ اس سے گرم رہ پانا ناممکن ہو گیا، اپنے سویٹر اور کوٹ میں سردی سے ٹھٹھرتی ہوئے میں حیران تھی کہ یہ عورتیں صرف ریشم پہنے ہوئے منجمد کیسے نہیں ہو گئی تھیں؟ کیا انہیں اپنے کیمونو لپیٹنے اور باندھنے اور سنبھالنے میں کسی کی مدد کی ضرورت رہتی ہوگی یا نہیں؟
بے دھیانی میں ہوتے ہوتے میں اس گروہ کے مرکز میں جا پہنچی، تو جب ان عورتوں نے اچانک سے بالجماعت چلنا شروع کر دیا، گویا کہیں سے کوئی خفیہ اشارہ ہوا ہو، تو میں بھی ساتھ ہی اس ریشمی ریلے اور ننھی ننھی چپلوں کی تیز گام چاپ کے ساتھ مدھم روشنی والی چوڑی بغیر چھت والی راہداری میں بہہ چلی۔ تقریباً بیس فٹ چلنے کے بعد وہ گروہ ٹھہر گیا اور اپنی امیبا جیسی شبیہ سے ایک عورت کو اُگلا، جو عام سے روزمرہ کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس نے باقی سب کو مخاطب کر کے بولنا شروع کر دیا۔ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ہی میں ان عورتوں کے سروں کے اوپر سے اس چار سو سال پرانے مراقبے کے باغ کو دیکھ پائی جو جاپان بھر کے مشہور ترین باغات میں سے ایک تھا۔ سمیٹی گئی بجری اور معدودے چند پتھروں، جھاڑیوں اور درختوں کا حامل باغِ مراقبہ داخلے کیلیے نہیں بلکہ باہر سے مشاہدہ کیے جانے کیلیے ہوتا ہے۔ گروہ جہاں رکا تھا اس سے ذرا ہی پیچھے اس مقصد کیلیے بنایا گیا پیش دالان تھا۔ مگر جب میں نے لوگوں کے کندھے تھپک تھپک کر لجاجت سے رستہ مانگ کر آگے جانا چاہا تو میرے اردگرد گھیرا تنگ ہی ہوتا رہا۔ میں جس کسی کا بھی کندھا تھپکتی وہ مجھے پلٹ کر بڑی حیرت کی نظر سے دیکھتی، اور پھر ایک دو قدم دائیں یا بائیں ہو جاتی تاکہ میں گزر پاؤں، مگر فوراً ہی کوئی اور کیمونو پوش عورت بہہ نکلتی اور خلا کو پر کر دیتی۔ ایسا وہ شاید گروہ کا نظم برقرار رکھنے کی کسی داخلی جبلت کے تحت کرتیں، یا وہ اپنی گائیڈ کے قریب ہونا چاہتی تھیں۔ چاروں طرف سے گِھر کر عطر کے چکرا دینے والے بھبھوکوں میں سانس لیتے ہوئے ، اور گائیڈ کی بے تکان اور ناقابل فہم وضاحتوں کو سنتے ہوئے مجھے گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں زور سے کہنی چلا چلا کر باہر نکلتی، ان عورتوں نے اچانک چلنا شروع کر دیا اور میں راج پروہت کی اقامت گاہ کی دیوار سے چپک کر اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، اور ان کو میرے ارد گرد سے گزرنا پڑا۔ گھسٹتی ہوئی چپلوں کی موسیقی میں ان سب نے چوبی فرش پار کر لیا۔
تبھی میں نے اسے چھتے ہوئے رستے پر مخالف سمت میں جاتے دیکھا۔ وہ پہلے کی نسبت عمر میں کچھ بڑا دکھ رہا تھا، اس کی لہریلی زلفیں سفید ہو چلی تھیں، جس کے باعث اس کے سیاہ ابرو کچھ اور بھی متین دکھ رہے تھے۔ کچھ اور بھی الگ تھا۔ فلم میں جسمانی صلابت کا تاثر دینا از حد ضروری تھا، جس خاطر کیاروستامی نے تہران کے باہر پہاڑیوں میں گاڑی چلانے کے دوران کیمرہ اس کے چوڑے کاندھوں اور مضبوط کاٹھی پر مرکوز رکھا تھا۔ مگر جب ارشادی ان بنجر پہاڑیوں پر نظر دوڑانے کیلیے گاڑی سے اترا تھا اور کیمرا ذرا فاصلے پر رکا تھا، تب بھی وہ جسمانی طور پر بڑا وجیہہ دکھ رہا تھا، اور اس وجہ سے اسے ایک تاثیر حاصل ہو گئی تھی، جس نے اس کی آنکھوں میں موجود جذبات کی گہرائی کے ساتھ مل کر مجھے رونے پر مائل کر دیا تھا۔ مگر اس چھتے ہوئے رستے پر جاتے ہوئے ارشادی کچھ چھریرا ہی لگ رہا تھا۔ اس نے وزن گھٹایا تھا، مگر کچھ اور بھی تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے کاندھوں کی چوڑائی سمٹ گئی ہو۔ پیچھے سے دیکھتے ہوئے مجھے شک ہوا کہ شاید یہ ارشادی نہ ہو۔ ابھی کنکریٹ جیسی وزنی مایوسی مجھ میں سرایت کرنے ہی لگی تھی کہ وہ شخص ٹھہرا اور پلٹا، جیسے اسے کسی نے پکارا ہو۔ وہ کافی ساکن کھڑا ہو کر پیچھے کی طرف باغِ مراقبہ کو دیکھ رہا تھا، جہاں پتھر چیتوں کی علامت کے طور پر موجود کسی ایسے مقام کی طرف جھپٹ رہے تھے جہاں وہ کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ایک گداز روشنی اس کے جذبات سے عاری چہرے پر پڑی۔ یہی تھا، کنارہِ نومیدی۔ اس لمحے میں ایک ایسا مغلوب کر دینا والا مدھم جذبہ میرے انگ انگ میں سما گیا جسے محبت کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا۔
ارشادی نے بڑی خوبی سے موڑ مڑا۔ میرے برعکس ان چپلوں میں پھر پانا اس کیلیے چنداں دشوار نہ تھا۔ میں اس کا پیچھا کرنے ہی والی تھی کہ کیمونو پوش خواتین میں سے ایک نے میرا رستہ روک لیا۔ وہ اسی گروہ کی جانب ہاتھ لہرا کر اشارہ کر رہی تھی جو راج پروہت کے مکان کے ایک نیم تاریک کمرے میں جھانک رہا تھا۔ مجھے جاپانی نہیں آتی، مگر وہ میرے سامنے پھدکتی رہی اور بڑھتے ہوئے اصرار سے چپڑ چپڑ کرتی ہوئی اس گروہ کی جانب اشارہ کرتی ہوئی جو اب ایوان سے ہوتے ہوئے داخلی باغیچے کی جانب جا رہا تھا، ان کے قدم یوں غیر محسوس انداز سے گھسٹتے جا رہے تھے جیسے ہزاروں چیونٹیوں نے انہیں اٹھا رکھا ہو۔ میں نے اپنی کلائیوں جوڑ کر کر ایک چھوٹا سا کراس کا نشان بنایا، جیسا میں نے جاپانیوں کو کچھ گڑبڑ ہونے، یا کسی کام کے نا ممکن یا ممنوعہ ہونے کے موقعہ پر کرتے دیکھا تھا۔ میں نے کہا کہ میں باہر جا رہی ہوں، اور خارجی راستے کی طرف اسی اصرار سے اشارہ کیا جس اصرار سے کیمونو پوش عورت گروہ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے مجھے کہنی سے پکڑا اور زور زبردستی مجھے مخالف سمت میں کھینچنے لگی۔ شاید میں نے کسی کلیت کا نازک توازن بگاڑ دیا تھا، ایسا توازن جو کچھ ایسی لطافتوں سے عبارت تھا، جنہیں میں پردیسن ہونے کے باعث کبھی نہ سمجھ پا سکتی۔ یا شاید میں نے اس گروہ کو چھوڑ کر کوئی ناقابل معافی فعل سرزد کر دیا تھا۔ مجھے ایک مرتبہ پھر ایک اتھاہ جہل، جو میرے لیے ہمیشہ اپنے جاپان کے سفر کا مترادف رہے گا، کا احساس ہو رہا تھا۔ معاف کیجیے گا مجھے جانا ہے، یہ کہہ کر میں نے اپنے ارادے سے کچھ زیادہ ہی شدید جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور خارجی راستے کی طرف دھیمی رفتار سے دوڑ دی۔ مگر جب تک میں نے موڑ مڑا، ارشادی کا کچھ اتا پتا نہ تھا۔ پرانے چوبی چوکھٹوں ہر قطاربند پڑے جاپانی خواتین کے جوتوں کے علاوہ انتظار گاہ میں کچھ نہ تھا۔ میں نے باہر کو دوڑ کر ادھر ادھر دیکھا، مگر دھرمشالا کے میدان میں صرف بڑے کوے تھے، جو میرے پاس سے دوڑنے پر الکساہٹ سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔
محبت، میں اسے یہی کہہ سکتی ہوں، گو یہ محبت کے میرے پچھلے تجربات سے کتنا ہی مختلف تھا۔ محبت کے بارے میں جو کچھ میں جانتی تھی اس کا سر چشمہ خواہش تھی، بدلے جانے کی تمنا یا کسی بےقابو قوت سے ٹکرا کر پرانی راہوں سے ہٹنے کی خواہش۔ مگر ارشادی کی محبت کے اس عظیم جذبے کے باہر تو شاید میرا وجود ہی باقی نہیں بچ رہا تھا۔ اسے رحمت کہا جائے تو شاید اس پر قدسی عشق کا شائبہ گزرے، جو کہ وہ نہیں تھا، وہ تو بری طرح سے انسانی محبت تھی۔ بلکہ یہ حیوانی محبت تھی، ایک ایسے حیوان کی محبت جو ایک ناقابلِ فہم جہان میں رہ رہا ہوتا ہے اور ایک دن اپنے جیسے کسی اور کو دیکھ کر جان پاتا ہے کہ وہ اپنی فہم کو بالکل غلط جگہ استعمال کرتا آیا ہے۔
یہ بات سننے میں بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے، مگر اس لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ارشادی کو بچا سکتی ہوں۔ دوڑتے دوڑتے میں دیوقامت چوبی دروازے تلے سے گزری اور میری قدموں کی صدا سے اوپر لگی بلیاں گونج اٹھیں۔ ایک خوف در آیا، یہ خوف کہ کہ اس کا اپنی جان لے لینے کا ارادہ تھا، اس کردار کی طرح جس کی اس نے برائے نام ہی اداکاری کی تھی، اور میں خود کو ودیعت کیا گیا مداخلت کا موقعہ گنوا چکی تھی۔ جب میں گلی تک پہنچی تو وہ سنسان تھی، میں تنگ دریا کے متوازی جاتے ہوئے ہوئے مشہور و معروف رستے کی سمت مڑ کر ایسے دوڑ نکلی کہ میرا بستہ میری رانوں پر بجتا گیا۔ اگر میں اس کو جا پکڑتی تو اسے کیا کہتی؟ میں اس سے خود سپردگی کے متعلق کیا دریافت کرتی؟ جس آن وہ مڑا تھا اور آخرکار اس کی نظر مجھ پر پڑی تھی، میں اس آن کیا بن جانا چاہتی تھی؟ خیر یہ سب لایعنی ثابت ہوا، کیونکہ میں جب میں نے موڑ مڑا تو رستہ خالی تھا اور درخت سیاہ اور بے برگ تھے۔ سرائے پہنچ کر چٹائیوں کے فرش پر کمر دوہری کر کے انٹرنیٹ پر تلاش کرتی رہی ، مگر ہمایوں ارشادی کے متعلق کوئی خبر نہ تھی، کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے معلوم ہوتا کہ وہ جاپان کی سیر پر آیا تھا ،یا زندہ نہ رہا تھا۔
تل ابیب کو واپس جانی والی پرواز پر میرے شبہات میں اضافہ ہوا۔ جب جہاز قوسی بادلوں کے ایک بڑے سے جھنڈ کے اوپر سے تیرتا ہوئے جیسے جیسے جہاز جاپان سے دور ہوتا گیا اس شخص کا ارشادی ہونا اتنا ہی بعید از امکان معلوم ہوتا جا رہا تھا، بالاخر یہ بالکل ہی مہمل لگنے لگا، جیسے کیوٹو میں اٹل عبقریت کے حامل دکھنے والے کیمونو، جاپانی طہارت خانے ، ادب آداب اور چائے کی تقریبات ذرا فاصلے پر بالکل مہمل ہو گئی تھیں۔
تل ابیب لوٹنے کے بعد کی رات کو مجھے ایک شراب خانے میں رومی ملی۔ میں نے اسے جاپان کی کل روداد سنا دی، مگر ہنستے ہنستے۔ خود پر ہنستے ہوئے کہ میں نے ایک لحظے کیلیے بھی باور کر لیا تھا کہ میں نے ارشادی کو ہی دیکھا تھا اور اس کے پیچھے دوڑ پڑی تھی۔ جیسے جیسے میں کہانی سناتی گئی، اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور بڑی ہوتی گئیں۔ رومی نے اپنی ساری اداکارانہ تربیت کو بروئے کار لاتے ہوئے بڑے ڈرامائی انداز میں اپنا ہاتھ سینے پر رکھا اور بیرے کو اپنا گلاس دوبارہ بھرنے کیلیے بلایا۔ اس نے اس کا کاندھا اپنے مخصوص اضطراری ڈھنگ سے چھوا، جس کے بل پر وہ دوسروں کو اپنے جذب کا اسیر کر کر کے اپنی دنیا میں کھینچ لاتی ہے۔ اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑے ہوئے اس نے اپنے بیگ سے ایک سیگریٹ نکال کر جلایا اور ایک کش لیا۔ پھر اس نے نظر ہٹائے بغیر اپنی ٹھوڑی کو ذرا سا خمیدہ کیا اور دھواں چھوڑا۔
بالاخر اس نے ایک پھنسی پھنسی سرگوشی میں کہا ’یقین نہیں آتا، بالکل ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے‘
میں پھر سے ہنسنے لگی، رومی کے ساتھ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ الٹ پھیر ہوتا رہتا تھا، اس کی زندگی اتفاقات اور پراسرار اشاروں کے سلسلے میں بہتی جاتی تھی۔ وہ اداکارہ تو تھی مگر وہ سوانگ نہ بھرتی تھی، یعنی اس کا صدق دل سے یقین تھا کہ کچھ بھی اصلی نہیں ہے، سب کچھ ایک کھیل جیسا ہے، مگر اس بات پر اس کا یقین مخلصانہ، گہرا اور سچا تھا، اور اس کی جینے کی امنگ بے پایاں تھی۔ دوسروں لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو قائل کرنے کیلیے نہیں جیتی تھی۔
اس کے ساتھ جو کچھ الٹ پھیر ہوتا وہ اس لیے ہوتا کہ وہ اس کے لیے تیار رہتی اور اس کی تلاش میں رہا کرتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے نتائج سے بے پرواہ رہ کر کچھ نیا کرنے میں لگی رہتی، اسے دلچسپی ہوتی تو اس کام سے جنم لینے والے جذبات میں، اور ان کا سامنا کر پانے کی اپنی صلاحیت جانچنے میں۔
اپنی فلموں میں وہ ہمیشہ ہی اپنا آپ ہوا کرتی تھی، سکرپٹ کے حالات کے مطابق ادھر ادھر پھیل جانے والا ایک وجود۔
بس بھی کرو، تم مذاق کر رہی ہو، میں نے کہا۔ مگر وہ کبھی بھی مکمل سے کم سنجیدہ نہیں ہوا کرتی تھی، حتی کے ہنستے ہوئے بھی۔ اسی لیے اس نے ٹیبل پر میرا ہاتھ تھامے رکھا، اور ارشادی سے متعلق اپنا قصہ سنانے لگی۔
اس نے ’چیری کا ذائقہ‘ پانچ یا چھ برس قبل لندن میں دیکھی تھی۔ میری طرح اسے بھی فلم نے اور ارشادی کے چہرے نے پوری طرح متاثر کیا تھا۔ بلکہ بے چین۔ باوجود اس کے اخیر میں وہ شادمانی میں ڈوب گئی تھی۔ بالکل، اسے جھٹپٹے کے وقت تھیٹر سے اپنے والد کے گھر جاتے ہوئے شادمانی ہی محسوس ہوئی تھی۔ وہ سرطان کے ہاتھوں مرنے والے تھے اور وہ ان کی دیکھ بھال کرنے آئی تھی۔ جب وہ تین برس کی تھی تو اس کے والدین کی طلاق ہوگئی تھی اور اس کے بچپنے اور نوعمری میں دونوں بہت دور ہو گئے تھی، تقریباً لا تعلق۔ مگر فوجی نوکری کے بعد وہ ایک طرح کی ڈیپریشن سے گزری تھی اور اس کے والد اسے ملنے ہسپتال آئے تھے۔ اور جتنا وہ اس کے سرہانے بیٹھے رہے اتنا ہی وہ انہیں برسوں کی کدورتوں کے لیے معاف کرتی رہی۔ اس کے بعد سے وہ قریب رہنے لگے۔ وہ ان کے ساتھ رہنے کیلیے اکثر لندن جایا کرتی ، اور کچھ عرصے کیلیے تو وہ اداکاری کی تربیت گاہ میں داخلہ کے کر ان کے ساتھ ان کے بیلسائز پارک کے فلیٹ میں بھی رہی۔ کچھ سالوں بعد ان کے سرطان کی تشخیص ہوئی، جس کے نتیجے میں ایک لمبا معرکہ شروع ہوا جو جیتا ہوا لگ رہا تھا، پھر ایک نکتہ ایسا آیا کہ بلا شک و شبہہ واضح ہو گیا کہ درحقیقت جنگ ہاری جا چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے انہیں جینے کے لیے تین مہینے دیے۔
رومی تل ابیب میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس اپنے والد کے اپارٹمنٹ منتقل ہو گئی، اور جن مہینوں میں ان کا بدن کام کرنا چھوڑنے لگا، وہ ان کے ساتھ رہی، اور شاذ ہی انہیں تنہا چھوڑا۔ انہیں نے زندگی کے محض چند ہفتے یا مہینے بڑھا دینے والا زہرناک علاج معالجہ نہ کرانے کا فیصلہ کیا۔ وہ وقار اور سکون کی موت مرنا چاہتے تھے۔ اب سکون سے کون مرتا ہے؟ بدن کے فنا ہونے کا سفر ہمیشہ تشدد کا متقاضی ہوتا ہے۔ تشدد کی یہ چھوٹی بڑی انواع ان کے لیے روز کی بات بن گئیں، مگر ان میں اس کے والد کی ظرافت ہمیشہ شامل حال رہتی۔ جب تک وہ چل پھر سکتے تھے وہ دونوں اٹھے چہل قدمی کرتے رہے، جب وہ اس سے قاصر ہو گئے تو وہ مل کر گھنٹوں گھنٹوں جاسوسی سیریزیں، اور قدرت کے متعلق ڈاکومنٹریاں دیکھتے۔ ٹی وی کی روشنی میں اپنے والد کے ساکت تاثر کو دیکھتے ہوئے رومی کو خیال آیا کہ اب جب کہ ان کی اپنی کہانی اختتام کی جانب بڑھ رہی تھی، وہ ان کہانیوں، اندھے قتلوں اور جاسوسوں کے قصوں، اور کسی گوبریلے کے گوبر کی گولے کو ایک ڈھلان پر سے دھکیلنے کی جدوجہد میں کچھ کم منہمک نہیں تھے۔ گرچہ وہ رات کے وقت بستر سے نکل کر غسل خانے نہیں جا پاتے تھے، وہ پھر بھی کوشش کرتے اور پھر رومی ان کے فرش پر گرنے کی آواز سن کر جاتی، ان کا سر اپنی آغوش میں لیتی اور انہیں اٹھا لیتی، کیونکہ تب تک وہ کسی بچے سے زیادہ وزنی نہ رہے تھے۔
یہی وقت تھا، یعنی وہ وقت جب اس کے والد غسل خانے تک بھی نہیں جا پاتے تھے اور چوبیس گھنٹے موجود رہنے والی نرس کو انہیں اپنے چوڑے چکلے یوکرینی شانے پر اٹھائے پھرنا پڑتا تھا، جب نرس کے اصرار پر رومی نے اپنا کوٹ پہنا اور کچھ گھنٹوں کے لیے ایک فلم دیکھنے گھر سے باہر نکلی۔ اسے فلم کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، مگر وہ فلم کا نام، جو اسے نے ہسپتال سے آتے ہوئے یا وہاں جاتے ہوئے تھیٹر کے تشہیری تختے پر دیکھا تھا۔
وہ قریب قریب اجاڑ تھیٹر کی پشت پر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ رومی نے بتایا کہ وہاں پانچ چھ ہی لوگ تھے مگر کسی بھرے ہوئے تھیٹر کے برعکس، جہاں پردے کے روشن ہوتے ہی اردگرد کے لوگ غائب ہو جاتے ہیں، اسے دوسرے لوگوں کی موجودگی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، ان میں سے زیادہ تر اکیلے ہی آئے تھے۔ فلم کے کئی بے حرف دورانیوں میں، ایسے دورانیے جن میں کوئی گاڑیوں کے ہارن اور بلڈوزروں کی آوازیں اور ان دیکھے بچوں کی ہنسی سن سکتا ہے، اور ان طویل مناظر میں جن میں کیمرا ارشادی کے چہرے پر ٹھہرتا ہے، رومی کو اپنے دیکھنے کا احساس ہوا، اور دوسروں کے دیکھنے کا بھی۔ جب اس سمجھ آیا کہ آقائے بدیع اپنی جان لینے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ کسی ایسے کی تلاش میں ہے جو اسے علی الصبح دفنا دے، وہ رونے لگی۔ اس سے کچھ دیر بعد ایک عورت اٹھ کھڑی ہوئے اور تھیٹر سے باہر نکل گئی۔ یہ رومی کو ذرا اچھا لگا، کیونکہ اس سے باقی رہ جانے والوں کے درمیاں ایک بے نام رشتہ بن گیا۔
میں نے کہا تھا کہ میں فلم کا اختتام فاش نہیں کروں گی، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی چارہ ہی نہیں بچا، اور مجھے بتانا ہی پڑے گا کیونکہ رومی کا ماننا تھا کہ اگر فلم روایتی انداز سے انجام کو پہنچتی تو بعد میں ہم دونوں کے ساتھ جو ہوا وہ شاید بالکل ہی نہ ہو پاتا۔ یعنی بظاہر گولیاں نگل کر سردی سے بچنے کیلیے ایک ہلکی جیکٹ پہننے کے بعد آقائے بدیع اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں لیٹ جاتا، اور ہم اس کے جذبات سے عاری چہرے کو بادلوں سے ابھرتے ڈوبتے چاند کو تکتا ہوئے دیکھتے، اس منظر کے بعد سب کچھ تاریک ہو جاتا ، اور اس وقت جب تاریکی اتنی بڑھ جاتی کہ ہم اسے مزید نہ دیکھ پاتے، بجلی گرجتی اور بجلی کی چمک سے پردہ پھر روشن ہوجاتا، اور وہ وہیں ہوتا، وہیں لیٹا ہوا، اسی دنیا میں، منتظر، اور ہم بھی منتظر ہوتے مگر تاریکی پھر چھا جاتی، پھر ایک اور کوندا لپکتا، جس میں ہم بالاخر اس کی آنکھوں کو بند ہوتا دیکھتے، اور پھر پردہ آخری بار تاریک ہوجاتا، اور صرف بارش کے بڑھتی ہوئی تیزی کے ساتھ برسنے کی آواز باقی رہ جاتی اور وہ بھی بالاخر اپنی انتہا پر پہنچنے کے بعد مدھم ہوتی ہوتی ختم ہو جاتی۔ اگر فلم یہیں ختم ہو جاتی، جس کا پورا پورا امکان تھا، تو رومی کا کہنا تھا کہ شاید یہ فلم اسے یاد نہ رہتی۔
مگر فلم وہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ تیز قدمی کرتے ہوئے فوجیوں کے تال دار صدائیں سنائی دینے لگتی ہیں، اور آہستہ آہستہ پردہ پھر سے جی اٹھتا ہے۔ اس مرتبہ جب کوہساروں کا منظر سامنے آتا ہے تو بہار کا موسم ہوتا ہے، ہر طرف ہریالی ہوتی ہے ، اور بدرنگ اور دانیدار عکاسی براہ راست ویڈیو پر ہی کی گئی ہے۔ پردے کی نچلی سمت میں بائیں ہاتھ پر فوجی بل کھاتی ہوئی سڑک پر صف بند ہو کر تیز قدمی کر رہے ہیں۔ یہ نیا منظر پہلے ہی کافی حیران کن ہے، مگر ذرا دیر میں فلم کے عملے کا ایک رکن وارد ہوتا ہے، وہ ایک اور شخص کی طرف کیمرہ ڈھو رہا ہوتا جو کیمرے کا سہ پایہ سہارا نصب کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر خود ارشادی، وہی ارشادی جو ابھی اپنی قبر میں سو گیا تھا، آرام سے چلتا ہوا فریم میں آتا ہے۔ اس نے ہلکے پھلکے، عام سے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ وہ اپنی سامنے کی جیب سے ایک سیگریٹ نکالتا ہے، ہونٹوں کے درمیان رکھ کے اسے سلگاتا ہے اور بنا کچھ بولے اسے کیاروستامی کو تھما دیتا ہے، جو اپنے ناظمِ تصویر کشی سے بات میں وقفہ لائے بغیر، اور ارشادی کی طرف دیکھے بنا سیگریٹ لے لیتا ہے۔ اس موقعے پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ارشادی اس سے کامل وجدان کی راہ سے جڑا ہوا ہے۔ اب کیمرہ معاونِ صدا بندی کی طرف جاتا ہے، جو ذرا نیچے پہاڑی پر اونچی جھاڑیوں میں اپنا بڑا سا مائکروفون لیے ہوا سے بچنے کے لیے اکڑوں بیٹھا ہے۔
”کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟“ ایک بے پیکر آواز پوچھتی ہے
نیچے مشق کرانے والا کارندہ رکتا ہے اور چلانا بند کر دیتا ہے۔
وہ کہتا ہے ” ہاں “
اپنے آدمیوں کو کہو کہ درخت کے پاس ٹھہر کر آرام کر لیں، فلم کی شوٹنگ ختم ہو گئی ہے۔
کچھ لمحوں بعد جب لوئی آرمسٹرانگ کا سوگوار باجہ بین کرنا شروع کر دیتا یے فلم کا آخری مکالمہ ادا کیا جاتا ہے، اور سپاہیوں کو ہنستے بولتے ہوئے اس درخت کے پاس سے پھول چنتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جہاں آقائے بدیع ابدی آرام کی امید میں جا لیٹا تھا، گرچہ اب وہ درخت سبز پتوں سے ڈھکا ہوا ہے۔
کیاروستامی کہتا ہے ہمیں یہاں صدابندی کرنی ہے۔
اور پھر ایک بلند آہنگ، جمیل اور درد بھرا باجہ بجنے لگتا ہے۔ رومی بیٹھ کر سنتی رہی اور فلم کے عملے کے نام بھی پڑھتی رہی، اور اگرچہ اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے ، وہ بہت خوش تھی۔
اپنے والد کو سپرد خاک کر دینے اور ان کی قبر میں بیلچے سے مٹی ڈالنے کے دوران بیلچا چھیننے کی کوشش کرنے والے اپنے چچا کو دھکیلنے کے کچھ عرصہ بعد جا کر رومی کو ارشادی دوبارہ یاد آیا۔
بیحد خوشی کے عالم میں جھٹپٹے کے وقت گھر واپس جانے کے بعد سے وہ اتنے شدید حالات سے گزری تھی کہ اسے فلم کے بارے میں دوبارہ سوچنے کا موقعہ ہی نہیں ملا تھا۔ وہ اپنے والد کے ترکے کی دیکھ بھال کے لیے لندن میں ہی رک گئی، اور جب نگہداشت کرنے لائق کچھ نہ بچا، جب سب معاملات طے ہو گئے، تو وہ اس ویران فلیٹ میں مہینوں تک ٹھہری رہی ۔
یکسانیت سے گزرنے والے دنوں میں وہ بے سدھ لیٹی رہتی، اس کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ جفتی کے دوران ہی اسے کوئی امنگ محسوس ہو پاتی تھی اسی لیے اس نے مارک کو پھر سے ملنا شروع کر دیا۔ اداکاری کی تربیت گاہ میں گزرے سال میں وہ اسے ملا کرتی تھی۔ وہ شکی مزاج تھا، پچھلی بار ان کا تعلق اسی لیے ختم ہوا تھا۔ اور اب جب کہ اس سے الگ ہونے کے بعد وہ کئی مردوں کے ساتھ رہی تھی، وہ اور بھی حاسد اور وہمی ہو گیا تھا، اور ہر وقت اس سے دوسرے مردوں کے ساتھ بتائے گئے وقت کے بارے میں بتانے کیلیے تنگ کرتا رہتا تھا۔ مگر ان کا ملاپ ہمیشہ زوردار اور عمدہ ہوا کرتا تھا۔
رات کو جب مارک کام سے گھر آتا ، رومی اس کے گھر چلی جاتی اور اس کے تاریک کمرے میں وہ فحش فلمیں کھنگالتے جب تک انہیں اپنے مطلب کی چیز نہ مل جاتی۔ اس کے بعد وہ رومی کو پیٹ کے بل لیٹتے ہوئے ملاپ کرتا، اور وہ ٹی وی کی چوڑی سکرین پر دو یا تین مردوں کو کسی عورت میں دخول کرتے دیکھتے۔ وہ اپنے عضو اس کے مختلف سوراخوں میں گھسیڑتے ، ٹی وی اُن کی سانسوں اور آہوں کو گونج دے دیتا۔ انزال کے وقت مارک رومی کا کولہا زور سے تھپکتا اور اس میں مضبوطی سے جفتی کرتے ہوئے اسے چھنال کہہ کر بلاتا، یہ کسی قدیم درد کا اظہار تھا جس کی وجہ سے وہ یہ سوچتا تھا کہ جس عورت سے وہ پیار کرے گا وہ کبھی اس سے وفا نہیں کرے گی۔ ایک رات اس ساری کاروائی کے بعد مارک اس کے گرد بانہیں ڈال کر سو چکا تھا اور رومی جاگی رہی تھی، وہ ہمیشہ کی طرح خستہ تھی اور سو نہیں پائی تھی۔ بالآخر وہ مارک کے نیچے سے کھسکتی ہوئے نکلی اور فرش پر رینگتے ہوئے اپنا زیر جامہ ڈھونڈنے لگی۔ نہ اسے وہاں ٹھہرنے کی آرزو تھی اور نہ وہاں سے چل نکلنے کی، سو وہ دوبارہ مارک کے پلنگ کے کنارے پر جا دھنسی۔ اسے لگا کہ ٹی وی کا ریموٹ اس کے نیچے پڑا ہے۔ اس نے ٹی وی چالو کیا اور چینل بدلنے لگی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ دیکھی گئی ہتھنیوں اور شہد کی مکھیوں کی بستیوں کی کہانیوں، وارداتوں جنہیں داخل دفتر کر دیا گیا تھا اور آخر شب کے ٹاک شوز سے گزرتی جا رہی تھی جب وہ عین سامنے آیا، فراخ سکرین کو تقریباً پوری طرح گھیرے ہوئے، ارشادی کا چہرہ۔ ایک لحظے کیلیے وہ اس تاریک کمرے میں بہت غیر معمولی دکھائی دیا اور پھر کھو گیا، کیوں کہ اس سے پہلے کہ رومی کو اندازہ ہوتا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے رومی کے انگوٹھے نے اپنی بے چین تلاش دوبارہ جاری کر دی۔ جب اس نے چینل دوبارہ لگایا تو وہ اسے ڈھونڈ نہ سکی۔ فلم یا ایران یا کیاروستامی کے متعلق کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ وہیں اندھیرے میں حیران و پریشان بیٹھی رہی، اور پھر آہستہ آہستہ ایک تمنا نے کسی لہر کی طرح اسے آ لیا، اور وہ اپنے والد کی موت کے بعد پہلی بار ہنس پڑی، اور اس نے جان لیا کہ گھر لوٹنے کا وقت ہو گیا تھا۔
رومی کا یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کی کہانی اتنی مفصل تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس نے اسے گھڑا ہو۔ کبھی کبھی وہ تفصیلات میں مبالغہ آرائی کر دیتی تھی مگر اسے ان مبالغوں ہر یقین ہوتا تھا اور اس سے اس پر مزید لاڈ ہی آتا تھا، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس دنیا کے خام مال کے ساتھ کیا کیا کر سکتی ہے۔ پھر بھی جب میں گھر گئی اور اس کی موجودگی کا سحر اترا، میں اپنے بستر پر شدید غم آور خلش کے عالم میں مسلسل بڑھتی ہوئی اندوہناکی کے ساتھ لیٹ گئی، کیونکہ نہ صرف یہ کہ ارشادی کے ساتھ میرا ٹاکرا منفرد نہیں تھا، بلکہ رومی کے برخلاف مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آخر اس کا مطلب کیا تھا، یا وہ میرے کس کام کا تھا۔ میں کچھ سمجھنے یا اس واقعہ سے کچھ اخذ کرنے سے قاصر تھی، میں نے تو اپنی کہانی بھی کسی چٹکلے کی طرح خود پر ہنستے ہنستے سنائی تھی۔ اندھیرے میں لیٹے لیٹے میں رونے لگی۔ اپنے گھٹنے میں ٹیسیں مارتے درد سے تنگ آ کر میں نے غسل خانے جا کر مٹھی بھر اڈول کی گولیاں نگل لیں۔ میرے معدے میں گولیاں ملاقات کے دوران پی گئی شراب کے ساتھ چکر کھاتی رہیں، اور ذرا ہی دیر میں مجھے متلی آ گئی، اور میں غسل خانے کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی کموڈ میں الٹی کرتی رہی۔
اگلی صبح میں دروازہ بجنے کی آواز سے جاگی، رومی کو محسوس ہو گیا تھا کہ کچھ گڑ بڑ ہے، اور اس نے فون ملانے کی کوشش کی تھی مگر میں نے ساری رات فون نہ اٹھایا۔ میں ابھی بھی کچھ کچھ ٹن تھی، میں نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ مستعد ہو گئی، اس نے چائے ابالی، مجھے صوفے پر بٹھایا اور میرا منہ صاف کیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور دوسری ہتھیلی اپنے گلے پر رکھ دی ، گویا میرا درد اس کا درد ہو اور وہ سب کچھ محسوس کر چکی تھی تھی اور سب کچھ جانتی تھی۔
دو مہینے بعد میں نے طائفہ چھوڑ دیا۔ میں نے اعلی تر تعلیم کیلیے نیو یارک یونیورسٹی میں داخلہ لیا، مگر گرمیوں میں میں تل ابیب میں ہی ٹھہری رہی، اور سمسٹر شروع ہونے سے کچھ ہی دن پہلے نیو یارک واپس گئی۔ تب تک رومی عامر کو مل چکی تھی، وہ ایک کاروباری مہم جو تھا جو اس سے پندرہ برس بڑا تھا، اور اس کے پاس اتنا وافر پیسہ تھا کہ اس کا زیادہ تر وقت اس پیسے سے جان چھڑانے کے طریقے ڈھونڈنے میں گزرتا تھا۔ اس نے رومی کی خواستگاری اسی اچھوتی لگن سے کی جس سے وہ ہر من چاہی چیز کا پیچھا کرتا تھا۔ میری پرواز سے کچھ دن پہلے رومی نے میرے پسندیدہ ریستوران میں میرے لیے الوداعی پارٹی رکھی، سبھی رقاصائیں آئیں، ہماری سہیلیاں بھی آئیں اور اس سال ہم جن جن لڑکوں کے ساتھ سوئی تھیں ان میں سے بھی اکثر آئے۔ عامرنہیں آیا کیونکہ وہ مصروف تھا۔ اگلے دن اس کی بادبانی کشتی میں سارڈینیا کو عازم ہوئی۔ میں نے اپنا سامان اکیلے سمیٹا۔ جاتے ہوئے میں اداس تھی اور سوچ رہی تھی کہ کہیں میں نے غلط فیصلہ تو نہیں کیا؟
کچھ عرصہ ہم لوگ قریبی رابطے میں رہے۔ رومی نے شادی کر لی اور بحیرہِ روم سے کچھ اونچائی پر ایک پہاڑی پر واقع عامر کے محل میں منتقل ہوئی، اور پیٹ سے ہو گئی۔ میں نے اپنی سند کے کیلیے پڑھائی لکھائی کی، عشق کیا اور دو برس بعد ترک عشق کیا۔ اس دوران رومی کے دو بچے ہوئے، اور کبھی کبھار وہ مجھے ان لڑکوں کی تصویریں بھیجتی جن کے چہرے ہوبہو اس جیسے تھے اور بظاہر اپنے باپ سے ذرا بھی مشابہت نہ رکھتے تھے۔ مگر ہمارا رابطہ کم سے کم ہوتا گیا، اور پھر کئی ایسے سال گزر جاتے جن میں ہم ایک دوسرے سے بات نہ کرتے۔ میری بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد ایک دن میں ٹویلفتھ سٹریٹ پر ایک سنیما گھر کے پاس سے گزر رہی تھی کہ مجھے کسی کی نگاہ کا احساس ہوا، اور جب میں مڑی تو ارشادی کی آنکھیں ‘ چیری کا ذائقہ’ کے ایک پوسٹر سے مجھے گھور رہی تھیں۔ میری ریڑھ میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ فلم کی نمائش ختم ہو چکی تھی مگر کسی نے پوسٹر نہیں اتارا تھا۔ میں نے اس کی تصویر کھینچی اور رات کو اسے رومی کو بھیج دیا، اور اسے گئے دنوں میں بنائے گئے اپنے تہران جانے کے منصوبے کی یاد دلائی ، میرے پاس اسرائیل کے ٹھپوں سے پاک اپنا نیا امریکی پاسپورٹ ہوتا ، اور اس کے پاس اس کا برطانوی پاسپورٹ جو اس نے اپنے والد کے ذریعے حاصل کیا تھا۔ ہم قہوہ خانوں میں بیٹھتیں اور ان گلیوں میں گھومتی جہاں ہماری کئی پسندیدہ فلموں کی منظر کشی کی گئی تھی، ہم وہاں کی زندگی کا مزا چکھتیں اور کوہ گیلان کے ساحل پر لیٹتیں۔ ہمارا ارادہ ارشادی کو ڈھونڈنے کا تھا، جو ہمارے خیال سے ہمیں اپنے دلآویز فلیٹ میں مدعو کرتا، جس کا نقشہ اس نے خود ترتیب دیا ہوتا۔ وہ ہماری کہانیاں سنتا اور برف پوش کوہ البرز کے نظاروں میں ہم سب کے کالی چائے کے دور میں وہ ہمیں اپنی کہانی سناتا۔ اپنے خط میں میں نے اس رات اپنے رونے کی وجہ کا اعتراف کیا جب اس نے مجھے ارشادی کے ساتھ اپنے تجربے کے بارے میں مجھے بتایا تھا۔
میں نے لکھا کہ جلد یا بدیر مجھے ماننا تو پڑتا ہی کہ اپنی امنگ کے جوش میں خود کو روکنے میں ناکام رہی تھی۔ مجھے اس بات کا سامنا تو بہرحال کرنا ہی پڑتا کہ میں کتنے برے حال میں تھی اور رقص کے بارے میں میرے جذبات کیسے الجھ چکے تھے۔ مگر اس خواہش نے کہ میں ارشادی سے کچھ حاصل کروں اور یہ محسوس کروں میرے لیے بھی حقیقت ویسے ہی وسیع ہو چکی تھی جیسے رومی کیلیے ہوئی تھی اور دوسرا جہاں مجھے چھونے کو آ ہی گیا تھا، میری غلط فہمی اور بھی تیزی سے دور کر دی تھی۔
رومی کا جواب ہفتوں تک نہیں آیا، اور پھر آخر کار آ ہی گیا۔ اس نے اس قدر تاخیر کیلیے معذرت کی۔ اس نے کہا کہ حیرت کی بات تھی کہ اس نے سالوں تک ارشادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا جب تین ماہ قبل اس نے ‘چیری کا ذائقہ’ دوبارہ دیکھنے کی ٹھانی، اس نے حال ہی میں عامر سے علیحدگی اختیار کی تھی اور جن راتوں میں وہ اپنے نئے فلیٹ کی نامانوس مہکوں اور گلی سے آتے شور کی وجہ سے سو نہ پاتی، وہ دیر تک جاگ کر فلمیں دیکھتی۔ اسے اس بات نے حیران کیا کہ اب کے ارشادی کا کردار اسے کس قدر مختلف لگ رہا تھا۔ اس کو ارشادی پر سکون، تقریباً برگزیدہ یاد تھا، مگر اب اس نے دیکھا کہ وہ جن آدمیوں سے بات کرتا تھا ان کے ساتھ بے صبری اور بدمزاجی سے پیش آتا، اور اپنی بات منوانے کیلیے خاصی چالاکی سے ان کی کمزوریوں کا اندازہ لگاتا اور ان کو قائل کرنے کیلیے کچھ بھی کہہ دیتا۔ اسے بس اپنے غم کی پرواہ تھی اور اپنا منصوبہ پورا کرنے کی اس کی اٹل ضد سے ایک طرح کی خود غرضی جھلکتی تھی۔ اسے ایک اور چیز نے بھی حیران کر دیا، کیونکہ یہ اسے یاد نہیں تھی، یعنی فلم شروع ہونے سے پہلے سیاہ پردے پر ابھرنے والے ان لفظوں نے ’ In the name of God ‘۔ وہ حیران تھی کہ اس نے پہلے ان پر غور کیوں نہیں کیا۔ اندھیرے میں بیٹھ کر فلم دیکھتے ہوئے اسے میرا ہی خیال آیا تھا، اس سال کا خیال جب ہم ابھی تک نوجوان تھیں۔ اس نے لکھا کہ ہم نے کتنا ہی وقت یہ سوچنے میں ضائع کر دیا کہ نہیں چیزیں آپ ہی آپ مل جاتی ہیں، عجائب کے رستوں سے، مردوں کی چاہ میں، خدا کے نام پر۔ بجائے ان کی حقیقت دیکھنے کے،یعنی اصل میں یہ وہ توانائیاں تھیں جو ہم نے اپنے باطن کی گہرائیوں میں موجود خلا سے برآمد کی تھیں۔ اس نے مجھے اس فلم کے متعلق بتایا جو وہ فرصت ملنے پر لکھنا چاہتی تھی، جو مجھ جیسی ایک رقاصہ کی کہانی پر مبنی ہوتی۔ اس نے مجھے اپنے بیٹوں کے بارے میں بتایا جو ذرا ذرا سے کاموں کے لیے اس پر منحصر تھے، جیسے اس کی زندگی میں آنے والے سب مردوں کو ہر چیز کیلیے اس کی ضرورت رہا کرتی تھی۔ اس نے لکھا کہ یہ بڑی اچھی بات تھی کہ میری بیٹی تھی۔ اور پھر جیسے وہ بھول گئی ہو کہ اب وہ اور بکھیڑوں میں مشغول تھی، اور ہم دونوں اب بھی آمنے سامنے بیٹھی اپنی کسی آغاز اختتام یا وسط کے بغیر کی باتوں میں ڈوبی ہوں، اس نے لکھا کہ آخری بات جس پر اسے حیرت ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جب ارشادی اپنی کھودی ہوئی قبر میں لیٹ جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بالاخر مند جاتی ہیں اور پردہ سیاہ ہو جاتا ہے، تو مکمل تاریکی نہیں چھا جاتی۔ اگر غور سے دیکھو، تو بارش کو برستے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔
ماخذ: The New Yorker