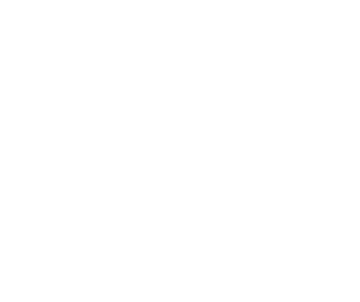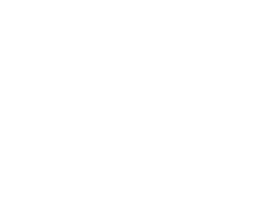دھنی بخش کے بیٹے: حسن منظر (تبصرہ: بلال حسن بھٹی)
اردو افسانہ جس وقت تجریدیت اور علامت کے دور سے گزر رہا تھا، افسانے کی ہیئت اور اسلوب میں طرح طرح کے تجربات کیے جا رہے تھے۔ اس وقت 1981 میں سید حسن منظر کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ”رہائی“ کے نام سے شائع ہوا جس میں موجود تمام افسانے نئے تھے۔ اگلے سال 1982 میں ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ ”ندیدی“ کے عنوان سے شائع ہوا۔ حسن منظر نے لکھنے کا آغاز زمانہ طالب علمی سے کیا تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاس میں افسانے پیش کیے اور ان کا افسانہ ” لاسہ“ سننے کے بعد سعادت حسن منٹو نے بھی داد دی۔ اس کے بعد وہ اپنی تعلیم کی طرف متوجہ ہو گئے اور لکھنے کا یہ سلسلہ رُک گیا۔ ایک لمبے وقفے کے بعد لگ بھگ پچاس سال کی عمر میں ان کا نیا افسانوی مجموعہ شائع ہوا۔ اپنی ابتدائی دونوں کتابیں چونکہ انہوں نے خود شائع کی تھیں اس لیے یہ زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکیں۔ چونکہ حسن منظر صاحب ملک واپسی کے باوجود ادبی گروہوں اور اسلام آباد، لاہور یا کراچی جیسے ادبی مراکز سے دور رہے اس لیے بھی ان کا چرچہ اس طرح سننے کو نہیں ملا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ تاہم انہوں نے اپنے متنوع موضوعات، بدلتے منظر ناموں، دھیمے مزاج اور سادہ اسلوب کی بنا پر اردو افسانے میں اپنا نام پیدا کیا۔ بیسویں صدی میں جہاں افسانہ اپنے عروج پر تھا وہیں اکیسویں صدی میں ناول نے لکھنے والوں کو اپنی طرف زیادہ متوجہ کیا۔ 2006 میں حسن منظر صاحب کا پہلا ناول ”العاصفہ“ شائع ہواجو تیل کی دریافت سے قبل کے عرب معاشرے، وہاں کے رہن سہن، رسم و رواج، عادات اور غربت کی بہت عمدہ منظر کشی کرتا ہے۔ علامت نگاری، دیہی اور شہری زندگی کے درمیان پایا جانے والا تفاوت اور تیل کی دریافت سے پہلے کے عرب معاشرے کی جھلک نے العاصفہ کو اردو ناول میں ایک اہم اضافہ بنایا۔ العاصفہ کے دو سال بعد 2008 میں ”دھنی بخش کے بیٹے“ شائع ہوا۔ یہ ناول اپنے وسیع کینوس، موضوعاتی تنوع، جدید وقت کے مسائل سے آگاہی دیتا، پستے طبقوں کی آواز بنتا اور بڑھتی تہذیبی کشمکش کو عیاں کرتا مصنف کا نمائندہ ناول ہے۔
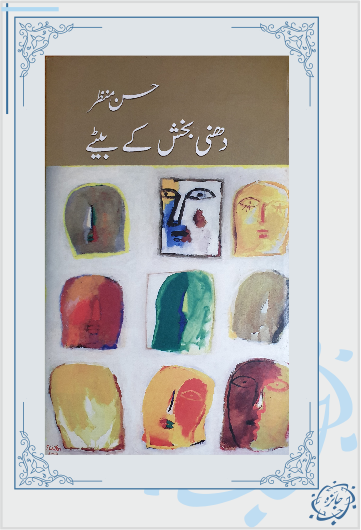
جاگیرداری نظام اور طبقاتی کشمکش جیسے موضوعات پر اردو ادب میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ 1980 کی دہائی اور اس کے بعد یورپ اور امریکہ کی طرف ہونے والی ہجرت، اس کے نتائج میں پیدا ہونے والے مسائل اور مغرب میں بوڑھے ہوتے مشرقی والدین کے سامنے بہت سے سوالات کھڑے ہوئے۔ مثلاً اس معاشرے میں پروان چڑھ کر ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہو گا؟ ان کا مذہب کیا ہو گا؟ اگر وہ اس کھلے ڈلے ماحول میں پروان چڑھیں گے تو اپنے جنسی ہیجان پر کیسے قابو پائیں گے؟ کیا وہ بھی اسی گن کلچر کا شکار ہو جائیں گے جو وہ اپنے دائیں بائیں دیکھں گے؟ موت کے بعد ان کو جلایا جائے گا یا دفنایا جائے گا؟ ہجرتوں کے بعد پیدا ہونے والے ان سوالات کا جواب ڈھونڈتے والدین اور خاص کر نائن الیون کے بعد پیدا ہونیوالی صورتحال نے اس تہذیبی کشمکش کو مزید گہرا کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستانی ادیبوں نے بھی ان موضوعات کو اپنے فکشن میں برتنا شروع کیا۔ پاکستان میں اس موضوع پر زیادہ تر لکھنے والے برطانوی نژاد پاکستانی یا امریکی نژاد پاکستانی انگلش لکھاری ہیں جن میں محسن حامد، ندیم اسلم، علی اعتراض، کاملہ شمسی اور ایچ ایم نقوی وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ اس حوالے سے محسن حامد کا نام نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ ان کے ناول The reluctant fundamentalist کو بین الاقوامی طور پر بہت پزیرائی ملی۔ جس کا موضوع امریکہ میں نائن الیون کے بعد مسلمانوں سے ہونے والا سلوک ہے۔ ندیم اسلم نے اس سے بھی پہلے 2004 میں اپنا ناول Maps for lost loversشائع کیا جواپنے پلاٹ، موضوعات اور اسلوب کی بنا پر مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس میں پاکستان سے انگلینڈ ہجرت کے بعد بدلتے حالات، نئی تہذیب میں پروان چڑھتے بچے، تنہائی، لوگوں کی ایک دوسرے سے بڑھتی لاتعلقی، مذہب سے دوری اور مشرق و مغرب کے تہذیبی ملاپ سے پیدا ہوتی صورتحال میں بڑھتی ہوئی گھٹن کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ”دھنی بخش کے بیٹے“ تہذیب کی اس کشمکش سے پیدا ہونے والی صورتحال اور مسائل پر اردو میں اس موضوع کو خاص طور پر زیر بحث لانے والا غالبا پہلا ناول ہے۔
حالات کو بدلنے کی آرزو، ناقابل برداشت حالات سے فرار، شکست سے پہلے کی کشمکش اور آخر کار بے بسی پر مبنی شکست وہ حصے ہیں جن میں ” دھنی بخش کے بیٹے“ کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ”آرزو“ اس ظلم کو ختم کرنے کی جو ہمارے آس پاس ہو رہا ہے۔ ”آرزو“ ان لوگوں کی مدد کرنے کی جو ہمارے دائیں بائیں بدحال اور شکستہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی زندگی جس کو برداشت کرنا کسی بھی شخص کو مشکل ہی نہیں نا ممکن لگے۔ جہاں آخری سانسیں لیتے ہوئے مریض کی چارپائی لے کر سڑک پار کرنے کی اجازت محض اس لیے نہ ملے کہ اس وقت کسی حکمران کا قافلہ اس سڑک سے گزرنا ہے۔ جہاں ایک عورت کی خوبصورتی اس کی سب سے بڑی غلطی ہو۔ جہاں شادی کے لیے عمر، ذہنی مطابقت اورعقل نہیں بلکہ خاندانی عظمت اور حسن کو ترجیح ملے۔ ایسے سماج میں رہتے ہوئے جب انسان کو شعور آنا شروع ہوتا ہے تو وہ عجیب ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس ذہنی کشمکش میں پہلی کوشش ”احتجاج“ یا ”فرار“ کی ہوتی ہے۔ نظر آنے والے ہر ظلم، زیادتی اور نا انصافی کے خلاف احتجاج یا فرار لیکن جب معاشرتی نا انصافی، ظلم اور بے بسی اپنی انتہا پر پہنچ کر بے حسی بن جائے؛ ظلم، ظالم اور مظلوم کا فرق مٹ جائے تو ظلم کو ظلم نہ سمجھ کر برداشت کرنے والا انسان، ظالم اور اس ظالم کی مدد کرنے والے تینوں ایک ہو جاتے ہیں۔ لوگ ظلم برداشت کرتے ہیں، لوگ ظلم کا ساتھ دیتے ہیں اور ظالم ظلم کو ظلم نہیں سمجھتا۔ یہ تینوں کردار جب ایک ہو جائیں تو ایک حساس دل اور شعور رکھنے والے دماغ کی ”شکست“ یقینی ہو جاتی ہے۔ جو وقتی طور پر فرار اختیار کر کے بھی ظلم کی نہ ختم ہونے والی اس تاریک دنیا کے وسوسوں اور خوف سے خود کو دورنہیں کر پاتا۔
یہ بے حسی، ظالمانہ نظام اور مظلوموں کا صبر ہی اس ناول کے ایک اہم کردار احمد بخش کو ملک چھوڑنے پر اکساتا ہے۔ اس جاگیرداری نظام میں کام کرنے والے انسانوں کو بھی وراثت کی طرح اولاد میں بانٹا جاتا ہے۔ ان کی قسمت کے تمام فیصلے بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کی قسمت کے فیصلے بھی جاگیردار کرتا ہے جو جدی نوکروں کی نسلوں تک کو قبول کرنے ہوتے ہیں۔ ”اللہ بہتر جانتا ہے کہ نوکر کسی خاندان کے حصے میں ہمیشہ کے لیے کیسے آتے ہیں اور غلام نہ ہوتے ہوئے بھی جائیداد کی طرح بٹ جاتے ہیں۔ اور بھاگ بھی نہیں جاتے کہ حضر الموت یا حبشہ جا نکلیں“۔ جہاں عورت اہم بھی ہے لیکن اس کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ وہ یا تو کام کرنے والی مشین ہے اور اگر وہ گھر کی بڑی بہو ہے تو اس کی ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ ”مشرق میں گھر میں نئی آنے والی بہو اور بھابھی سے، اگر کنبہ مضبوطی سے جڑا ہوا ہے، بڑی توقعات وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ گھر بھی چلا سکتی ہے اور ہر ایک کا کام بھی کر سکتی ہے۔ نہ اس کا جسم تھکنا جانتا ہے، نہ اس کا دماغ مضمحل ہوتا ہے۔ وہ بیک وقت ساس، سسر، بیٹی، جٹھانی، نندوں اور سب کے بچوں کو خوش رکھنا جانتی ہے۔ لیکن اگر وہ بیمار پڑ جائے تو سب کو لگتا ہے کہ جیسے کنبے کی مشین چلتے چلتے رک گئی۔ حرمت کے بھی وہ مشین کے رک جانے والے دن آ رہے تھے“ـ یا پھر عورت بچے پیدا کرنے والی مشین ہے۔ جنس کا تصور روز مرہ کے کاموں مثلاً آٹا گوندھنے، مرغیوں کو دانا ڈالنے اور برتن مانجھنے جیسا ہی ہے۔ عورت کی اپنی جذباتی یا نفسیاتی کیفیت کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حرمت سوکھ جاتی ہے تو وہ خود کو یہ کہتے ہوئے کہ ”اب مجھے ماہواری نہیں ہو گی۔ پھر قربت کا فائدہ “ علی بخش سے دور کر لیتی ہے۔
حسن منظر کے ناولوں میں خیر اور شر کی کشمکش ہرجگہ نظر آتی ہے۔ ”دھنی بخش کے بیٹے“ کے مرکزی کرداروں کا تعلق متمول طبقے سے ہے۔ قدیم یونانی المیہ کے طرز پر یہ ناول بھی چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جس میں پہلے حصے میں کردار اپنا تعارف کرواتے ہیں، پھر کہانی آگے بڑھتی ہے، تیسرے حصے میں کرداروں کی اندرونی کشمکش سامنے آتی ہے اور چوتھے حصے میں ایک المناک احتتامیہ ہوتا ہے۔ نثر کی سادگی اور روایتی اسلوب کے باوجود ناول نگار تازہ موضوع کو زیر بحث لاتے ہوئے سماجی حقیقت نگاری کی عمدہ مثال قائم کرتا ہے۔ ناول میں جب دھنی بخش گاؤں یا حیدر آباد کا ذکر ہو تو منظرنگاری بہت تفصیل کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ ”دھنی بخش جب زندہ تھا تو اس کا گاؤں ایک خوبصورت اور آئیڈیل قسم کا پرانا گاؤں تھا۔ جو کئی نہروں کو عبور کر کے شمال اور جنوب کی طرف جانے والی سڑک کے بائیں کنارے پرموجود تھا جہاں لوہے کے ایک بورڈ پر جلی حروف میں لکھا تھا ” دھنی بخش کا گاؤں“ اور اس بورڈ کے پہلو میں ہی ایک بڑا اور اونچا بورڈ نصب تھا جس پر دھنی بخش فروٹ فارم اور پولٹری فارم بڑا بڑا لکھا تھا جس کے نیچے مرغی، انڈے اور موسم میں آم کےآگے ایک تیر بنا تھا کہ کدھر ان چیزوں کے لیے جاؤـ اور بائیں ہاتھ کو جا کر جہاں یہ سڑک ختم ہوتی ہے وہاں دھنی بخش کی حویلی ہے یعنی حویلی دھنی بخش جس نے اس سڑک کو جیسے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔لیکن اب نہ وہاں فروٹ فارم ہے نہ کسی نے سنا تھا کہ اُدھر کوئی پولٹری فارم ہے۔ رہا فروٹ فارم تو دھنی بخش کے گاؤں کے آس پاس کوئی آم کا باغ تک نہیں ہے جن کے لیے یہ علاقہ مشہور ہے، جہاں اکثر زمین دار اپنے باغ کو موسم میں ایک لاکھ یا زیادہ کے ٹھیکے پر اٹھا رکھتا تھا“۔
اس منظر نگاری کی کمی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب احمد بخش امریکہ پہنچتا ہے۔ یہاں تک کہ جو جزئیات احمد بخش کے اسکاٹ لینڈ کی سیر کرنے پر دکھائی گئیں وہ ان تفصیلات سے زیادہ گہری ہیں جو احمد بخش کے امریکہ پہنچنے کے بعد دکھائی جاتی ہیں۔ کردار نگاری میں اولا، حرمت اور علی بخش کے کردارتو مضبوط نظر آتے ہیں لیکن شاید یہ موضوع کا تقاضا ہے کہ احمد بخش کا کردار داخلی اور خارجی سطح پر عملی اور بعض اوقات فکری طور پر کمزور نظر آتا ہے۔ یا شاید یہ اس لیے ہے کہ احمد کئی ذاتوں یا شناختوں کو جی رہا تھا جیسا کہ ناول میں ذکرملتا ہے۔ ”احمد بخش کی کئی ذاتیں ہیں ایک قومی وفاداری کی، ایک سیاسی وفاداری کی، ایک مذہبی وفاداری کی، ایک لامذہبی جسے مارکسی سمجھا جاتا ہے۔ ایک مشرقی ایک مغربی اسی لیے تو وہ خوش نہیں رہتا۔ یوں لگتا ہے جیسے مغز قصائی کے کُندے پر رکھ کر اسے بغدے سے کٹوا رہے ہیں“ـ گو اولا کا کردار احمد بخش کے کردار کو فکری سہارا تو دیتا ہے لیکن پھر بھی بعض جگہوں پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ناول نگار کو بات آگے بڑھانے کے لیے خود مداخلت کرنا پڑ رہی ہے۔
احمد بخش دھنی بخش کا سب سے چھوٹا بیٹا اور ناول کا مرکزی کردار ہے۔ وہ ایک پڑھا لکھا لیکن حساس طبیعت کا مالک ہے۔ ”سولہ سال کا احمد بخش بائیس سال کے علی بخش سے کہیں سیانہ تھا“ـ گو وہ فکری طور پرانقلابی ہے جیسا کے اسی کی دہائی میں مارکسزم کو پڑھنے والا ہر طالب علم فکری طورانقلابی ہوتا تھا۔ اپنے آس پاس ہونے والے ظلم جبر اور زیادتی کی ہر داستان پر وہ کڑہتا رہتا ہے لیکن عملی طور پر وہ ایک کمزور کردار کے طور پر سامنے آتا ہے۔ تقریروہ بہت اچھی کر لیتا تھا لیکن چند واقعات کے علاوہ اس نے فکری کشمکش سے آگے بڑھ کرلوگوں کی حالت بدلنے کی عملی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے جب وہ حکمرانوں پر تنقید کررہا تھا تو پوسٹ ماسٹر صاحب نے اسے کہا کہ ”آپ ایسی تنظیم پیدا کریں جو لوگوں کے فکری شعور کو ابھارے!“۔ اس کے جواب میں بھی احمد بخش نے ایک لمبی تقریر کی جس میں حکمرانوں کی طرز زندگی اور طاقتور طبقات کے خلاف نفرت تھی لیکن آخر پر جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ” ایسا وقت شاید آئے گا نہیں۔ انقلاب آتے رہیں گے۔ جمہوریتیں بنتی رہیں گی اور لوگ وہی کے وہی رہیں گے، ہندوستانی پاکستانی فلموں کی ہیروئن کی طرح جو ایک ناچ میں دس پوشاکیں بدلتی ہے اور رہتی وہی کی وہی ہے“، تو وہ ایک شکستہ اور تھکا ہوا نوجوان نظر آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر یہ بے مقصدی زمیندار گھرانوں کے لڑکوں ہی میں کیوں آتی ہے؟، اور اس سوال کا جواب اس کے دماغ نے فوراً ہی ڈھونڈ نکالا، ”وہ خوف کہاں ہے میرے جی میں جو غربت سے ڈرا کر سب کچھ کرا لیتا ہے“۔ وہ اپنےبھائی کی عیاشیوں اور جنسی آزادیوں کو روکنے کی ہمت تو رکھتا ہے لیکن اس سلسلے میں مستقل مزاج نہیں ہے۔ وہ اپنی بستی اور آس پاس کے حالات تو بدلنا چاہتا ہے لیکن زمینداری یا گھر کے باقی معاملات کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں۔
اس سارے وحشت زدہ اور ظالم سماج سے بھاگ کر وہ امریکہ جاتا ہے۔ امریکہ وہ کسی مذہبی آزادی یا اخلاقی بندھنوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ اپنے ملک کی ہر چیز سے بیزاری کی وجہ یہ تھی کہ ”جو لوگ اسے استعمال کر رہے تھے وہ اسے آنے والوں کے لیے بہتر چھوڑ جانے کے ارادے سے نہیں کر رہے تھے۔ کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے۔ وہاں والوں کا یہ فلسفہ تھا کہ انہیں
خود اپنے لیے جینے والوں سے نفرت تھی لیکن جی سب اپنے لیے رہے تھے“۔ احمد بخش جب امریکہ جاتا ہے تو وہاں کے سٹڈی سرکلز میں ہونے والے مکالمے بہت اہم ہیں۔ احمد بخش مشرق کا نمائندہ ہوتے ہوئے اپنی تہذیب، ثقافت، رسم و رواج اور رہن سہن کے بارے میں جو باتیں ساتھی طلبا کو بتاتا ہے وہ ان کے لیے نئی لیکن دلچسپ ہوتی ہیں۔ ان مکالموں میں ایک بالکل منفرد احمد بخش نظر آتا ہے جو اس کردار سے مختلف ہے جو امریکہ آنے سے پہلے آس پاس کی ہر چیز سے نفرت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کردارکی فکری سطح پر ہونے والی تبدیلی سے زیادہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ناول نگار مشرقی تہذیب کی برتری دکھانے کے لیے احمد بخش سے یہ سب کہلوا رہا ہے۔ مثلا مشرقی معاشرے کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ”ماں باپ کا گھر، جو کہلاتا ماں کا گھر ہے اور وہ بڑا سولڈ سٹرکچر ہوتا ہے۔ مکان ڈھے جائے پر وہ رہتا وہیں کا وہیں ہے۔ اس کی دیواریں اور چھت رشتے کے بنے ہوئے ہیں۔ وقت، دوری اور آندھی یا پانی سے ٹوٹ نہیں جاتے“۔
اس کے جواب میں ایک امریکی لڑکی کہتی ہے۔ ”thats not with us. یہاں اگر لڑکی نیویارک سے اپنے میکے میں جائے تو پتا چلے گا وہ لوگ وہاں سے جا چکے ہیں ۔ ہو سکتا ہے وہ گھر ٹوٹ چکا ہو اور ماں باپ دونوں لاپتا ہوں“۔ وہ اپنے معاشرے کی خرابیوں کو سوچتا تو ہے لیکن اسے ان لوگوں کو بتانے سے جھجھکتا ہے۔ مثلاً جن بوڑھوں کی سگی اولاد نہ ہو انہیں اپنے گھر رکھنے کا کوئی روادار نہیں ہوتا یا جن بچوں کے والدین نہ ہوں وہ غربت میں زندگی گزارتے ہیں اور ان بوڑھوں یا بچوں کی ذمہ داری کوئی بھی نہیں لیتا۔ یہاں تک کہ ان کی ذمہ داری حکومت پر بھی عائد نہیں ہوتی۔ شادی کے بعد اس معاشرتی برتری کی داستانیں احمد بخش کی بیوی اولا کے سامنے نہیں چلتیں۔ بلکہ اولا کا کردار تو equalizer محسوس ہوتا ہے جو اس تہذیبی بحث کو معنی خیز بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ شادی کے بعد اولا سے اپنے معاشرے کی اچھائیوں مثلاً شرم و حیا، صلہ رحمی اور ایکتا کا ذکر کرتا ہے تو اولا اکثر اس خیال اور بات کو مسترد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ” تم مشرق والےprude ہوتے ہو۔ ہے تمہارے ہاں سب کچھ لیکن ظاہر یہی کرتے ہو کہ شرم اور رحم کے علاوہ تمہارے یہاں کچھ نہیں“۔
اولا سے شادی کے بعد جب اس کے بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تونئے وسوسے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کرپریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے اس کے بچے بالغ ہوتے ہی اس کو چھوڑ کرکہیں اور رہنے لگ جائیں گے۔ یا اس کی بیوی اسے چھوڑ کر اپنے ملک واپس چلی جائے گی اور وہ جب مرے گا تو اس کو جلایا جائے گا۔ یہ خوف اور سوچیں اسے واپس اپنے ملک جا کر کچھ کرنے پر اکساتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ ” ایک ایسے ملک میں مرنا جہاں زندگی کی آخری بیماری میں آس پاس بیٹھنے والے نہ ہوں، نہ دم نکلتے وقت کوئی ہاتھ پکڑے ہو، نہ نہلا کر کفن پہنانے والے، تو سارا کام کوئی سرکاری یا پرائیویٹ ایجنسی کرے گی جس کا بل آس پاس کے مکین چکا دیں گے اور وہ لے جا کر۔۔۔۔ “ـ امریکہ میں رہتے ہوئے وہ ایک الگ قسم کے وہم اور خطرے کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک خلش میں گرفتاررہتا۔ اس کی سوچیں اسے اولا سے اور باقی سب چیزوں سے بھی بیگانہ کر دیتیں۔ وہ امریکہ میں رہتے ہوئے پندرہ سالوں میں فکری طور پر واپس اپنی روایت سے جڑ جاتا ہے۔ اسے اپنی اولاد ”سیلی“ اور ”ہومر“ کے بڑے ہونے کی فکر ستاتی ہے۔ وہ اس تہذیب میں خود کو مدغم کرنے سے انکار کردیتا ہے۔ اب وہ بچوں کو کھانے کی میز پر اپنے ملک کی تہذیب کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ انہیں اپنے پیدائیشی ملک سے نفرت پیدا کر کے اس ملک کے لیے محبت پیدا کرنا چاہتا ہے جسے انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ امریکہ چھوڑنے پر” احمد بخش کہتا ہے میں صرف بچوں کی وجہ سے یہ ملک نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ میں تنہائی کی موت نہیں مرنا چاہتا ہوں۔ نہ ایک روح اور جذبات سے عاری ان سنے ریٹر کو اپنا جسم حوالے کرنا چاہتا ہوں وہ جسم جسے اتنے سال سینت کر رکھا۔ جوچند منٹوں میں مجھے استخواں اور گوشت پوست سے ایک یا آدھ کلو سفید راکھ میں تبدیل کر دے“۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے سال گزارنے کے باوجود وہ امریکہ کو کبھی اپنا وطن نہیں سمجھتا۔ اپنے ملک کا ذکر کرتے ہوئے وہ پاکستان نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے کہ ”اپنے ہاں لوگ یہ کرتے ہیں ایسے رہتے ہیں“ وغیرہ۔
وہ اپنے لوگوں کی مدد کرنے یا ان کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے پاکستان واپس لوٹتا ہے۔ واپسی پر اسے سب کچھ پہلے جیسا لگتا ہے۔ لوگوں کے رہن سہن، رسم و رواج اور عادات کی یکسانیت کو دیکھ کر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ آخر پر وہ شکست خوردہ، کمزور اور بے بس کردار کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اپنے ملک میں واپسی پربھی وہ تنہا تھا، کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا اور سب اسے ایک عجیب مخلوق سمجھتے تھے۔ احمد کا المیہ یہ تھا کہ وہ جس طرح آبائی ملک چھوڑتے وقت اکیلا تھا، بیس برس گزرنے کے بعد پلٹنے پر بھی تنہا ہی تھا۔ وہ خود یہاں نہیں آنا چاہتا تھا بلکہ یہ تو اولا تھی جو اکثر اصرار کرتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ وہ واپس جائے اور وہاں کے لوگوں کی زندگی بدلے۔ اس ساری فکری یا تہذیبی کشمکش کے بعد، جو احمد بخش کے کردار میں نظر آتی ہے، یہ ناول ایک تہذیبی اور معاشرتی المیہ بن جاتا ہے جسے مشرقی معاشرے کا المیہ کہا جائے تو غلط نہ ہو گا۔
اولا کا تعلق سوئیڈن سے تھا۔ امریکہ وہ تعلیم حاصل کرنےکے لیے آتی ہےاور اپنی پہچان ایک ادیب کے طور پر بناتی ہے۔ فکری طور پر اولا ایک واضح تشخص کی حامل ہے۔ اولا کے آنے سے احمد بخش کی تنہائی، اداسی اور فکری انتشار کا کچھ عرصے کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اولا کے کردار سے ناول نگار مشرقی اور مغربی معاشرے میں پائی جانے والی تہذیبی کشمکش، خوبیوں اور خامیوں کو سامنے لاتا ہے۔ احمد بخش سے اولا کے وہ مکالمے جو خاص کر امریکی ماحول، مذہب کے کردار، تیسری دنیا کے مسائل اور رسم ورواج پر مشتمل ہوتے ہیں وہ ناول کا مضبوط ترین حصہ ہیں۔ اولا کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔ بعض اوقات ہندوستان اور پاکستان پر اس کی معلومات احمد بخش کو حیران کر دیتی ہیں۔
علی بخش دھنی بخش کا دوسرا بیٹا ہے۔ اس کے کردار میں ایک جاگیردار کی تمام روایتی برائیاں یا عادات موجود ہیں۔ وہ کم عمری میں ہی بدتمیز ہو گیا تھا۔ ”سب لڑکوں کی طرح وہ ماں کے سامنے سگرٹ پیتا تھا اور اس کے مُنھ پر سگرٹ کا دھواں چھوڑ کر اسے تنگ کیا کرتا تھا“ـ وہ اکھڑ، بدمزاج اور بے حس تھا۔ ”اسے اپنے سوا کسی کی فکر نہیں تھی۔ اس کی آواز بلند تھی، غصہ ناک پر رہتا تھا اور اکثر سننے میں آتا تھا اس کی نظریں لڑکیوں پر رہتی ہیں“ـ اس نے اپنی چھوٹی عمر میں آس پاس موجود سارے بڑے نشے کر لیے تھے۔ وہ اس قدر جلدی میں ہوتا تھا جیسے دنیا میں کوئی ایسا نشہ مرنے سے پہلے رہ نا جائے جس کی طلب اسے دوسری دنیا میں ہو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی نشئی دوست دنیا کو داغ مفارقت دے جاتا تھا تو اس کے غم کو مٹانے کے لیے بھی وہ زراب یا چرس کا سہارا لیتا تھا۔ ”وہ بائیس سال میں پانچوں بڑے نشے کر چکا تھا۔ شراب اپنی ایک سو ایک شکلوں میں وہ پیٹ بھر کر پی چکا تھا، ان میں کوہلی وسکی بھی تھی یعنی ٹھرا جو سڑے ہوئے پھلوں سے گاوں میں بنتی ہے اور نشئی غریبوں کی غم گسار ہوتی ہے، ٹنکچر جو کُپی یا بمباٹ کے نام سے بکتا ہے، اسکوچ، بھنگ، چرس، افیون، ہیروئن اور مختلف گولیاں، ہر چیز اس کی ساتھی تھیں“۔ اس کے علاوہ اسے بیل پالنے اور لڑوانے کا شوق تھا۔ وہ بیلوں کو کتوں پر فوقیت دیتا تھا۔ پالتو جانوروں کے بارے میں اس کی رائے تھی کہ ” جانوروں میں بیل اچھے ہوتے ہیں۔ جہاں باندھو دن بھر کھڑے یا بیٹھے جگالی کرتے رہتے ہیں اور رسی کھل جائے تو بھی بھاگ نہیں جاتے۔ ریس کے گھوڑے پالنے سے یہ شوق سستا ہے۔ کتے خواہ وہ شکاری ہوں خواہ بھالو یا سور سے لڑانے کے، قابل بھروسا نہیں ہوتے۔ منتظر رہتے ہیں کہ کھلیں اور ہاتھ نہ آئیں“۔
علی بخش کا کردار اپنی اصل میں ناول کا مضبوط ترین کردار ہے۔ وہ زمینوں کو گروی رکھ کراپنے تمام شوق پورے کرتا ہے۔ اپنی زمینوں کو گروی رکھ کرعیاشیاں کرنے کا یہ طریقہ وادی سندھ کے زمینداروں کی پرانی ریت ہے۔ تقسیم سے پہلے پنجاب کے جاٹوں اور سندھ کے زمینداروں کی زمینوں کا ایک بڑا حصہ ہندو بنیوں کے ہاں گروی رکھا ہوا تھا۔ زمینوں سے جتنا وہ کماتے تھے اس سے زیادہ میلوں، شادیوں اورلڑائیوں میں خرچ کر دیتے تھے۔ تقسیم کے بعد اب یہ کام وہ بنک سے قرضہ لے کر پورا کرتے ہیں۔ علی بخش بھی ویسا ہی جاگیردار ہے۔ وہ عورتوں اور شراب کا شوقین ہے۔ شراب وہ اپنی کمائی کے مہینوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پیتا ہے۔ فصل کی کٹائی کے بعد وہ ولائیتی اور بعد کے مہینوں میں دیسی یہاں تک کے کُپی سے بھی کام چلاتا ہے۔ خوبصورت عورت اسے جہاں سے ملے وہ عمر اور ذات پات کی قید سے آزاد ہو کر اسے شہر کے کسی فلیٹ میں، کسی پہاڑی مقام پر یا اپنے بنگلے میں لے آتا ہے۔ لوگوں کا حق کھانے، ان کی عزت کو تار تار کرنے اور غریبوں پر ظلم کرنے کے باوجود وہ مزاروں پر جاتا ہے اور پیروں یا دم درود کرنے والوں سے خوف کھاتا ہے۔ وہ جو کرنے کی ٹھانتا ہے اسے پورا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔
حرمت علی بخش کی پہلی بیوی ہے۔ اس کا مقام گھر میں وہی ہے جو جاگیردار خاندان میں روایتی پہلی بیوی کا ہوتا ہے۔ گھر کا سارا خرچہ علی بخش اسے ہی دیتا ہے۔ وہ علی بخش کی تمام بیویوں اور بچوں کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ ہر نئی آنے والی سوتن کو نہ صرف برداشت کرتی ہے بلکہ ان کے مر جانے کے بعد ان کی اولادوں کو بھی پالتی ہے۔ حرمت کا کردار بنگلے اور گھر کے درمیانی معاملات میں پل کا سا ہے۔ علی بخش کے لیے وہ بیوی کم ماں بن کر اس کے تمام عیبوں پر پردہ ڈالتی اور سہولت کار بنتی ہے۔ علی بخش اسے اپنے کمرے میں تب ہی بلاتا ہے جب وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ حرمت اسے پریشانی میں لعنت ملامت نہیں کرتی بلکہ وہ اپنی خاموش قربت سے اس کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے۔
” دھنی بخش کے بیٹے“ حسن منظر کا نمائندہ ناول ہے۔ اس ناول نے انہیں افسانہ نگاری کے ساتھ ساتھ ناول نگاری میں بھی ایک اہم مقام دلایا۔ نو آبادیات اور استعمار کے خلاف جو نفرت ان کے افسانوں میں نظر آتی ہےـ وہ جاگیرداری کے نظام پر تنقید کرتے ہوئے اس ناول کا بھی خاصہ ہے لیکن حسن منظر صاحب اس سے آگے بڑھ کر زیر نظر ناول میں مشرق اور مغرب کے معاشروں کی تہذیبی تفاوت پر بھی اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک طرف مغربی معاشرے میں پائے جانے والی جنسی بے راہ روی، ظلم، بڑھتے ہوئے گن کلچر اور بے حسی دکھائی ہے، تو دوسری طرف اپنے معاشرے میں پائے جانے والے جبر، عورتوں پر ہونے والے ظلم، وٹہ سٹہ کی شادیوں، حکمرانوں کی طاقت اور غربت پر بھی تنقید کی ہے۔ مغربی معاشرے میں پائی جانے والی اخلاقی برائیوں اور خاص کر بچوں کی تربیت ان کے لیے ہمیشہ اہم موضوع رہا ہے۔ مذکورہ ناول سے پہلے حسن منظر صاحب کا اس حوالے سے ایک طویل تجزیاتی مضمون ” موجودہ معاشرہ اور برہنہ فلمیں“ کے نام سے 1998 میں شائع ہوا۔ بچوں کے حوالے سے یہ مضمون ان کے طویل سائیکائٹری تجربے پر مبنی ہے۔ اس ناول میں بچوں کی فکر کے حوالے سے اٹھائے گئے بہت سے سوالوں کے جواب اس مضمون میں مل جاتے ہیں۔ ”دھنی بخش کے بیٹے“ اردو کا ایک اہم ناول ہے جس کے بغیر اردو ناولوں کا تذکرہ نامکمل ہو گاـ۔