گُل دستۂ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں۔ تحریر: عاصم بخشی
تنقیدی تھیوری کے تحت قصوں کہانیاں پر مشتمل افسانوی ادب کی ساختی حرکیات تاحال ایک ایسا موضوع ہے جس پر کی جانے والے بحث کئی اعتبار سے محدود ہے۔ مثال کے طور پر روایتی ساسوریائی ماڈل نسبتوں کی تلاش سے مدد لیتے ہوئے خود کو متن کے علامتی نظام تک محدود رکھتا ہے اور یوں نت نئی تعبیراتی بصیرتوں تک رسائی کا مقصد حاصل کرتا ہے۔ ساختیاتی روایت کی ’ساخت‘ نہ تو متن کی تہوں میں موجود ہندسی (یعنی جیومٹری سے متعلق) اور نہ ہی طبیعیاتی نظام سے کوئی سروکار رکھتی ہے۔ دیکھا جائے تو تنقیدی روایت میں یہ مباحث تاحال حاشیائی کہلانے کے مستحق بھی نہیں ۔ راقم کی مراد کم وبیش اس نادر (مگر شایدنیم) تنقیدی جہت سے ہے جسے امریکی لکھاری کرٹ وانیگٹ نے اپنے مشہور لیکن قدرے بے فائدہ مانے جانے والے تھیسس میں ’’کہانیوں کی شکل‘‘ کا نام دیا تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ یونیورسٹی آف شکاگو نے وانیگٹ کی اس پُرمذاق نظری کاوش کو شاید اس کی عملی بے کاری یا پھر شاید اس وجہ سے ردّ کر دیا کہ وہ اس انوکھی کارتیزی چھیڑ چھاڑ پر مشتمل کچھ عجیب سی ادبی فن کاری تھی۔ ناول کے فن پر ہر سال لکھے جانے والے سینکڑوں صفحات او ربیسیوں تعبیراتی مضمون یوں تو کسی ادبی فن پارے کی ساخت میں تہہ در تہہ غوطہ زنی کرتے ہیں لیکن شاذونادر ہی خالص ہندسی نقطۂ نظر سے جمالیاتی مشاہدے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔
لہٰذااس قسم کے سوالات کہ بیانیے کی لغوی بنت کاری اور اس کے اجزاء کی باہم پیوندکاری کیسے کی گئی ہے حاشیوں پر ہی رہتے ہیں اور تکنیکی اعتبار سے دائرۂ بحث میں نہیں آتے۔ ادبی لطف اپنی جگہ لیکن کسی نقاد کے لیے تجزیاتی ڈھانچوں کا انتخاب کرتے سمےعملی افادیت کا سوال بہرحال اپنی جگہ قائم و دائم رہتا ہے۔ رہا قاری، تو وہ تو یقیناً کسی اور ہی دنیا کا باسی ہوتے ہوئے بیانیوں کے بارے میں بے دریغ اور انوکھے طریقوں سے اپنی رائے کا اظہار کرنے میں آزاد ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر کیا آپ کوئی ناول پڑھتے وقت خود سے یہ پوچھنا پسند کرتے ہیں کہ آیا آپ دائرے میں گھوم رہے ہیں یا کسی خطِ نیم مستقیم پر گامزن ہیں؟کیا یہ بیانیہ کوئی دائروی یا لاخطی قوس کی شکل رکھتا ہےیا سیدھا آگے بڑھتے ہوئے اپنی خطی شناخت برقرار رکھنا چاہتا ہے؟عین ممکن ہے کہ کہانی میں آگے پہنچ کر آپ خود سے یہ سوال پوچھ بیٹھیں کہ جسے آپ غلطی سے دائرہ سمجھ بیٹھے وہ دراصل نصف درجن ہم مرکز دائروں کی کوئی کہکشاں تو نہیں تھی؟
پھر یہاں صرف جیومٹری کا رفرما نہیں، فزکس بھی اتنی ہی کارآمد ہے۔ کیا دو مخالف قوتیں آپ کو بار بار بیانیے کے داخل و خار ج میں تو نہیں پھینک رہیں؟ بیانیے کی سب سے اندرونی تہہ میں اترنے کے لیے کم سے کم کتنی قوتِ جمود پر حاوی ہونا لازم ہے؟ کیا زمان مکان کو اپنے گھیراؤ میں لیے ہے یا اس کےاندر سرایت کر چکا ہے؟ یا یہی سوال خود سے یوں پوچھ لیجیے کہ کیا آپ ایک ایسی کہانی میں ہیں جس پر مکانیت کا غلبہ ہے یا زمانیت کا؟
اساتذۂ تنقید سے جھاڑ پڑنے کا خطرہ نہ ہو تو ہم قارئین ان سے نظر بچا کر کم و بیش یہی استدلال دائرۂ منطق میں بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح بیانیہ قوسوں کی ہندسی لطافتوں کو ساخت کی صریحی جہت کے طور پر کسی نہ کسی طرح سامنے کی بات سمجھ لیا جاتا ہے ، بالکل ایسے ہی خالص منطقی معاملات کو تاریخی، نفسیاتی یا بشریاتی معاملات مان کر خاص انہی پیراڈائموں میں زیرِ بحث لایا جاتا ہے۔ سرونٹس مہم جوئی کی فطرت کا مطالعہ کرتا ہے، فلابرٹ روزمرہ میں دلچسپی رکھتا ہے، پرؤسٹ اور جوائس ماضی اور حال کی پیچیدگی سے نبردآزما ہیں، ٹالسٹائی ماورائے عقل میں غوطہ زن ہے۔ غرض گمان ہوتا ہے کہ خالص منطق کے خشک مان لیے جانے والے مباحث دلچسپ وجودی معاملات کا بھیس بدل لیں تو اپنے اندر کچھ نہ کچھ تازگی کے سامان رکھتےہیں۔
لہٰذاکہانیوں کی شکلوں ہی کی طرح یہ بحث بھی تاحال نہیں اٹھائی گئی کہ کیا کسی قاری کا خود سے یہ سوال پوچھنے کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ آیا وہ ایک ایسے بیانیے کی پڑھت میں ہے جس کا محور ارسطوئی ثنویت ہے یا کوئی تکثیری یا فازی منطقی ڈھانچہ؟ کیا وہ دوئیوں کے علامتی چیستان میں پھنسا ہوا ہے یا تکڑیوں کے اور کیا لکھاری نے اپنے بیانیے میں کوئی ایسے چوردروازے رکھ چھوڑے ہیں کہ ایک واقعتاً مہم جو قاری نادیدہ اور متبادل بیانیہ قوسوں پر اپنے قدم رکھ سکے ؟ ایسی قوسیں جو اپنے اندر مزید نت نئی ہندسی حیرانیاں رکھتی ہوں؟
اس ساری تمہید کو کسی قدر ٹھوس مفروضے کی شکل دی جائے تو سوال کچھ یوں ہو گا: کیا مناسب طوالت رکھنے والے افسانوی بیانیوں کے بارے میں لازم اور امکانی ہندسی ساختوں، اور بنیادی اور ضمنی منطقی ڈھانچوں کے تناظر میں سوچنا جمالیاتی اعتبار سے مفید ہو گا؟
اسامہ صدیق کا ناول ’’Snuffing Out the Moon ‘‘ نہ صرف اس تحقیقی مفروضے کی جانچ پڑتال میں ہماری مدد کرتا ہے بلکہ جنوبی ایشیائی ناول میں تازہ مابعدالجدید تجربات کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے بھی راہیں کھولتا ہے۔ یہاں ہمارے سامنے ایک ایسا طے شدہ سانچہ ابھرتا ہے جس کے تمام چھوٹے بڑے پرزے بہت دھیان سے اپنی جگہ بٹھائے گئے ہیں اور لطیف ترین خلا کو بھی بہت صفائی سے پُر کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ایسے لکھاری کے ہاتھوں ہوا ہے جو منطقی معاملات میں رسمی طور پر تربیت یافتہ ہے۔ ایک تہہ دار اور پیچیدہ مکانی و زمانی ساخت ایک ایسی واضح ہندسی شکل میں پھیلتی چلی جاتی ہے جو کہیں کہیں تو انتہائی متناسب ہے لیکن کہیں کہیں لطیف کھردرا پن بھی رکھتی ہے۔ پانچ غیرہم مرکز موضوعی دائروں کی ایک تہہ کے اوپر چھ مختلف بیانیہ قوسیں یوں جمائی گئی ہیں کہ اپنے طبق پر رہتے ہوئے دائرہ وار گھومتی ہیں۔ لیکن جہاں ناول کی مکانی ساخت کو مخصوص جغرافیائی منظرنامے تک محدود کیا گیا ہے، وہیں اسے زمانی حرکیات کے پھیلاؤ میں بھی پرو دیا گیاہے۔ کردار بالتعریف مکانی اجزاء ہوتے ہوئے اپنے اپنے زمانوں تک محدود ہیں لیکن اگر کوئی قاری ان کے ساتھ ذرا زیادہ وقت گزارے تو وہ جذباتی اعتبار سے زمانی سرحدوں کے آر پار ہوتے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی لطیف تجریدیت ہے جو اپنی حرکیاتی تہہ کے باعث صرف قاری کے ذہنی منطقے پر ہی وجود پاتی ہے۔
تاہم یہ حرفِ آخر نہیں۔ ہر بیانیہ قوس بھی داخلی اعتبار سے اپنے لطیف خدوخال رکھتی ہے گو بنیادی ساخت کے برعکس یہ مخصوص ہندسی لطافتیں ٹھوس مصنفی نمونے نہیں بلکہ دریافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں ہمارا اسلوبی طور پر ہمہ جائی مصنف تفویض کردہ ساخت چھوڑ دیتا ہے اور کئی ننھی منی بیانیہ قوسوں کو آزادانہ حرکت کرنے دیتا ہے جو کبھی تو مبہم ہم مرکز دائروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھار خطی خدوخال اختیار کر لیتی ہیں۔
مثال کے طورپر پہلے موضوعی مرکز یعنی کتاب ِ سراب کو دیکھتے ہیں ۔ قوس کا آغاز پیکانِ زماں کے بیسویں صدی قبل مسیح تک کھینچے جانے سے ہوتا ہے۔ دنیا کے اسٹیج پر شیشے اور چاکلیٹ کے ظہور کے ساتھ ساتھ یہ وہ صدی تھی جہاں سے بزنجی دور کی وادیٔ سندھ کی تہذیب کے تنزل کا آغاز ہوتا ہے۔ بڑے دائرے میں سمایا ہوا پہلا ہم مرکز ننھا دائرہ جدیدیت اور ترقی کے سراب کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا یوروپی جدیدیت کا جانامانا تصور نہیں جسے ہم مغربی جدیدیت کے نام سے جانتے ہیں۔ آئزن ستاد کی سماجی سائنسی ٹائپ سازی سے کافی زیادہ مطابقت رکھنے والا اسامہ صدیق کا یہ ادبی تجربہ عصری اعتبار سے جدیدیت کے ایک مانوس تصور کو ماضی بعید میں لوٹاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ستھوئی ایک قطبی اور کسی حد تک نظریاتی کشمکش کا شکار ہے، پرکا غالباً نتائجیت پسند اور لازماً کثرت پسند نظریاتی پیراڈائم کی بازیافت کی بھرپور کوشش پر مائل ہے۔
قدرے تیز رفتاری سے ڈھائی ہزار سال آگے بڑھیے تو ہم خود کو گندھارا تہذیب میں پاتے ہیں۔ یہاں بدھ مت کی سرزمین پر جاری بحث گہری فلسفیانہ جہات رکھتی ہے۔ گُرو بدھ متر جو کافی حد تک تحریک تنویر کی عینیت پسندی سے مطابقت رکھتا نظر آتا ہے، ایک ایسی دنیا میں ظاہر اور حقیقت کے بیچ کوئی درمیانی راستہ نکالنا چاہتا ہے جو اب تک ’مائتھوس‘ سے ’لوگوس‘ یعنی کسی اساطیری تناظر سے عقلی تناظر کی جانب بڑھنا شروع نہیں ہوئی۔ قاری اس پڑاؤ پر ٹھہر کر خود سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا اس مقام پر زیرِ متن کوئی ایسی واحد موضوعی لہر دوڑتی ہے جو سراب سے متعلق ہو؟ یا ظاہر اور حقیقت دونوں ہی کا اپنا اپنا فریبِ نظر سراب کے ایسے خواص رکھتا ہے جن سے نمٹنا قاری پر چھوڑ دیا گیا ہے؟
مزید ایک ہزار سال آگے بڑھ جائیے تو ہم خود کو جہانگیر کے زمانے میں پاتے ہیں جہاں مغل طاقت کے ڈھانچے موہوم ہو تے ہوئے مستقبل کی سامراجی قوتوں کے لیے اپنے دروازے کھول رہے ہیں۔ پیکانِ زماں اب ۱۸۵۷ء میں آ کر رکتا ہے جہاں ایک داستان گو جو بظاہر افسانوی سرابوں کی دنیا میں پھنسا اپنے سامعین کو مسحور کر دینے کی کوشش میں ہے، دراصل ایک آخری سانسیں لیتے ثقافتی منظر نامے کے بکھرے ہوئے خدوخال بچانے میں لگا ہے۔ اس کے بعد ہم بیسویں صدی کے لاہور میں پہنچتے ہیں جہاں رفیعہ بیگم ایک نادیدہ اور بے اثر عدالتی نظام کے سراب سے تسکین پانے کی امید لگائے بیٹھی ہے۔ ہمارا آخری موضوعی دائرہ بیانیے کو ستر سال مستقبل میں لے جاتا ہے جہاں استبدادی اور مطلق العنان آبی اتحاد بڑے پیمانے پر کھڑے کیے گئے ایک تکنیکی سراب کو بچانے کی پوری کوشش میں لگے ہیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام موضوعی دائرے ایک دوسرے کے ساتھ بہت سختی سے نہیں بندھے۔ مصنفی ٹائپ سازی کے باعث یہ نہ صرف ایک دوسرے کے آر پار ہوتے محسوس ہوتے ہیں بلکہ یہاں مشترکہ موضوعاتی لطافتیں بھی دریافت کی جا سکتی ہیں۔ سراب اور شگون کے پہلے دو موضوع جن سے اپنی اپنی کتابیں منسوب ہیں یک لخت کتابوں کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتے بلکہ کتابِ سوز اور کتابِ نفرت میں مدغم ہوجاتے ہیں۔ پھر یہ چاروں موضوعات یک جا ہو کر بیانیے میں سرایت کرتے اور اسے مزید پھیلاتے ہیں ، یہاں تک کہ وہ اپنی اٹھان کو پہنچ کر انحراف کے موضوع پر ختم ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً جو پہلے پہل ممیزاور غیرہم مرکز دائرے معلوم ہوتے تھے، بالآخر پیکان ِ زمان کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مزید پیچیدہ ہندسی ساختوں میں ڈھل جاتے ہیں۔
جہاں تک انشقاقی بکھراؤ اور تاریخ وارانہ ندرتوں کی بات ہے تو یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا اسامہ صدیق کی سوچی سمجھی ادبی مہم اینٹی ناول ہے؟ ناول کی روایت سے اس حد تک انحراف کی تہمت نہ بھی لگائی جائے، پھر بھی اس بات میں کسی حد تک سچائی ضرور ہے۔ تاہم یہ بولانو اور کورتازار جیسا عام اینٹی ناول نہیں۔ مزید سوال یہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا یہ ایشیائی اینٹی ناول کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ سوال سکہ بند نقادوں کے لیے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، تاہم ناول کا لہجہ واضح طور پر مشرقی ہے جو اپنے قصہ گوئی کے شوق، مختصر حکایتی قوسوں اور قیاسی استدلال جیسے عوامل سے عبارت ہے، جو مقامی وجودیات اور علمیاتی ساختوں میں گندھے ہوئے ہیں۔ نتیجتاً ہمیں ایک خردافروز افسانوی فن پارہ حاصل ہوتا ہے جس میں متعلقہ علاقائی فلسفوں کی آمیزش ہے۔ لہٰذا علمیائے جانے کا یہ عمل بس اس حد تک ہے کہ اس منفرد ادبی کاوش کو ایک متلون مزاج مابعدالجدید تجربہ بننے سے ایک قدم پہلے رک جاتا ہے اور علمیت اتنی قلیل بھی نہیں کہ اسے عوامی انداز کا پاپولر فکشن گردانا جائے۔
لیکن بہرحال Snuffing Out the Moon میں ساختی حرکیات کے انوکھے پن کی شناخت کی قیمت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لسانی اسلوب کے عناصر پر کم غور کیا جائے۔ جنوبی ایشیائی ناول کی دنیا کے قدرے محدود تنقیدی منظرنامے میں اسلو ب او رفکر کے مخصوص عناصر عام طور پر زیرِ بحث نہیں آتے۔ مثلاً بنگالی مصنف ضیاء حیدر رحمان کے ناول In the Light of What We Know کی اشاعت کے دس سال بعد بھی اس کے علمیاتی، اور بالخصوص ریاضیاتی عناصر جنوبی ایشیائی نقاد کی نگاہوں کو اپنی جانب متوجہ نہیں کر سکے۔ بالکل اسی طرح گمان کیا جا سکتا ہے کہ اسامہ صدیق کی غنائی نثر میں جا بجا پھیلے ہوئے سائنس فکشن، الٰہیاتی قیاس آرائی اور ماحول مرکز فکری عناصر غالباً اس سیاسی فکر کے بوجھ تلے دب جائیں گے جو یہ ناول اپنی پشت پر لادے نظر آتا ہے۔
کسی بھی ادبی ترجمے کی طرح Snuffing Out the Moon کے ترجمے بعنوان ’چاند کو گل کریں تو ہم جانیں‘ کے دوران پیشِ نظر لسانی ترجیحات پیچیدہ اور شش جہت تھیں۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہدفی زبان، یعنی اردو کو کسی ایسے پینٹ برش کے طور پر استعمال کیا جائےجو بیانیے کی ایک دوجے کو کاٹتی قوسوں کو ابھارنے اور آراستہ کرے۔
یہ تو سامنے کی بات ہے کہ کوئی بھی بلند نظر ترجمہ ایک ایسا آدرش قائم کرتا ہے جو اپنے اندر کچھ مخصوص واضح او رمبہم سمجھوتے رکھتا ہے۔ اس آدرش کا حصول نہ صرف مترجم کی قابلیت (اور نااہلیت) بلکہ ہدفی زبان کی مخصوص تحدیدات پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ اس ترجمے میں بھی یقیناً بہت سے ایسے عوامل کی نشاندہی کی جا سکتی ہے جو اسے اس کے قائم کردہ آدرش تک پہنچانے میں رکاوٹ رہے۔اصولاًزبان کو اپنے زمانی و مکانی تعاملات کے باعث بیانیے کی بدلتی شکلوں کے ساتھ بدلتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ بدلاؤ تیز رفتار ہو تو ایسا ممکن ہے کہ قاری لہجوں میں تیزی سے تبدیلی کے ساتھ ہانپتا رہ جائے اور اس قسم کی آدرشیت متن کی روانی اور لطف میں حددرجے کمی کا باعث بنے۔ کسی بھی بدیسی زبان کی طرح انگریزی جنوبی ایشیائی ثقافتوں کے معاملے میں ایک ناگزیر سطحیت کی کڑوی گولی نگلتی ہے۔ زبان کی رنگینی اور کسی قدر حقیقت آرائی کی خاطر اصل زبان میں شامل کچھ مخصوص ثقافتی اشارے اور اسماء کو عمومی طور پر اسی طرح لے لیا جاتا ہے۔ چونکہ کسی بدیسی ثقافت کی انگریزی زبان میں بُنت کاری دراصل ایک درجے کی ترجمانی ہی ہے لہٰذا اس مخصوص ناول اور بالعموم زیادہ تر جنوبی ایشیائی ناولوں کے معاملے میں ترجمے کا عمل اصل کی بازیافت ہے۔ وضع کا یہ عمل اس وقت اپنے آدرش کے انتہائی قریب پہنچ جائے گا جب مصنف اور مترجم ایک مضبوط اشتراک سے کام کریں گے ۔
ایک قاری مترجم کے طور پر اصل متن سے وفاداری نبھانے کے ساتھ ساتھ راقم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مصنف کے ساتھ کام کرتے ہوئے اسلوبی عناصر کو ایک تازہ اٹھان دی جائے۔ انگریزی سے جنوبی ایشیائی زبانوں میں ادبی ترجمے کی صنف پہلے ہی نابوکوف کی شدید لغویت پسندی اور بورخیس کی اصل متون کی فن کارانہ دست درازی کے درمیان ڈولتے ہوئے نقطۂ توازن پر ٹِک چکی ہے ۔ کسی مقامی مصنف کے ساتھ اس کے متن کے ترجمے پر کام کرنا ایک ایسی مسرت بخش ادبی فرحت ہے جیسے صرف مترجم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے مواقع پر نام نہاد ’تنازعاتِ غیریت‘ سلجھ جاتے ہیں اور ہئیت میں بگاڑ ، جملوں کی بناوٹ کےساتھ تجربات، تصوراتی پھیلاؤ اور اس قسم کے متعدد دوسرے مسائل مثبت رجحانات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک ترجمہ فردواحد کی اختراع اور یک جہت اسلوبی فیصلوں کے مرہون منت رہتا ہے۔
یہ تبدیلیاں اس وقت مزید منفرد اور جمالیاتی اعتبار سے مزید منقش ہو جاتی ہیں جب اصل متن کا ثقافتی پس منظر ہدفی زبان کے پس منظر سے زیادہ قریب ہو۔ بورخیسی تناظر میں یہ کسی مترجم کا یوٹوپیا ہوتا ہے جب اصل متن ترجمے کی جانب کھنچتے ہوئے اس سے وفاداری نبھاتا ہے ۔ اصل متن سے انحراف دراصل ایک تخلیقی نقالی بن جاتا ہے۔ متن کےساتھ اس قسم کا منفرد تعامل یعنی ترجمے کی بجائے توضیع کا عمل کئی مشکل اور ترجمے کے عمومی طریقہ ٔ کار سے ہٹ کر کچھ نئی ترجیحات کا تقاضہ کرتا ہے۔ مصنف اور مترجم کی آوازیں ایک دوسرے سے غیرممیز ہونے کے باوجود اپنی پوشیدہ خطِ پرواز رکھتی ہیں۔ جہاں مصنف کی آواز فکری استدلال، کردار نگاری ، کہانی کی بنت کاری اور سماجی و سیاسی قضایا میں سنائی دیتی ہے، مترجم کی آواز لسانی، اسلوبی اور تعبیری معاملات تک محدود رہتی ہے۔ یہاں بھی حتمی اختیار تو مصنف ہی کا ہوتا ہے۔ لیکن ان دو کے علاوہ ایک تیسرا منطقہ بھی ہے جہاں مصنف اور مترجم کے بیچ مکالمہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس ناول کی حد تک اس منطقے کی سیاحت نہایت بصیرت افروز اور قیمتی ثابت ہوئی۔
ترجمے کے تناظر میں ان ترجیحات کے اشارتاً ذکر کے بغیر یہ تبصرہ ادھورا رہے گا۔ وادیٔ سندھ کی تہذیب سے متعلقہ زبانیں ایک ایسا تحقیقی موضوع ہیں جہاں ایک سے زیادہ مفروضے موجود ہیں۔ اہلِ علم عمومی طور پر یہ مانتے ہیں کہ سنسکرت یا عمومی طور پر ہندآریائی قبیل کی زبانوں کے وادیٔ سندھ میں ظہور سے قبل ہڑپائی زبانوں کا سب سے بڑا خاندان دراوڑی زبانوں پر مشتمل تھا۔ حالانکہ جدید یا کلاسیکی براہوی شاید بیانیے کے اس حصے میں شامل مکالمے کے لیے زیادہ بہتر ترجیح ہوتی ، ہم نے خود کو سنسکرتی لہجے تک محدود کیا بلکہ یوں کہیے کہ اسے ہندی ذائقہ عطا کرنے کی کوشش کی۔ تاہم موہنجوداڑو کی بیانیہ قوس میں یہ تیزی اس قدر نہیں کہ زبان پر صرف جدید ہندآریائی ذائقہ ہی محسوس ہو۔ دوسری طرف گندھارا تہذیب کے مناظر کے لیے یہ ایک زیادہ موزوں ترجیح تھی۔ مغل دور اور انیسویں صدی کے لاہور کے مناظر فارسی یاعربی زدہ اردو یا ہمارے دور کے قارئین کے لیے بلیغ اردو لہجے میں ترجمائے گئے ہیں ، سکھ مکالمے روزمرہ کی پنجابی میں ہیں جب کہ نوآبادیاتی دور اور مستقبل کے دور کو سیاق و سباق کے مطابق اردو میں ڈھالا گیا ہے۔
کافی غوروخوض اور مباحثے کے باوجود یہ ترجیحات بہرحال سمجھوتے ہی ہیں جو ترجمے کی صنعت کا عمومی عنصر ہیں۔ باالآخر اصل اور ترجمے کے موازنے اور دونوں کی تہوں میں غواصی پر آمادہ قاری ہی درست فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا وہ کسی جانی پہچانی دنیا میں اصل متن اور ترجمے کے ذریعے دو بالکل مختلف تجربات کا لطف اٹھانے کے قابل ہو سکا یا نہیں۔


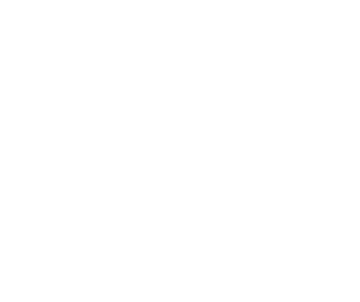
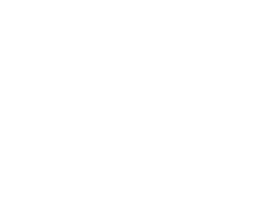



ناول پڑھ لینا چاہئے اب۔