خود سے ایک مکالمہ (خالدہ حسین کی یاد میں) ۔ تحریر: نجیبہ عارف
الف: خالدہ حسین ایک بڑی افسانہ نگار ہیں۔
بے: مگر ایک بڑا افسانہ نگار کون ہوتا ہے؟
الف: بڑا افسانہ نگار وہ ہوتا ہے جو انسانی تجربات کو ، خواہ وہ کیسے ہی معمولی یا غیر اہم کیوں نہ ہوں، ایسے واضح اور بین انداز میں پڑھنے والے کی آنکھوں کے سامنے لے آئے کہ قاری ان تجربات کو اپنی ذات کا حصہ بنتے ہوئے محسوس کر لے اور اس کے نتیجے میں وہی آگہی اور شعور حاصل کر لے جیسا لکھنے والے کو ودیعت ہوا تھا بلکہ اگر توفیق ہو تو اس سے کچھ بڑھ کر ۔
بے: غلط۔ بڑا افسانہ نگار وہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے ، اہم موضوعات پر کہانیاں لکھتا ہے؟ مثلاً عصری حسیت، عالمگیریت، نوآبادیاتی جبر، دہشت گردی، انتہا پسندی، مذہبی تنگ نظری، جمہوریت اور آمریت وغیرہ۔
الف: یہ کس نے کہا؟
بے: سبھی نقادوں نے، ادب کے ماپ تول کا اعشاری نظام مرتب کرنے والوں نے۔
الف: ایسا تو نہیں ہے۔ نقاد اتنے کم کوش تو نہیں ہو سکتے۔
بے: اگر کم کوش نہیں تو انھوں نے خالدہ حسین کو اس کے جیتے جی، نظر انداز کیوں کیے رکھا؟
الف: یہ بھی غلط۔ نقادوں نے خالدہ حسین کو نظر انداز نہیں کیا، وہ خود ہی ادبی دنیا میں جلوہ آرا ہونے سے کتراتی رہیں۔ ورنہ ان کے فن کا اعتراف تو بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے۔ آصف فرخی ان کے معتقد ہیں۔ مرزا اطہر بیگ ان کے مداح ہیں۔ سراج منیر نے تو دہائیوں پہلے ان کی انفرادیت اور عظمت کا اعتراف کیا تھا۔اور اب ان کے جانے کے بعد تو کئی اور لوگ بھی ان کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔
بے: لیکن دبے دبے لفظوں میں یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ ان کے موضوعات محدود ہیں۔ وہ وجودی الجھنوں سے باہر نہیں نکل پاتیں۔ باطن کی دنیا تک محدود رہتی ہیں۔
الف: بد قسمتی سے پچھلے دو تین سو برسوں میں دنیا بھر کا نظام علم و تعلم اس طرح ترتیب دیا جاتا رہا ہے کہ سیاست، حکومت اور بین الاقوامی معیشت کے مسائل کو انسانی فکر کا مرکزی موضوع سمجھ لیا گیا ہے۔ کائنات کو مسخر کرنے کا جنون سروں میں ایسا سمایا ہے کہ انسانی زندگی کی لطافتوں اور انسانی تجربے کی نزاکتوں کے تنوع پر نظر کرنا وقت کا ضیاع معلوم ہونے لگا ہے۔ افادیت پسندی اور عملیت پرستی کے فلسفے نے، زندگی کو قابل مشاہدہ اشیا و کیفیات تک محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ انسان کے وہ تجربات جو اس کی سیر باطن سے متعلق ہیں اور جو اسے تحیرزا انبساط اور اہتزاز سے آشنا کر سکتے ہیں، غیر حقیقی، ناقابل مشاہدہ اور غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ایسا کرنے سے اس نے اپنی پرواز کو وسعت عطا کی ہے اور اپنے وجود کا اثبات کیا ہے، حالانکہ معاملہ اس سے بالکل الٹ ہے۔ انسان نے خود کو تجربات کی ایک لامحدود دنیا سے دورکر لیا ہے، اپنی ذات کو مادے کی کائنات تک محدود کر کے خود کو ایک مختصر سی اقلیم میں سمیٹ لیا ہے اور زندگی کے لامحدود امکانات کا راستہ خود پر اپنے ہاتھوں بند کر لیا ہے۔
بے: مگر خالدہ حسین کا اس بات سے کیا تعلق؟
الف: تعلق یہ ہے کہ ہمارے ہاں تنقید ، بالخصوص فکشن کی تنقید میں ایک عمومی چلن یہ رہا ہے کہ فکشن کو اس کے موضوعات تک محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ عام طور پر کسی افسانے یا ناول کا تجزیہ کرتے ہوئے نقاد گھوم پھر کر بات موضوع یا نفس مضمون تک لے آتے ہیں۔
”اس افسانے میں یہ کہا گیا ہے، یہ بتانے کی کوشش کی گئی ، اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، مصنف دراصل یہ کہنا چاہتا ہے “ ۔ وغیرہ وغیرہ۔
بے: تو اس میں کیا قباحت ہے؟
الف: اس میں یہ قباحت ہے کہ ایک تو نقاد یہ دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ وہ مصنف کے مطمح نظر کو، اس کے شعوری و لاشعوری مقصد ِ تخلیق کو، اس کے ادبی مہیج و محرکات ، یہاں تک کہ اس کی نیت کو بھی، بخوبی سمجھ گیا ہے اور افسانے یا ناول کا موضوع اور اس کے مطالب دراصل وہیں تک محدود ہیں جہاں تک نقاد کی نظر یا ذہن کی حد ِرسائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افسانے یا ناول کو محض ایک پیمانہ، ایک صراحی — بلکہ محض ایک جگ یا گلاس —سمجھ لیا جاتا ہے (پیمانہ اور صراحی تو پھر بھی کچھ خیال انگیز معلوم ہوتے ہیں) جس میں کسی خاص موضوع کا شربت ڈال کر پیش کیا گیا ہو۔ ایسے میں قدرو قیمت اور خوبی و خامی کا تعین صرف اور صرف شربت کے رنگ و خوشبو اور ذائقے و افادیت پر منحصر ہو کر رہ جاتا ہے۔ جگ یا گلاس کا ذکر اگر ہو بھی تو انتہائی معمولی اور سرسری انداز میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ جگ کا سائز یہ ہے، رنگ ایسا ہے اور دیکھنے میں خوش نما معلوم ہوتا ہے یا نہیں۔ اصل اہمیت اور مرکزیت شربت کو حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ جگ، گلاس اور شربت کے مابین رشتے میں ہونی چاہیے۔ آخر جگ اور گلاس کی اس کے سوا اور کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی خاص سیال کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اصل بات تو سیال کی ہے۔ اس کا رنگ کیسا ہے، ذائقہ کیا ہے، تاثیر کیسی اور کتنی ہے اور اسے پی کر پیاس بجھتی ہے یا بڑھتی ہے، معدے کی گرمی کم ہوتی ہے یا نہیں، جگر کو ٹھنڈک پہنچتی ہے یا نہیں، ایک جگ بھر سیال کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ غٹا غٹ پیا جا سکتا ہے یا گھونٹ گھونٹ پینا مفید ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ۔
بے: لیکن جگ اور شربت کا فکشن اور اس کی تنقید سے کیا تعلق ہے؟
الف: ہمارے ہاں فکشن کی تنقید بھی عام طور پر اسی نوعیت کی ہوتی ہے۔ افسانے یا ناول کو محض ایک جگ یا گلاس سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کے موضوع کوشربت۔ لہٰذا عام طور پر تنقیدی مضامین اس نوعیت کے مباحث تک محدود رہتے ہیں کہ موضوع میں آفاقیت ہے یا نہیں؟ انسانیت کی خدمت کا کوئی پہلو (یعنی کوئی ایسا پہلو، جو دور سے انسانیت کی خدمت کرتا نظر آئے) موجود ہے یا نہیں؟ مسئلہ انفرادی ہے یا اجتماعی، غریبوں اور ناداروں کا درد سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا نہیں؟ طبقاتی تقسیم، سامراجی استحصال، معاشرتی جبر کے خلاف آواز بلند کی گئی ہے یا نہیں؟ مولوی، مذہب اور انتہا پسندی کے درمیان رشتہ تلاش کر کے اس کی مذمت کی گئی ہے یا نہیں؟ زندگی کے عقلی اور عملی پہلوؤں کو پیش نظر رکھا گیا ہے یا نہیں؟ کوئی ایسی بات تو نہیں جو عمومی انسانی تجربے اور معمول سے ہٹ کر ہو اور جس میں زندگی کو جست بھر کر اپنی سطح سے آگے نکل جانے کا موقع مل سکے۔
تنقید کی اصطلاح میں بات کریں تو فکشن کی تنقید زیادہ تر ”کیا کہا“ پر مرکوز رہتی ہے اور ”کیسے کہا“ کو مکمل نظر انداز کر دیتی ہے۔ ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ کسی فکشن نگار نے اپنے ناول یا افسانے میں کیا خیال پیش کیا ہے؟ کس موضوع کا انتخاب کیا ہے؟ اس کی فکر کا دائرہ کتنا وسیع یا محدود ہے؟ اس میں اجتماعیت کا رنگ کتنا گہرا ہے اور اس کی حدود کتنی وسیع یا مختصر ہیں؟
بے: تو اس میں کیا غلطی ہے؟ آخر فکشن نگار کوئی بات کہنے کے لیے ہی افسانہ یا ناول لکھتا ہے؟
الف: بالکل ٹھیک۔ کوئی بات کہنا ہی مقصد ہوتا ہے مگر بات کہنے کے لیے وہ فکشن کی صنف کا انتخاب کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محض بات کہنا، پیغام دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کی اصلاح یا تادیب کرنا ، انھیں کوئی سبق سکھانا ہی مقصود ہوتا تو وہ فکشن کا انتخاب کیوں کرتا۔ مضمون یا انشائیہ کیوں نہ لکھ لیتا۔ کالم یا مقالہ ہی قلم بند کر لیتا۔
بے: اس کی وجہ تو بالکل سیدھی سادی ہے۔ مضمون ، کالم یا انشائیے میں وہ اثر نہیں ہوتا جو افسانے یا ناول میں ہوسکتا ہے۔ افسانے یا ناول کی تکنیک کے ذریعے بات کو زیادہ مؤثر انداز میں پہنچایا جا سکتا ہے۔
الف: یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ تکنیک اپنے پیغام کے ابلاغ کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے مگر اس صورت میں تو ادب محض مونٹیسوری کا نصاب بن کر رہ جاتا ہے۔ جس طرح، مونٹیسوری نظام تعلیم میں بچے کو سکھانے پڑھانے کے لیے کھیل کھیل میں تعلیم کا انداز اختیار کیا جاتا ہے اسی طرح گویا ادب بھی ایک آلۂ کار ہے جس کے ذریعے ادیب شعوری طور پر اپنے نظریات اور خیالات کی ترسیل و تبلیغ کرتا ہے۔ اس سے مجھے یاد آیا، کہ کئی برس پہلے ایک محفل میں میں نے مشتاق احمد یوسفی کی کتاب ”آب گم“ پر اپنا مضمون تنقید کے لیے پیش کیا تھا۔ مضمون تنقیدی اصطلاحات کے بجائے تخلیقی انداز میں لکھا گیا تھا۔ اس پر ہونے والے دو تبصرے مجھے ہمیشہ یاد رہتےہیں۔ پہلا یہ کہ مضمون کسی کام کا نہیں کیوں کہ یہ یوسفی صاحب کے بارے میں ہے جو نہ صرف اشرافیہ کے نمائندے اور طبقاتی امتیاز کے قائل ہیں، بلکہ شاعروں کے بھی خلاف ہیں اور اس کتاب میں انھوں نے شاعروں کی تضحیک کی ہے۔ دوسرا یہ کہ نثر بہت خوب صورت ہے مگر خامی یہ ہے کہ ایسی نثر میں لکھے گئے مضمون کا خلاصہ نہیں بنایا جا سکتا۔
بے: ہا ہا ہا۔۔۔ دوسرے اعتراض کا حل تو بڑا آسان ہے۔ آئندہ ہر تخلیقی مضمون کا خلاصہ بھی اس کے ساتھ چسپاں کر دیا جائے۔ رہی بات یوسفی صاحب کی تو۔۔۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ بے چارے یوسفی صاحب!۔ ۔۔ لیکن یہ بات کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ ادب کو محض ایک آلۂ کار سمجھنا۔۔ ۔کچھ کھٹک سا رہا ہے۔ لیکن ادب اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟تخلیقی نثر لکھنا ضروری ہے کیا؟
الف: اصل بات ادبیت پیدا کرنے کی ہے۔ ادب خیالات، کیفیات اور انسانی تجربات کا محض بیان نہیں ہوتا بلکہ ان کی تخلیق کا مرکز بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ پہلو نہ ہو تو اس تحریر کو ادب میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ادب ایک سرچشمہ ہے جس سے انسانی تجربات کے نت نئے رنگ اور ان رنگوں کے انوکھے شیڈ قوس قزح کی طرح پھوٹتے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قوس قزح کے سات رنگ ہوتے ہیں۔ مگر ان سات رنگوں کو اگر پرزم سے گزار کر دیکھا جائے یا ان کے سپیکٹرم کا بغور معائنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر رنگ دوسرے رنگ میں ڈھلنے سے پہلے لامحدود شیڈز سے گزرتا ہے۔ ایسے شیڈ ، جن کا کوئی نام نہیں ہوتا، جنھیں کسی خاص مقام پر تلاش نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ شیڈ نہ صرف موجود ہوتے ہیں بلکہ قوس قزح کا لازمی اور ناگزیر جزو بھی بنتے ہیں۔ ان کے بغیر قوس قزح کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے۔اسی طرح زندگی کو گنے چنے، محدود اور عام سطح کے قابل فہم موضوعات یا تجربات تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ہر شخص زندگی میں ایسے لاتعداد ذہنی ، جذباتی اور معاشرتی تجربات سے گزرتا ہے جن سے شاید کوئی اور نہ گزرتا ہو، یا اگر گزرتا ہو تو رک کر انھیں پہچاننے اور شناخت کرنے کا ہنر نہ رکھتا ہو اور اگر پہچانتا اور شناخت کر بھی لیتا ہو تو انھیں بیان کرنے کے پل صراط سے گزرنا اس کے ممکن نہ ہو۔ فکشن نگار ان انوکھے تجربات کو بھی اپنے افسانے یا ناول کا موضوع بنا سکتا ہے اور بناتا رہا ہے۔
بے: اس بات کا فکشن کی تنقید سے کیا تعلق ہے؟
الف: دو باتیں ہیں؛ ایک تو یہ کہ فکشن نگار کے لیے لازم نہیں کہ وہ اپنے موضوعات کو سات رنگوں تک محدود رکھے۔ یعنی انھی مروج فکری سانچوں اور ڈھلے ڈھلائے موضوعاتی پیکروں کو پیش کرے جو اس کے معاصر ادب یا ادبی تاریخ کے دھاروں میں واضح شناخت رکھتے ہوں، جنھیں پہچاننا اور تسلیم کرنا آسان ہو کیوں کہ ان پر طبع آزمائی کی جاتی رہی ہو، اور جو کسی خاص نظری یا فکری تحریک کے لیے معاون ثابت ہوتے ہوں یا کسی مروجہ اخلاقی، معاشرتی یا سماجی نقطۂ نظر کا اثبات کرتے ہوں۔ فکشن نگار کا موضوع کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اہم مسئلہ، یا بالکل غیر اہم لگنے والا نکتہ، کوئی مانوس اور معلوم خیال یا بالکل نیا، اجنبی اور انوکھا احساس، کوئی اجتماعی یا معاشرتی احساس یا کوئی بالکل نجی، منفرد اور ذاتی واردات۔ ان نامانوس اور کم آشنا موضوعات کا انتخاب کرنے سے اس کے فکشن کی قدر وقیمت کم نہیں ہو سکتی بلکہ اگر وہ اپنے فن میں کامل ہو تو بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے موضوع کی بنیاد پر کسی فکشن نگار کا بڑا یا چھوٹا ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ قابلِ غور چیز وہ فن کاری، وہ ہنر ہے جو کسی بھی چھوٹے یا بڑے موضوع کو بیان کرنےکے لیے آزمایا جاتا ہے۔ موضوع کی اہمیت کو کم کیے بغیر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی اپنے فن میں کامل نہ ہو تو بڑے سے بڑا (سمجھا جانے والا) موضوع بھی نرا بے اثر اور پھسپھسا فکشن پیدا کر سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی موضوع کو بیان کرنے کے لیے مصنف نے کیسا اور کون کون سا حربہ آزمایا ہے۔ یعنی یہ کہ جو کچھ بھی وہ کہنا چاہتا ہے، اسے کہنے کا کیسا طریقہ اختیار کیا ہے؟ کیا اس کی بات پڑھنے سننے والے پر اثرا نداز ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی تحریر کوئی جمال آفریں واردات پیدا کرنےکی اہل ہے؟ کیا وہ قاری سے ہم کلام ہونے کی اہلیت رکھتی ہے؟ کیا قاری کے دل و دماغ پر وہ تاثر یا معنی مرتسم کرنے میں کامیاب ہے جو لکھنے والا پیدا کرنا چاہتا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا وہ تحریر ایسے امکانات کی طرف لے اڑنے کی محرک بن سکتی ہے جو اس سے پہلے قاری— اور شاید خود لکھاری —کے حیطۂ شعور میں بھی نہ آئے ہوں۔ اور اگر ایسا ہوا ہے تو آخر مصنف نے یہ اثر کس طرح پیدا کیا ہے؟ الفاظ کے چناؤ سے، علامات اور استعاراتی طرزِ اظہار سے، پلاٹ میں واقعات کے الٹ پھیر سے، راوی کے چناؤ سے، زمانی و مکانی جست سے، کچھ باتوں کو پیش منظر اور کچھ کو پس منظر میں رکھ کے، کسی خاص عہد، کسی خاص لمحے، کسی خاص مقام کو منتخب کرکے ، کرداروں کے مخصوص افعال کو نمایاں کر کے اور باقی تمام افعال کو نظر انداز کر کے، مصنف شعوری یا غیر شعوری طور پر زندگی کا ایک امکان تخلیق کرتا ہے۔ اس امکان کی تخلیق سے زندگی کی حدود ، کم از کم ذہنی سطح پر، پھیل جاتی ہیں، وسیع ہو جاتی ہیں اور ایک نئے تجربے سے ہم کنار کرتی ہیں۔ نقاد کا کام یہ ہے کہ وہ ان حربوں کو تلاش کرے جن کی مدد سے کوئی خاص فن پارہ ایک مخصوص اثر پیدا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ نقاد کی یہ کوشش سو فی صد درست اور مکمل ہو ۔ بعض اوقات تو نقاد اپنی ذہنی اپج اور فکری پروازکی مدد سے اصل بات میں کچھ اضافہ بھی کر دیتا ہے ۔ یہ کمی بیشی فطری امر ہے۔ تخلیق کی طرح تنقید کا بھی معروضی اور دو جمع دو جیسی ریاضیاتی صداقت کا حامل ہونا ناممکن ہے۔ تنقید کا معروض ایک ایسی شے ہے جو سیال کیفیات سے تعلق رکھتی ہے اور مختلف اوقات اور صورت حال میں معانی کی مختلف تہیں اور سطحیں واضح کر سکتی ہے۔ اس لیے تنقید کو ایسا پیمانہ تصور کرنا درست نہیں جس میں ڈال کر ہر قسم کی تخلیق کا وزن کیا جا سکے اور اس کی قدر و قیمت کا فیصلہ صادر کیا جا سکے۔ تنقید محض ایک اشارہ ہے اور نقاد کی فہم و بصیرت کی سمت اور حد تک محدود ہے۔
بے: جناب عالی! دو ہزار چھے سو پینتالیس لفظ ہو گئے ہیں اور ابھی تک خالدہ حسین کی بات نہیں چھڑی۔
الف: یہ دو ہزار چھے سو پینتالیس لفظ یہ بتاتے ہیں کہ خالدہ حسین کے موضوعات کو محدود، کم مایہ یا غیر اہم سمجھنا نادانی ہے۔ اگر انھوں نے عصری حسیت، عالمگیریت، نوآبادیاتی جبر، دہشت گردی، انتہا پسندی، مذہبی تنگ نظری، جمہوریت اور آمریت وغیرہ پر براہ راست افسانے نہیں بھی لکھے تو کوئی بات نہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ یہ سارے پہلو اُن کے افسانوں میں کہیں راست اور کہیں ترچھے انداز میں بیان ہو گئے ہیں۔ بلکہ ان میں سے کچھ تو بہت واضح طور پر ان کے افسانوں میں جھلکتے ہیں۔ ان پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ان افسانوں کو دیکھتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتاہے کہ وہ ایک شدید داخلیت اور وجودی واردات کا عکس لیے ہوئے ہیں۔ ان کے پہلے مجموعے پہچان کے افسانے ہی دیکھیے۔ ان میں مجموعی طور پر ایک فرد کی ان داخلی، نفسی وارداتوں کا بیان ملتا ہے جن کا بظاہر کوئی خارجی محرک نہیں۔ زیادہ تر افسانے ماضی کے صیغے میں لکھے گئے ہیں۔ ایک ایسا ماضی جو گزر چکا ہے مگر کیا گزر جانے کے بعد ماضی بے اثر اور بے نتیجہ ہوجاتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ مصنفہ نے کچھ کہا تو نہیں ، لیکن قاری یہ سمجھ لیتا ہے کہ ماضی کے یہ تجربات فرد کی شخصیت پر کس طرح اپنی چھاپ چھوڑ گئے ہیں۔ فرد جو ان افسانوں کا مرکزی کردار ہے اور کردار بھی مؤنث۔ یعنی ایک عورت جو اس زمانے کے تجربات اور احساسات کو دہراتی ہے جب وہ ابھی بچی تھی اور دنیا اور اپنے گردو پیش کو پہچاننے اور ان سے آشنا ہونے کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ اس مرحلے پر اس کی بصارت کیسے بصیرت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ وہ اپنے گردوپیش کی اشیا کو کس طرح دیکھ اور سمجھ رہی تھی اور کس طرح خود اپنی ذات سے جدا ہو کر خود کو اپنے ماحول میں چلتا پھرتا اور حرکت کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک عجیب و غریب تجربہ ہے۔ اگر کسی صوفی نے بیان کیا ہوتا تو اسے کوئی روحانی کرشمہ سمجھا جاتا مگر یہ تو ایک نوخیز بچی کا تجربہ ہے جو اپنی ذات سے الگ ہو کر ، اس کو اپنے ماحول کا جزو بنا دیکھتی ہے اور اس کا بیان بھی کرتی ہے۔ اس بیان میں وہ ماحول کے ان اجزا کا ذکر کرتی ہے جو عام طور پر توجہ سے محروم رہتے ہیں۔ یہ اجزا اس کے تمام حواس کو تحریک دیتے ہیں۔ ذائقہ، شامہ، لامسہ، سامعہ اور باصرہ، وہ ہر ذریعے سے اپنے ارد گرد کو دیکھتی اور پہچاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی قوت متخیلہ بھی مسلسل مصروف رہتی ہے۔ اسے ساکت چیزوں میں حرکت دکھائی دیتی ہے، بے جان اشیا کی آواز سنائی دیتی ہے، غیر موجود اجسام نظر آنے لگتے ہیں اور وہ موہوم ہیولوں کا لمس محسوس کرتی ہے۔ اس کے یہ تجربات کسی بیماری کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کے حواس کی شدت کا نتیجہ ہیں۔ وہ اپنی مختصر سی دنیا کو اس شدت سے دیکھتی، سوچتی اور محسوس کرتی ہے کہ اسے اس دنیا کے وہ اجزا بھی دکھائی دینے لگتے ہیں جوکسی اور کو دکھائی نہیں دیتے۔ انسانی رشتے اور آپسی تعلق، آوازیں، لمس، یہ سب اس کے ادراک پر ایسا نقش چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنے گردوپیش کی دنیا اور اس میں بے نیازی سے جینے والے لوگوں کے لیے اجنبی ہو جا تی ہے۔ اسے ایسی تنہائی کا احساس ہوتا ہے جسے کسی اور کو سمجھانا ممکن نہیں۔ یہ تنہائی انسان کا ایسا باطنی تجربہ ہے جسے اس سے گزر کر ہی پہچانا جا سکتا ہے۔ ”گنگ شہزادی “ ، ”شہر پناہ “ ، ”منّی “ ، ”آخری سمت “ ، سب ایسی کہانیاں ہیں جن میں شعور اور بلوغت کی سرحد کو پہنچنے والی لڑکی کی نفسی وارداتوں کا بیان ہے۔ ان کہانیوں میں واقعات بھی ہیں مگر واقعات کا سلسلہ مربوط اور ایک دوسرے سے جڑا ہوا نہیں، کٹا ہوا، اکھڑا اکھڑا اور غیر مسلسل سا ہے۔ واقعات صرف وہی ہیں جو ان کیفیات کو اجاگر کرتے ہیں۔ مقصد کسی قصے کا بیان نہیں، اس ذہنی منظر نامے کا اظہار ہے جو اس لڑکی پر منکشف ہوتا ہے اور وہ خود اس پر حیران ہوتی ہے۔ اس لڑکی کے کے علاوہ دیگر کردار انتہائی ضمنی اور مفعول نوعیت کے ہیں۔ وہ کہیں کہیں اس ذہنی عمل کو مہمیز دیینے یا اس کا شکار بننے کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ ان کی اپنی کوئی ذاتی اہمیت نہیں۔ بیانیے کامجموعی تاثر انتہائی اداسی کا ہے۔ حالانکہ بظاہر اداسی کی کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آتی۔ دراصل اداسی صرف احساس تنہائی سے پیدا ہوتی ہے جو دوسروں سے مختلف ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کے اندر پیدا ہوتا رہتا ہے اور وہ اپنے اور دیگر تمام کرداروں، اشیا اور پوری دنیا کے درمیان ایک ناقابل عبور فاصلہ دیکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیانیے میں گہرا فلسفیانہ رنگ ہے۔ یہ فلسفیانہ رنگ ایک نوعمر بچی کے تجربے سے بڑھ کر معلوم ہوتا ہے لیکن ناقابل یقین اس لیے نہیں لگتا کیوں کہ مصنفہ نے اس میں استعجاب ، تحیر اور استفسار کا رنگ بھر دیا ہے۔ افسانوں میں در آنے والے فلسفیانہ بیانات قطعی اور حتمی ہونے کا تاثر نہیں دیتے بلکہ تجربے سے حاصل ہونے والی حکمت کا اندازلیے ہوئے ہیں یا پھر دانائی سے پہلی پہلی آشنائی کے تحیر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ چند مثالیں دیکھیے:
اب مثلاً یہ پیار کا مسئلہ بھی پہاڑ بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جو انسان شدت سے اچھا لگتا ہے، اسے دیکھ کر دکھ سا کیوں ہوتا ہے، دل ڈوبنے سا کیوں لگتا ہے؟
اسے خود بھی احساس تھا کہ جان کا اتنا عزیز رکھنا بڑی گھٹیا سی بات ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اسے جان اتنی پیاری نہ تھی، دراصل اسے منظر خوف زدہ کرتے تھے، حادثے نہیں؛ کیوں کہ منظر تو وجود پانے سے پہلے ہی اس کے ذہن میں موجود ہوتے اور اسے معلوم ہوتا کہ جب وہ باہر کی دنیا میں سمانے آن کھڑے ہوں گے تو کتنے بھیانک ہوں گے۔
اس کو یقین سا ہو گیا کہ جب وہ کسی روز آئینے کے سامنے رکے گی تو ایک کی بجائے اس کے دو وجود ساتھ ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ یا یہ کہ چلتے چلتے کسی روز وہ اپنے آپ سے ٹکرا جائے گی اور اسے خود اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا ہوگا۔
ان افسانوں میں بعض اوقات تو زمان و مکاں کی سرحدیں مٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور اس نوجوان خاتون کی ذہنی رسائی اوربراقی پر حیرت ہوتی ہے۔
فضا میں مابعد الطبیعیاتی رنگ پیدا ہونے لگتا۔ اس کے ذہن میں اترتی گرد کے پیچھے لوح محفوظ کے عجیب عجیب ہیولے ابھرنے لگتے۔۔۔ اور بے شمار نبضیں اس کے جسم میں دھڑکنے لگتیں۔ وقت کا احساس اس کا دل جکڑ لیتا۔ میں پل پل بڑی ہورہی ہوں۔ ہر حرکت، ہر قدم وقت ہے۔ بازو چلانا، چلنا ، ہنسنا سب زندگی کے لمحے ہیں۔ اس کا ذہن گول گول دائروں پر گیند بنا گھومتا رہتا ہے۔
یہ سب کچھ بیان کرنے والی ظاہر ہے کہ خود بچی نہیں ہے بلکہ وہ فرد ہے جو ان تمام مرحلوں سے گزر کر اب اپنے اس گزشتہ تحیر کی بازیافت کرتا ہے۔ فرد بھی ایک عورت۔ اس کا ایسی عورت ہونا، جس کا ذہنی عمل اپنے ارد گرد موجود سب مردوں اور عورتوں سے مختلف اور تیز ہو، محض ایک انفرادی تجربہ نہیں ہے بلکہ ایک عصری تجربہ ہے پانچ چھے سوقبل مسیح کی عورت شاید اس تجربے سے نہیں گزر سکتی تھی۔نہ صرف یہ، بلکہ اس کے ہم عصروں میں بھی دیگر مرد و زن اس تجربے سے تقریباً محروم ہیں۔ اگر تجربہ ہو بھی تو اس کے ایسے تصویری بیان کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہ ایسی عورت بننے کے لیے اس پورے تاریخی اور تہذیبی ارتقا کی محتاج ہے جس سے گزرنے کے بعد وہ یہاں تک پہنچی ہے کہ اپنے تجربے کو زبان دے سکے۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خالدہ حسین کے افسانے عصری حسیت سے محروم ہیں۔
بے: یہ سب تو ایک فرد کی نفسی اور ذہنی وارداتوں کا بیان ہے۔ انسان اپنے داخل میں جن کیفیات و تجربات سے گزرتا ہے وہ بڑے انوکھے اور نادر ہوتے ہیں۔ مگر انسان کی ایک خارجی زندگی بھی تو ہوتی ہے۔ معاشرے، خاندان اور بنی نوع انسان کے فرد کی حیثیت سے دوسرے انسانوں سے اس کا ربط، اس ربط میں پڑنے والے رخنے، دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش اور اس کوشش کی راہ میں آنے والی رکاوٹیں، جو ایک طرح کا تصادم یا ٹکراؤ پیدا کرتی ہیں اور اس تصادم کے نتیجے میں واقعات و حادثات جنم لیتے ہیں۔ کیا ان واقعات و حادثات کو نظر انداز کر کے اعلیٰ ادب تخلیق کیا جا سکتا ہے؟
الف: یہ واقعات و حادثات نظر انداز ہو ہی نہیں سکتے کیوں کہ انسان جو کچھ بھی بنتا، کرتا یا سہتا ہے وہ اسی تصادم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تصادم کو براہ راست بطور تصادم بیان کیا جائے یا نہ کیاجائے مگر جو کچھ اس کے ساتھ بیتتا ہے وہ اس کی انفرادی اور یکہ و تنہا ذات کا زائیدہ نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ بعض لکھنے والے انداز ایسا اختیار کر لیتے ہیں کہ تصادم دکھائی نہیں دیتا، صرف اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر کہانی ”سواری “ کو لیجیے۔ یہ فرد کی نہیں، شہر کی کہانی ہے۔ ایسے شہر کی، جس میں خوف اور گھٹن بڑھتی جاتی ہے تو تفریحی تقریبات میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ جہاں لوگ قرض لے کر واپس نہیں کرتے اور قرض دینے والے سے پرخاش رکھ لیتے ہیں۔ جہاں سورج دریا کے پانی میں نہیں مٹی میں ڈوبتا ہے کیوں کہ پانی خشک ہوچکا ہے اور ایک دلدل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس دریا کا ایک نام بھی ہے، راوی۔ راوی جو ایک حقیقی دریاہے اور جس کے کنارے ایک بڑا شہر آباد ہے، جس کا نام لاہور ہے مگر افسانے میں شہر کا نام نہیں ہے صرف دریا کا نام ہے۔ اس شہر پر نازل ہونے والی آفات، افق پر تنی ہوئی خون کی سرخ چادریں اور پیٹ میں مروڑ پیدا کرنے والی مہک، جس کے بارے میں علم نہیں کہ وہ خوشبو ہے یا بد بو، شہر والوں سے پہلے مضافات والوں کو محسوس ہوجاتی ہے۔ یہ سب واقعات اور مرکزی کردار کا طرز عمل جو ایک متوسط طبقے کا نوکری پیشہ ، بال بچے دار فرد ہے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچاتے۔ بس ایک نامعلوم خوف، دہشت اوراضطراب پیدا کرتے ہیں۔ اس ساری دہشت کا ماخذ ایک ہی ہے۔ ایٹمی تجربات جو دور کسی اور ملک میں ہو رہے ہیں اور کرہ ٔارض کی فضا کو مسموم بنا رہے ہیں۔ اب معاملہ شہر سے نکل کر پورے کرہ ٔارض تک پھیل جاتا ہے اور شہر پوری دنیا کی علامت بن جاتا ہے۔ دنیا ، جو اپنی تباہی کے اصل سبب سے بے خبر ہے یا بے نیاز ہے، اور اس کے نتائج کا شکار ہو رہی ہے۔ فطرت کے اشارے سمجھنے سے منکر ہے اور خود کو تفریحات میں غرق کر کے چشم پوشی کو ترجیح دیے بیٹھی ہے۔ اب بظاہر تو یہ ایک فرد کے کرب و خوف کی کہانی ہے لیکن اس کہانی کا دائرہ پورے کرۂ ارض کو محیط ہوگیا ہے۔ فن کاری یہ ہے کہ کہیں بھی براہ راست بیانیہ استعمال نہیں کیا گیا۔ فضا بندی ایسی کی گئی ہے کہ ایک مخصوص واقعے کے ذریعے، جو ایک خاص دریا کے کنارے آباد شہر میں وقوع پذیر ہو رہا ہے، ایک عالمگیر المیے کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔
بے: وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے موضوعات کا کینوس وسیع تو ضرور ہوتا ہے۔ وہ نوجوان لڑکی جب ایک باشعور خاتون کا روپ دھارتی ہے اور ایک پیشے سے وابستہ ہوتی ہے، بیوی اور ماں بنتی ہے اور گھریلو اور پیشہ ورانہ زندگی کے درمیان معلق ہوتی ہے تو اس کے تحیر اور اضطراب میں جو اضافہ ہوتا ہے ان کا بیان بڑی وضاحت سے ملتا ہے۔ ایک عورت جو تخلیقی اضطراب میں سرتاپا گندھی ہوئی ہے، اپنے ساتھیوں اور ہم کاروں سے برابری کی سطح کا رشتہ جوڑنے میں ناکام رہتی ہے کیوں کہ وہ زندگی کو اس سطحی انداز میں دیکھنے اور گزارنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جس انداز میں عام طور پر لوگ جیتے ہیں۔ بیوی کی حیثیت سے وہ اپنے شریک حیات کی ان توقعات پر پوری اترنے سے قاصر نظر آتی ہے جو روزمرہ کے معمولات سے متعلق ہیں ۔ اسے اپنے سر کے اندر موجود پاؤنڈ بھر سرمئی مادے اور اس کی کارگزاری کا شدت سے احساس ہے۔ وہ اس کے بارے میں سوچتی اور اس کا تجزیہ کرنے کی عاد ت میں مبتلا ہے۔ اسے وہ باتیں پریشان کرتی ہیں جو دوسروں کو محسوس تک نہیں ہوتیں۔ وہ زندگی کو محض وقت کی لکیر کا ایک معین فاصلہ نہیں سمجھتی بلکہ اس فاصلے کو کم و بیش کرنے والے عناصر کو دیکھتی اور محسوس کرتی ہے۔ وہ معمول کی اشیا اور سطحی باتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتی۔
الف: اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خصوصیت ایسی ہے کہ جو شروع سے لے کر آخر تک ان کے افسانوں میں نظر آتی ہے اور وہ ہے ثنویت۔ دہرا پن۔ اشیا اوراجسام اور اشخاص کا ایک نہ ہونا۔ بلکہ خود اپنے وجود کا بھی عکس دکھا ئی دیتا ہے جو وجود کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور اس پریشانی میں مبتلا رکھتا ہے کہ دونوں میں سے اصلی وجود کون سا ہے۔ اسی طرح بعض افسانوں میں وجود دو حصوں میں تقسیم ہوتا نظر آتا ہے۔ مثلاً افسانہ ”آدھی عورت “ کے پہلے چند جملے دیکھیے:
ایک صبح جب وہ جاگی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی داہنی آنکھ، باہنی آنکھ سے الگ دیکھتی ہے اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے الگ ہے اور ان کا باہمی رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ اور ان چاروں نے باہم کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تب وہ اپنے اس آدھے پن پر بہت پریشان ہوئی۔
اور آخری اقتباس کے چند جملے دیکھیے:
سب سے آگے تو وہ ہے جو وقت کی گرفت سے باہر ہے اور وقت کی گرفت ہم پر سب سے زیادہ سخت ہے۔ اسی لیے ہم اس قدر مضحکہ خیز حد تک المناک ہیں کہ خود ہم پر ہماری ایک آنکھ روتی اور دوسری ہنستی ہے۔ آؤ ہم اس میک اپ کو دھو کر اپنے مرجھائے چہروں کو دیکھیں اور رنجیدہ نہ ہوں اور ”اخبار خواتین“ سے اپنا رشتہ جوڑیں کہ ہم دوسرے درجے کی جنس ہیں اور اس پر بھی ہم رنجیدہ نہ ہوں۔
لیجیے بات کہاں سے نکلی اور کہاں جا نکلی، یہ تو کچھ فیمینزم کا اثر لگتا ہے۔ حالانکہ وہ ہمیشہ اپنے فیمی نسٹ ہونے کی تردید کرتی رہیں ۔ اس کے باوجود ان کے افسانوں میں عورت ہونے کا دباؤ اور بوجھ نظر آتا ہے۔ وہی بوجھ جو یاسمین حمید کے بقول، ہر عورت، اپنی تمام تر آزادی اور آسانی کے باوجود ازل سے محسوس کرتی آئی ہے۔ خالدہ حسین کی تحریریں بھی اس بوجھ سے چٹختی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ”واشنگ مشین“، ”مکڑی“، ”الاؤ“ ، یہ سب افسانے اسی بوجھ کے احساس سے لدے ہوئے ہیں۔ مگر وہ اس بوجھ کو براہ راست بیان نہیں کرتیں۔ یوں ہی باتوں ہی باتوں میں، خود کلامی کرتے ہوئے، کبھی اپنے کسی کام کا جواز پیش کرتے ہوئے، کبھی اپنی کسی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ احساس دلاتی ہیں کہ عورت ہونے کا دباؤ کیسے ان کے وجود کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑے ہوئے ہے۔
بے: دہشت گردی، انتہاپسندی اور ظلم و جبر کے بارے میں بھی تو خالدہ حسین نے افسانے لکھے ہیں۔
الف: لکھے تو ہیں مگر انھیں پڑھ کر یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کسی خاص نقطۂ نظر کی تبلیغ یا کوئی سبق دینے کے لیے لکھے گئے ہیں۔ ان میں بھی انسانی ذات کےٹوٹنے بکھرنے کے منظر دکھائی دیتے ہیں اور یہ احساس ہوتا ہے کہ سیاست، نظریات اور مفادات کی جنگ میں انسانی جذبات کس طرح مجروح ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک افسانہ ”ابن آدم“ عام طور پر اس حوالے سے اکثر زیر بحث آتا ہے۔ یہ تین ایسے نوجوانوں کی کہانی ہے جو اپنے وطن کی آزادی کے لیے دہشت گرد بن جاتے ہیں۔ وہ شہر میں دھماکہ کرنے کا پروگرام بناتے ہیں لیکن پکڑے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو پروفیسر کا بیٹا ہے، بزدل نکلتا ہے اور مخبر بن جاتا ہے۔ اپنے ہی دوست کا مخبر۔ کیوں کہ زندگی اسے بہت عزیز اور قیمتی لگتی ہے اور درد اور تکلیف کو سہارنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس کی ساری تربیت ہی ایسی ہوتی ہے جیسی عام طور پر صرف ذہنی سطح پر جینے والوں کی ہوتی ہے، جو زندگی کے عریاں اور تیز دھار حقائق کے مقابلے میں بالکل بودے نکلتے ہیں۔ پروفیسر کا بیٹا ہونا بہت معنی خیز پہلو ہے۔ دوسرا اپنی محبوبہ سمیت ڈٹا رہتا ہے مگر دھماکے میں محبوبہ کے برخلاف بچ نکلتا ہے اور گرفتار ہوجاتا ہے۔ پکڑنے والے اس کے اندر سے انسان ہونے کا احساس، تکریم ذات کا پندار توڑنا چاہتے ہیں اور اسے کتے کی طرح چلنے اور بھونکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آدمیت کا شرف چھین لینا چاہتے ہیں۔ یہی کہانی کا مرکزی نکتہ بھی معلوم ہوتا ہے مگر اس کے اندر اور بھی کئی پہلو توجہ طلب ہیں۔ کوئی شخص اپنی جان لینے پر کیوں کر آمادہ ہو جاتا ہے؟ وہ کیا عناصر ہیں جو انسان کو اپنی زندگی قربان کر دینے پر اکساتے ہیں اور وہ کون سے پہلو ہیں جو اپنی جان کے تحفظ کے لیے اپنی عزیز از جان ہستیوں کی قربانی دینے سے بھی نہیں چوکتے۔ یہ دو متضاد انسانی رویے ایک اور نوعیت کا المیہ پیدا کرتے ہیں جو دہشت گردی کے موضوع سے کہیں بڑا ہے۔
لیکن سچ پوچھیں تو مجھے اس موضوع پر ان کاایک اور افسانہ بے حد پسند ہے جو ان کی آخری کتاب ”جینے کی پابندی“ میں ”جان من و جانِ شما“ کے عنوان سے شامل ہے۔ یہ ایک ایسی ماں کے درد کا بیان ہے جس کا ایک بیٹا جہادیوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور دہشت گرد حملوں میں ملوث ہے ۔ وہ مسلکی انتہا پسندی کا شکار ہے اور ماں کو بھی اس کے مختلف مسلک سے تعلق رکھنے کے باعث واجب القتل سمجھتا ہے لیکن ماں اس سے محبت کرنے پر مجبور ہے۔ اس کادوسرا بیٹا فوج میں افسر ہے اور ان حملوں کو روکنے کے لیے آپریشن راہ راست کا حصہ بنتا ہے۔ آپریشن پر جانے سے پہلے وہ ماں سے اجازت لینے آتا ہے۔ ماں جانتی ہے کہ اس کا ہدف کون ہے لیکن وہ اجازت دے دیتی ہے ۔ کہانی کی بنت ماں اور اس کی پرانی سہیلی کی ملاقات پر مشتمل ہے۔ یہی سہیلی کہانی کی راوی ہے جس کے سامنے ماں کی بچپن سے لے کر جوانی تک کی پوری کہانی کھلی پڑی ہے اور جو ایک دوست کی طرح اس کے اندر کا کرب سمجھ سکتی ہے۔ ہم اس ماں کو اسی سہیلی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک دوست کی نظر سے جو درد آشنا ہے۔ وہ ایک ایسی ماں ہے جس کے دل و جگر کے ٹکڑے ہو چکے ہیں؛ کس کو سنبھالے اور کس کو فنا ہو جانے دے۔ اگرچہ وہ فیصلہ کر لیتی ہے لیکن اس کا کرب بیان سے باہر ہے جو اس کی خاموشی سے عیاں ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ماں ہماری قوم کی تجسیم ہے۔ اس قوم کی تجسیم جس کے اپنے ہی بیٹے مارنے والے لشکر میں بھی ہیں اور مرنے والے گروہ میں بھی۔ دونوں طرف سے زخم کھاتی ہوئی ماں۔ لہو لہو ہوتی قوم۔ ہماری قوم۔۔۔ دہشت گردی ایک بڑا موضوع ہے مگر اس ماں کی کیفیت، اس کے رنج و محن کا بیان۔۔۔۔ اس کی ٹوٹ پھوٹ ، اس کا زخم زخم وجود۔ مصنفہ نے نہ تو کہیں ترحم آمیز انداز اختیار کیا ہے نہ کوئی حکم لگایا ہے، نہ فیصلہ صادر کیا ہے، بس ایک ٹوٹی بکھری ماں کی چلتی پھرتی تصویر دکھا دی ہے۔ سیاست کے کھیل میں مہرے بننے والے انسانوں کی ماؤں کی تصویر۔ سیاسی مسائل تو حل بھی ہو جاتے ہیں لیکن ماں کی اجڑی ہوئی کوکھ کبھی نہیں بھرتی۔
بے: مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے ایک اور افسانے کا بھی بہت ذکر کیا جاتاہے۔ ”دادی آج چھٹی پر ہیں“؛ جس کا پہلا فقرہ ہی لرزا دیتا ہے: ”دادی دوزخ میں جائیں گی۔“
الف: مگر دادی کے بارے میں یہ کہانی دراصل پوتی سناتی ہے۔ یہ ایک ایسی بچی کی خود کلامی ہے جو متضاد فکری رویوں کے درمیان پلی بڑھی ہے اور اس کا ننھا سا ذہن ان تضادات کی الجھنوں کو سلجھانے سے قاصر ہے۔ ایک طرف انتہا پسند والدین کی تربیت ہے جو مذہبی اور مسلکی انتہا پسندی کا شکار ہیں، جن کے خیال میں زیادہ ہنسنا شیطانی کام ہے، موسیقی حرام ہے اور شعر اور کہانیاں لکھنا بہت بڑا گناہ۔ اور دوسری طرف دادی کی وسیع المشربی ہے جو کتابیں لکھتی ہے، موسیقی سنتی ہے اور کھلی ہوا میں سانس لینے کی مشتاق ہے۔ وہ پوتی کو اس کے ماں باپ کی نظریاتی شدت سے نہیں بچا سکتی تو اسے ایک دن کی چھٹی پر گھمانے لے جاتی ہے تاکہ اسے کم از کم ایک دن زندگی کے حقیقی لمس سے آشنا کر سکے۔ دادی مر جاتی ہے اور پوتی سوچتی ہے کہ کیا واقعی وہ دوزخ میں جائیں گی جیسا کہ اس کے ماما بابا کو خدشہ تھا۔ یہ ایک ایسے معاشرے کا نوحہ ہے جہاں بیٹے ماؤں کے مشرب ترک کر دیتے ہیں اور ایسی ذہنی دھلائی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ محترم اور عزیز ترین رشتے بھی ان ٹھونسے ہوئے نظریات کے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں۔ کہانی کی راوی ایک تیسری نسل ہے جو ان دونوں نسلوں کا ملغوبہ ہے۔ ایسی بچی جس کا ذہن انتشار اور بے یقینی کا شکار ہے اور جو دادی سے محبت کرنے کے باوجود یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا دادی دوزخ میں جائیں گی؟معاشرے میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کئی شکلیں اختیار کرتی ہے لیکن جو شکل بھی اختیار کرے، اس کا نشانہ بالآخر ماؤں کے دل بنتے ہیں۔ ماں کا دل جو انسانیت، دل سوزی اور ترحم و محبت کا سرچشمہ ہوتا ہے۔
بے: اور ان کا سب سے اچھا افسانہ؟
الف: سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان کے اکثر و بیشتر بلکہ کم و بیش سبھی افسانے بے حد پسند ہیں ۔ ہر افسانے میں ایسی شدت احساس، ایسی نیزے کی انی جیسی چبھتی ہوئی کیفیت ہوتی ہے جو دل کے اندر کہیں پیوست ہو جاتی ہے اور کسی ایسے احساس کو روشن کر دیتی ہے جو پہلے سے موجود تھا مگر لباس وجود سے عاری تھا۔ جیسے ماں کی کوکھ میں موجود بچہ جو جیتا جاگتا وجود تو رکھتا ہے مگر جب تک ماں درد زہ سہار کر اسے جنم نہیں دیتی، وہ اپنی زندگی کا اثبات نہیں کر سکتا۔ زندگی کے معمولی اجزا اور تجربات کے اندر ایسی گہری معنویت دیکھنا اور اسے اس کمال مہارت سے بیان کر دینا کہ قاری بھی اس معنویت میں پوری طرح شریک ہو جائے، ان کے فن افسانہ نگاری کا کمال ہے۔ جیسے ان کا افسانہ ”معدن“ ہے۔ بظاہر سیدھا سادا واقعاتی افسانہ ہے جس میں ایک ڈھلتی عمر کی عورت اپنے ایک ”ہمدم دیرینہ“ کی معیت میں— جسے ہمدم دیرینہ ماننے میں اسے تامل ہے اور ڈر ہے کہ اس سے کوئی رومانوی قصہ نہ منسوب کر لیا جائے، (شاید وہ ایک ممکنہ ہم دم دیرینہ ہے، جو دیرینہ تو ضرور ہے لیکن ہم دم ہونے کی اہلیت بھی رکھتا تھا، مگر ہو نہ پایا)— سونے کی کان میں اترتی ہے۔ اسے وہ دولت دیکھنے کی تمنا ہے جوزمین کی آغوش میں دبی ہے اور جس کی حفاظت پر سرسراتے ہوئے سانپ مامور ہیں۔ جدید لفٹ کے ذریعے زمین کے اندر ڈیڑھ کلومیٹر کی گہرائی میں ، ائر کنڈیشنڈ دفتر اور شاہدہ پروین کی آواز، ”روٹھی رت نہ مانی، عمریا بیت گئی“۔ مگر ابھی اس نے اطراف میں موجود سنگین زر خالص کو چھو کر بھی نہ دیکھا تھا کہ کسی فنی خرابی کے باعث خطرے کے الارم بج اٹھتے ہیں جیسے کوئی سانپ سرسرا رہا ہو اور اسے واپس اسی لفٹ میں دھکیل دیا جاتا ہے جس کے بٹنوں اور برقی نظام سے وہ بالکل ناواقف ہے۔ قصہ بالکل صاف اور واضح ہے مگر ا س کے بیان میں ایسی رمزیاتی کیفیت ہے جو اس عام واقعے کو زندگی کا اہم ترین وقوعہ بنا دیتی ہے۔بیانیہ بہت دلچسپ اور شگفتہ ہے اور اس قدر سنجیدہ اور دقیق معاملے کی پر اسراریت کو قابل برداشت بلکہ دلچسپ بنا دیتا ہے۔ عالمی طاقتوں کے درمیان کشمکش کی اصل وجہ، اساطیر اور قرآنی آیات کے حوالے اس سادہ قصے میں ایسی دبازت پیدا کر دیتے ہیں جس سے اس کے معانی کی کئی تہیں روشن ہوتی ہیں۔ سونا کیا ہے؟ سونے کا طاقت سے کیا تعلق ہے؟سونے کی حفاظت پر سانپ کیوں مامور ہوتے ہیں؟ سین کی آواز میں یہ کیسی سرسراہٹ ہے؟ قدیم حویلیوں میں فرش کے نیچے دبی سونے کی اشرفیوں بھری دیگوں کے لڑھکنے سے یہ آواز کیوں آتی ہے کہ بیٹا دے دو، دولت لے لو! ؟ دولت لینے کے لیے بیٹے دینا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی مابعد الطبیعیاتی تناظر ہے؟ سونا ذات کا بھی تو ہوتا ہے۔ اپنے وجود کے معدن میں بھی تو اترنا پڑتا ہے اور یہ بھی ایک خطرناک کام ہوتا ہے۔ یہ اور ایسے کتنے ہی تناظرات اس افسانے کے متن میں پنہاں ہیں۔
بے: اس سے مجھے یاد آیا کہ ان کے کئی افسانوں میں مرکزی کردار کی بچپن کے کسی ساتھی سے اچانک اور غیر متوقع ملاقات کا موقع نظر آتا ہے۔ ایسا ساتھ، جس سے کوئی رومانی تعلق تو نہیں تھا، مگر بہت سے یادیں مشترک خزانے کی طرح دونوں کا سرمایہ تھیں (آخر خزانے کئی طرح کے ہوتے ہیں، صرف سونا تو خزانہ نہیں ہوتا) مگر اکثر وہ اس ساتھی سے کھل کر باتیں نہیں کر پاتی، کیوں کہ اس کے قریب کوئی نہ کوئی اس کی حرکات و سکنات کا نگران موجود رہتا ہے۔ (سانپ کی طرح؟) جس سے کوئی شکایت نہیں مگر اس کا خوف رگ و پے میں لہراتا ہے۔ جیسے افسانہ ”واشنگ مشین“ ۔ بلکہ ”واشنگ مشین“ میں دوسرا کردار شبر کا ہے جو ان کے اولین مجموعے میں شامل افسانے ”گنگ شہزادی“ میں بھی اسی نام اور انھی تفاصیل کے ساتھ موجود ہے۔
الف: ایک اور تجربہ جو ان کے بعد کے دور کے افسانوں میں نمایاں ہے، بوڑھے ہونے کا تجربہ ہے۔ زوال عمر کے آثار، عصر کے وقت کا سہم، جس کے آگے اندھیرا ہے، ڈھلتا ہوا سورج، ضعف اور قویٰ کے مضمحل ہوجانے کا ادراک، مستقبل کا اندیشہ، فنا کا خیال۔ بلکہ بعض افسانوں میں تو قرآن کے حوالے سے قیامت کے مناظر کا بیان بھی ہے اور اسلامی عقائد کے مطابق سزا ، جزا ، فرشتوں اور حساب کتاب کا احساس بھی بیان ہوا ہے۔ ”جینے کی پابندی“ میں شامل ایک افسانے ”پکنک“ میں تو نئی نسل کا پرانی نسل کے بارے میں رویہ اتنے سفاک انداز میں بیان کیا گیاہے کہ خوف آتا ہے۔
ویسے تو ان کے مجموعے ”دروازہ“ سے ان کے موضوعات کا تنوع نمایاں ہونے لگتا ہے اور آخری مجموعے ”جینے کی پابندی“ تک ہمیں بے شمار موضوعات پرت در پرت کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن موضوعات سے قطع نظر جو چیز ہمیں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے وہ ان کا تھری ڈی بیانیہ ہے۔
بے: ”دروازہ“ کا دیباچہ لکھتے ہوئے ڈاکٹر محمد اجمل نے بھی تو لکھا ہے، ” اردو میں خالدہ حسین کا ایک ایسا مقام ہے جو اور کسی افسانہ نگار کو نصیب نہیں ہوا۔ اس اسلوب میں نشوو نما کی صلاحیتیں موجود ہیں اور یہ کچھ بعید نہیں کہ خالدہ حسین اسی اسلوب کی تربیت و تکمیل کرتے کرتے ہمیں اس کے مزید نادر پہلوؤں سے روشناس کرائیں۔“
الف: ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر اجمل کی اسلوب سے مراد ان کا یہی خاص ہنر ہو جسے میں ان کا تھری ڈی بیانیہ کہہ رہی ہوں۔ یہ تھری ڈی بیانیہ ہمیں ان کے افسانوں میں جا بجا نظر آتا ہے۔ بلکہ تھری ڈی سے بھی آگے نکل کراس میں ایک اور ڈائمنشن موجود ہے اور وہ ہے دیکھنے والی نظر کا خود موجود ہونا ۔ یعنی جب کسی شے کا بیان کیا جاتا ہے تو نہ صرف اس کے تینوں ابعاد دکھائی دیتے ہیں بلکہ اسے دیکھنے والی آنکھ بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایک منفرد تجربہ ہے جو خالدہ حسین کے سوا کسی اور کے ہاں ہمیں اتنی وضاحت، تکرار اور اصرار سے نظر نہیں آتا۔ میرا جی چاہتا کہ اس کی کچھ مثالیں پیش کروں مگر جب اقتباس منتخب کرنے لگتی ہوں تو اتنی مثالیں نظر آتی ہیں کہ ششدر رہ جاتی ہوں۔
دوسری بات جو ان کے بیانیے کی انفرادیت ہے، وہ ایک عورت کی زبان ہے۔ متوسط طبقے کی تعلیم یافتہ ، ملازمت پیشہ اور باشعور عورت، جس کے ارد گرد موجود ماحول شہری زندگی کے متوسط طبقے کا عام ماحول ہے۔ اس کے مشاہدے میں بہت گہرائی ہے ۔ وہ روزمرہ کی اشیا کو غور سے دیکھنے اور ان سے گہرے معانی اخذ کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتی ہے۔ سینڈلوں سے لے کر ردی کے ڈھیر تک وہ ہر شے پر غور کرنے اور اس سے کوئی نہ کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس عورت کی ذہنی رفعت اور گہرائی اس کے ارد گرد موجود دوسری خواتین کی معمولی فکری صلاحیت کے پس منظر میں اور زیادہ اجاگر ہوتی ہے۔ ان کے بیشترافسانوں کی مرکزی کردار یہی منفرد اور اپنے ماحول سے الگ تھلگ اور بالا تر نظر آنے والی باشعور عورت ہے۔ یہی مرکزی کردار ان افسانوں کا راوی بھی ہے۔ ان کے افسانوں میں تخلیق ہونے والی دنیا اسی مرکزی کردار کی نظر سے دکھائی دیتی ہے ۔ قاری وہی کچھ دیکھتا ہے جو یہ کردار اسے دکھاتا ہے اور وہی سنتا اور محسوس کرتا ہے جو یہ کردار چاہتا ہے۔ اس مرکزی کردار کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ عام روش کے برعکس اس عورت کردارکے بالمقابل کوئی مرد کردار نہیں ہے ۔ اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ ان کے افسانوں میں مرد کردار نہیں ہیں۔ مرد کردار یقیناً موجود ہیں اور اہم بھی ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے اس ہیروئن کا ہیرو سمجھا جا سکے۔ وہ مرد کرداروں کو دیکھتی، ان سے ہم کلام ہوتی اور ان سے معاملہ بھی کرتی ہے۔ کہیں برابری کی سطح پر، کہیں ان کے جبر کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوئی اور کہیں ان کے طرز عمل پر حیران ہوتی ہوئی ۔ لیکن ان میں سے کوئی کردار ایسا نہیں جو اس عورت کی آرزو کا مرکز بن سکے۔ یا کم از کم اس کے سامنے ایک ایسے روپ میں سامنے آئے جسے پانے، جس سے کوئی ذہنی یا قلبی تعلق قائم کرنے کی خواہش پیدا ہو۔ خالدہ حسین کے افسانوں کی یہ مرکزی کردار ایک خود مکتفی ذات کے روپ میں سامنے آتی ہے۔ اسی لیے اس کے ارد گرد ایک شدید نوعیت کی تنہائی ہے۔ ایسا لگتاہے جیسے وہ ایک شفاف خلائی کیپسول میں زندہ ہے جہاں وہ سب کچھ دیکھتی اور محسوس کرتی ہے مگر اس تک پہنچنا ناممکن ہے۔ غالباً اس کی ذہنی سطح ایسی بلند ہے کہ ارد گرد موجود روایتی تعلق اور رشتے اس کی تسکین کا سامان نہیں بن سکتے۔ اس کی تسکین جذباتی نہیں ذہنی تعلق سے جڑی ہوئی ہے اور ذہنی تعلق کے لیے اسے اپنے برابر کی ذہنی سطح درکار ہے۔ بہر حال یہ بات اہم ہے اور بار بار اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ افسانے ایک عورت کی تخلیق ہیں۔ اس کا کچھ اندازہ ان کے تین افسانوں کے عنوانات سے بھی ہوتا ہے، ” آدھی عورت، مصروف عورت اور زوال پسند عورت۔ “ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ افسانے صرف ایک عورت کی دنیا تک محدود ہیں۔ ہر گز نہیں۔ یہ دنیا تو وسیع ہے۔ یہ صرف مادے کی دنیا نہیں، ماورا کی دنیا بھی ہے ۔ عورت، مرد، اور بچوں کی دنیا۔۔۔ مذہب، تصوف، سیاست، معیشت اور معاشرت کے معاملوں میں ملوث دنیا۔ لیکن ان افسانوں کی خاص بات یہ ہے کہ اس پوری، وسیع و عریض دنیا کو ایک عورت کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔
بے: ڈاکٹر اجمل نے اپنے پیش لفظ میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ:
۔۔۔ وہ فن پارے جو اپنے اسلوب میں علامتی ہوں اور واقعات و حادثات کو اس طرح پیش کریں کہ وہ علامتیں بن کر ذہن میں جذبۂ حیرت کا محرک بنیں ، نفسیاتی تبصرے کی ایک دلآویز دعوت بن جاتے ہیں، ذہن پر ایک سحر آمیز کیفیت طاری کر دیتے ہیں اور انسان اس جادو کی مستی میں شعور و آگہی کی راہیں تلاش کرتا ہے۔ ایسے تبصرے میں ”سحر“ کا قائم رہنا ضروری ہے ورنہ انسان عقل کے ذریعے علامتوں کی تشریح کرتا ہے اور وہ تشریح بالکل میکانکی اور بے جان ہوتی ہے۔ اپنے افسانوں میں خالدہ حسین نے اس ”سحر“ کو قائم رکھا ہے اور یہ وہ فضا ہے جو طلسمی بھی ہے اور دلآویز بھی۔ اس فضا میں انسان کی ذات کا دائمی طلسم ایسا جالا بنتا ہے کہ اس فضا میں سے نکلنا مشکل ہو جاتاہے۔ یہ طلسم ایک فن کارانہ دیانت سے تخلیق کیا گیا ہے۔
الف: ڈاکٹر اجمل صاحب واحد شخصیت ہیں جن سے خالدہ حسین نے خود دیباچہ لکھنے کی درخواست کی تھی اور اس بات پر فخر بھی محسوس کرتی تھیں۔ وہ ایک ماہر نفسیات تھے اور انھوں نے اسی حوالے سے خالدہ حسین کے فن کو دیکھا اور سمجھا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ خالدہ حسین کے ہاں واقعات و حادثات علامات بن کر سامنے آتے ہیں مگر یہ علامات خشک اور بے جان نہیں بلکہ ایک طلسمی فضا پیدا کر دیتی ہیں، بہت اہم ہے۔ اس تکنیک کو مابعد جدید تنقیدی تھیوری میں طلسمی حقیقت نگاری کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایسی تکنیک ہے جس میں حقیقت اور خواب کی سرحدیں مٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ واقعات کی عقلی توجیہ کے بجائے ان کا محسوساتی پیکر زیادہ اہمیت رکھتا ہے ۔ طلسمی حقیقت نگاری کوئی ایسا انوکھا تجربہ نہیں جس سے ہم ہر روز نہ گزرتے ہوں البتہ عادتاً یا اپنی عقلی تربیت کے زیر اثر ہم ایسے تجربات کو اہمیت دینے کے قائل نہیں ہوتے۔ ورنہ ہم میں سے ہر ایک اس تجربے سے گزرتا ہے کہ بعض اوقات اشیا اپنی حقیقی ٹھوس صورت کے بجائے تبدیل ہوتی ہوئی، سیال کیفیت کا روپ دھار کر سامنے آتی ہیں۔ اندھیرے میں دیوار پر بننے والی شبیہیں، بادلوں کے ٹکڑوں پر ابھر آنے والے نقش و نگار، ساکت اشیا کا متحرک اور متحرک اشیا کا ایک پل کو بالکل ساکت محسوس ہونا، ایسے تجربات ہیں جن کا مرکز ہمارا ادراک ہے، خارجی اشیا نہیں۔ فلسفیانہ سطح پر خارجی اشیا کے بجائے ان کے تاثر یا ادراکی کیفیت کو بیان کر دینے سے جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے طلسماتی کیفیات کا حامل ہوتا ہے کیوں کہ وہ اس ادراک کی تخلیق میں اولاً شریک نہیں ہوتے۔ البتہ اگر تحریر میں جان ہو تو قاری اسے پڑھ کر اسی کیفیت کا شکار ہو سکتا ہے۔ خالدہ حسین کے ہاں یہ تکنیک بڑے فطری انداز میں تکرار سے دکھائی دیتی ہے۔
بے: ڈاکٹراجمل نے تو ان کے اسلوب کی ایک ہی صفت بتائی ہے، علامت کا سحر آگیں استعمال۔ اس کے علاوہ بھی توان کے اسلوب کی کچھ خصوصیات ہوں گی۔
الف: ان کے اسلوب کا ایک نمایاں پہلو، اس کی شگفتگی اور زندہ دلی بھی ہے جس میں طنز و ایما کا پہلو نمایاں ہے۔ اس قدر سنجیدہ اور اداس کردینے والے تجربات کے بیان کو ایسی شگفتگی میسر نہ آتی تو شاید ان کی مطالعیت بہت کم ہو جاتی مگر خالدہ حسین مسلسل اپنے اسلوب میں ایسا انداز اختیار کرتی ہیں جس سے پڑھنے والے پر یاسیت، یبوست اور اکتاہٹ طاری نہیں ہوتی۔ بیشتر مقامات پر ان کا انداز استہزائیہ ہو جاتا ہے لیکن یہ استہزائیہ انداز دوسروں کی ہتک یا دل شکنی کا موجب نہیں بنتا کیوں کہ ان کا مرکزی کرداراکثر اس کا نشانہ خود اپنے آپ کو بناتا ہے۔
ایک اور بات، جو ان کی تحریر کو زیادہ قابل مطالعہ بناتی ہے، ان کے بیانیے کی تیز رفتاری ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جملوں کے استعمال سے بیانیے کی رفتار کو تیز کر دیتی ہیں۔ لمبے لمبے جملوں سے بیانیے کی رفتار میں جو سست روی در آتی ہے، اس سے گریز کر کے انھوں نے اپنے گہرے فن کارانہ شعور کا اظہار کیا ہے۔
پھریہ بات بھی اہم ہے کہ انھوں نے ایک طرف تو معاصر زبان کا استعمال کیا ہے۔ ان کے مکالمے کتابی زبان میں نہیں ، بالکل فطری اور حقیقی زبان میں ہیں جو ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں سنتے ہیں۔ جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے، انگریزی کے الفاظ و تراکیب استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتیں ۔ لیکن اس کے باوجود ان کا اسلوب سطحی نہیں۔ مکالموں کی زبان عام تو ہے مگر ایسی نہیں کہ عامیانہ لگے۔ اسلوب کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں وہاں ایسے ٹکڑے بار بار نظر آتے ہیں جو اپنی دبازت، تہ داری اور ادبی شان کے باعث شاعری کی طرح خیال انگیز اور معنی خیز ہوتے ہیں۔ ایسے ٹکڑے مذہبی تاریخی و اساطیری حوالوں اور اصطلاحات سے مزین ہیں اور زمان و مکاں کی سرحدوں کو پھلانگتے ہوئے، ماضی، حال اور مستقبل کو ایک کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ کئی جگہ پر تو ان افسانوں کے جملے کے جملے قرآنی آیات کے تراجم پر مبنی ہوتے ہیں۔ اردو فارسی اشعار کے مصرعوں، فارسی کہاوتوں، جملوں اور تراکیب کا استعمال بھی فراوانی سے کرتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے جملوں میں ایسا وفور ، ایسی شدت ہے کہ ان کے الفاظ روکھے پھیکے ، اوربے جان حروف کا مجموعہ نہیں ، دھڑکتے ہوئے دل کے مانند زندہ اورابلتے لہو کی طرح رنگین اور گرم اجسام محسوس ہوتے ہیں جو پڑھنے والے سے ہمکلام ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کا بڑا شدید احساس دلاتے ہیں۔
بے: ان کے افسانوں کے عنوان بھی بڑے انوکھے اور توجہ طلب ہیں۔ ڈیڈ لیٹر، ایکشن ری پلے، اسم اعظم، طلسم ہو ش ربا، پانچ دس، فشار الدم، بلیک ہول، الساعت، گٹھڑی میں لاگا چور، یار من بیا، قفلِ ابجد، دادی آج چھٹی پر ہیں، وغیرہ۔
الف: عنوان ہی نہیں، ایک اور بات بھی ان کے افسانوں میں نمایاں ہے۔ عموماً ان کا کوئی واضح اور منطقی انجام نہیں ہوتا۔ ایسے جیسے ایک سڑک پر جا رہے ہوں۔ سفر ختم ہوجائے لیکن سڑک ختم نہ ہو۔ دور کہیں کو جاتی نظر آتی رہے اور اس پر سفر کرنے کی خواہش باقی رہ جائے۔ ان کی کہانیاں شروع بھی کہیں درمیان سے ہوتی ہیں اور ختم بھی کہیں درمیان ہی میں ہو جاتی ہیں۔ ایسے جیسے زندگی کے تسلسل کا کوئی ایک ٹکڑا جو کسی کیمرہ نما نظر کے فوکس میں آ جائے۔ ایک پر شور، سیال بہاؤ جس کا کوئی ایک گرداب، کسی ایک لہر کا اچھال، کسی ایک موج کا خرام ہو، جس پر نظر جم جائے اور کچھ دیر کے لیے باقی سارا دریا نظر سے اوجھل ہو جائے۔ بس وہی ایک نقطہ نمایاں ہو کر نظر کے سامنے موجود رہے اور جب معدوم ہو تو احساس ہو کہ اس کے اردو گرد ایک پورا دریا ، اپنی تمام تر شوریدہ سری، اسرار اور گہرائی سمیت موجود ہے ۔ ایسے میں دریا کا طلسم اور بھی گہرا اور دلگیر محسوس ہونے لگے۔
ان افسانوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ بظاہر ان کا موضوع زندگی کے عام اور معمولی شب و روز ہیں۔ کرائے کے مکان، ہمسائیوں کا گوسپ، ملازمت پیشہ عورتوں کے معمولات کی سنگلاخی، پڑوسیوں کے تیور اور ایسی ہی روزمرہ کی مصروفیات۔ مگر افسانہ نگار انھیں ایسے رخ سے دیکھتی اور بیان کرتی ہیں کہ ان کے اندر سے زندگی کے اسرار پھوٹتے اور منکشف ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ معمول کی باتوں سے غیر معمولی نتائج اخذ کرنے کے لیے ایک انتہائی غیر معمولی دماغ اور اس سے بھی زیادہ مشاق قلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ خالدہ حسین کے پاس یہ دونوں قوتیں وافر مقدار میں موجود ہیں۔
افسانے کی صنف کے حوالے سے ان کا فنی شعور بہت پختہ ہے اور بالکل غیر شعوری طور پر اپنا اظہار کرتا ہے ۔ یہ کسی بھی قسم کی شعوری کوشش، کسی خاص تکنیک کے استعمال سے اثر پیدا کرنے یا مصنوعی فضا بندی سے کوئی خاص تاثر اجاگر کرنے کی جدو جہد سے بالکل پاک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ افسانے کی صنف کے فنی تقاضوں سے نابلد تھیں۔ اپنے ایک انٹرویو (مطبوعہ ”دنیا زاد“، ۴۵) میں اپنے فنی شعور کے بارے میں انھوں نے وضاحت بھی کی ہے ، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ شعور ان کے فن کے اندر اس طرح مدغم ہو کر سامنے آتا ہے جیسے شربت میں چینی گھل جاتی ہے۔ ہر گھونٹ میں اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے لیکن کہیں نظر نہیں آتی۔
اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ خالدہ حسین معاصر عہد میں افسانے کی سب سے طاقت ور اور ممتاز ترین آواز ہیں۔ انھوں نے اردو افسانے کے امکانات کو وسیع تر کیا ہے اور اس صنف کو مزید معتبر بنا دیا ہے۔ آنے والے دور میں خالدہ حسین کو نظر انداز کر کے اردو افسانے کی تاریخ نہیں لکھی جا سکے گی۔
ماخذ: دنیا زاد 2016


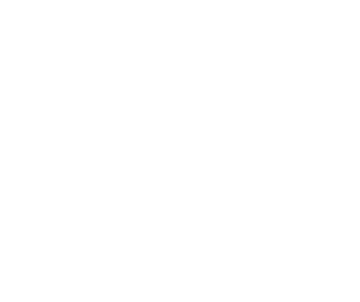
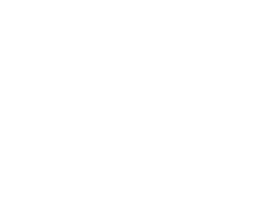



شاندار تخلیقی بیانیے کی حامل تحریر?