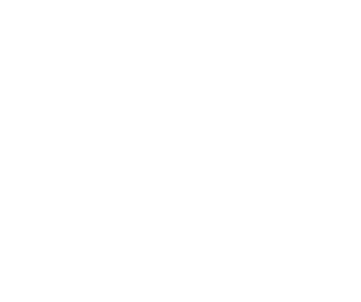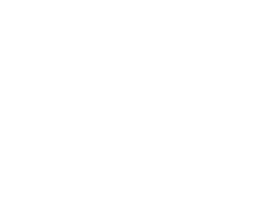وقت کے دو نقطے (تحریر: محمد حامد زمان)
۲۰۱۱ کے ابتدائی ایام تھے۔ ہمارے گھر میں ایک گہما گہمی تھی۔ فروری کے وسط میں مجھے سکندریہ کے تاریخی شہر میں ایک کانفرنس میں مدعو کیا گیا تھا۔ اور ہماری خوش بختی تھی کہ کانفرنس کے مقررہ دن اور بچوں کی موسم سرما کی تعطیل کے ایام میں اتفاقاً باہمی ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ نتیجتاً ارادہ یہ تھا کہ سبھی نقوشِ کہن کے روبرو ہونے بوسٹن سے براستہ لندن، مصر جائیں گے۔ چار عدد ٹکٹوں کا بندوبست بھی ہو چکا تھا۔ میری ٹکٹ کی قیمت تو کانفرنس کے منتظمین کانفرنس کے بعد، رسیدیں جمع کرانے کی صورت میں، واپس کر دیتے مگر باقی تین ٹکٹیں اپنے پلے سے لینی پڑ گئی تھیں۔ نئی نوکری کے ابتدائی دن تھے، اور بنک بیلنس پہلے بھی قد آور نہ تھا اور برٹش ائر ویز کی مہربانی کی بدولت اب اس کی مزید حجامت ہو چکی تھی۔ مگر دل کو یہ تسلی دی کہ مصر جانے کا موقع ہر روز ہاتھ نہیں آتا، اور ہمیں ویسے بھی ہر کوئی نہیں بلاتا، اس لئے اس کانفرنس کو ایک نعمت جانئے۔ اب چونکہ ٹکٹ ہاتھ آ چکی تھی اس لئے اگلے موضوعات پر بات شروع ہوئی۔ کس ہوٹل میں رہیں گے اور کس ٹیکسی کا انتظام کریں گے؟ سکندریہ میں کتنے روز رہیں گے اور قاہرہ کیسے جائیں گے؟ ابوالہول سے کب ملیں گے اور احرام سے دمِ دید کا ارادہ کس روز کا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ قریبی لائبریری سے سکندریہ کی تاریخ پر بھی کچھ کتب حاصل کیں اور ان کا مطالعہ شروع ہوا۔ سکندر صاحب کے احوالِ زیست بھی نظر سے گزرے۔ یونان سے ملتان، اور ان کے مابین مصر میں، بمع افواج اور سامانِ حرب، موصوف کی آمد کے بارے میں بھی چیدہ چیدہ معلومات کو نوٹ کیا۔ ارسطو نے اپنے تلمیذِ رشید کو کیا سکھایا اور کیا نہ سکھایا کے بارے میں کچھ فکر کی۔ یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ سکندریہ کی شاندار لائبریری کا کیا ہوا، اور اب جو اس کی نقل وہاں پر ہے وہ کسی کام کی بھی ہے یا پھر وہاں پر بھی گھر بیٹھے اعلی کشیدہ کاری سیکھنے، یا کمپیوٹر کیا ہے؟ کے عنوانات پر مبنی کتب کا غلبہ ہے۔ مصر میں بسر کرنے کو دن چونکہ کم تھے، اس لئے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کچھ اس بار کریں گے، اور کیا کچھ مستقبل کے کسی اور سفر تک موخر کر دیا جائے۔
بوسٹن میں احباب میں کچھ مصری دوست تھے، ان سے صلاح لی، بچوں کے بھی کچھ مصری ہم عصر ان کے ہم جماعت تھے، ان کے والدین سے نیا تعلق جوڑا، بتایا کہ مصر اور پاکستان تو گویا یک جان دو قالب ہیں اور اس دیرینہ تعلق کی چھاؤں میں ان سے مشورہ مانگا۔ مصر جانے کے لئے ویزہ کی درخواست پر کوائف درج ہوئے، اور اس پر چسپاں کر نے کے لئے پاسپورٹ سائز کی تصاویر ٹائی پہن کر بنوائی گئیں، کہ کہیں سفارت کاروں کو گماں نہ ہو کہ ہم ایسے ویسے ہیں۔
ہمارا شوق حد درجہ عروج پر تھا، مگر ہمیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ جس قدر اشتیاق ہمیں اہلیانِ مصر سے ملنے کا تھا، شاید ان کو ہماری آمد کی اتنی بے چینی نہ تھی۔
ابھی ہماری تیاری جاری ہی تھی کہ ایک شام ہم نے ڈرائنگ روم میں موجود اپنے چھوٹے سے پرانی طرز کے ٹی وی پر سی این این کی براہ راست خبروں میں مصر میں مہنگائی سے شکست خوردہ محنت کشوں کا مجمع دیکھا۔ تونس میں پہلے ہی عوام اہلِ اقتدار سے جان چھڑا چکے تھے مگر ابھی یہ معلوم نہ تھا کہ تونس میں مصائب سے تنگ آ کر، ایک غریب ٹھیلے والا، محمد البو عزیزی، جس نے افلاس اور ظلم سے تنگ آکر خود سوزی کی راہ لی، اس کے بدن کے شعلوں کی حرارت اہلیانِ مصر کے دلوں کو بھی گرمائے گی، یا پھر حسنی مبارک صاحب کی پولیس اور فوج ایسی حدت سے معمور قلب و نظر کو سرد خانوں میں پہنچا دے گی؟ ابتدا میں قرین قیاس یہ تھا کہ بعد الذکر کا امکان قوی ہے۔ مگر کاتبِ تقدیر نے شاید کچھ اور تحریر کیا تھا۔ حسنی مبارک کی حکومت کی کوشش کے باوجود تونس سے جلنے والی شمع کو چند اہلِ صفا حلقہ کئے ہوئے تھے، اورر بقول فیض صاحب یوں لگتا تھا کہ
کچھ روشنی باقی تو ہے، ہر چند کہ کم ہے۔
دیکھتے ہی دیکھتے پھر اس شمع سے کچھ اور مشعلوں نے فیض حاصل کیا اور حالات کی رو میں ایک تغیانی محسوس ہوئی۔
ہم لوگ ہر روز شام کو ٹی وی لگاتے اور بدلتے حالات پر امریکی ماہرین، جنہوں نے شاید دو روز قبل ہی مصر کی کئی دہائیوں پر مبنی حالیہ تاریخ کو عجلت میں ازبر کیا تھا، کے تبصروں سے استفادہ کرتے۔ ادھر حسنی مبارک کے حامی، جن میں امریکہ میں مصر کے سفیر بھی شامل تھے، تجزیے کے لئے وقت نکالتے، ٹی وی پر تشریف لاتے اور ہمارے جیسے لوگوں کو بتاتے کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، سب ٹھیک ہے اور سڑکوں پر نکلنے والے ظلم کی چکی میں پسنے والے عام لوگ نہیں بلکہ دراصل بیرونی سرمائے کی لعنت سے پیٹ بھرنے والے دہشت گرد ہیں۔ غریب اور پسماندہ لوگوں پر سوال اٹھانے کی صورت میں دہشت گردی کے الزام کو چسپاں کرنے والے یہ حضرت نہ پہلے شخص تھے اور نہ آخری ہوں گے۔ اور اپنے انٹرویو میں یہ اور ان جیسے اہلِ اقتدار سامعین سے گویا سوال کرتے کہ اب آپ ہی بتلائیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھلا کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ان سفیر صاحب اور شہ کے دوسرے مصاحبوں کی گفتگو میں ذرہ برابر بھی نرم دلی نہ تھی، اور نہ ہی یہ احساس کہ بندۂ مزدور کے اوقات کس قدر تلخ ہو چکے ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے اب ایسے لوگوں سے گھن آنے لگی تھی۔
حالات دن بدن بدل رہے تھے، جو پہلے اکا دکا جلسے تھے، اور جذبات کے انفرادی بہتے نالے تھے، اب ایک بڑے انقلابی سیلِ رواں کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ کچھ مصری احباب سے استفسار کیا تو وہ بھی پرجوش نظر آئے۔ زندگی کے زنداں میں روشنی کی اک کرن سلاسلِ استحصال کو دھکیل کر اپنی آمد کی بشارت دے رہی تھی۔ ٹی وی پر جو تصاویر دیکھیں تو مصر کے وسط میں واقع تحریر سکوائر میں ایک عالم نظر آیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قاہرہ کا ہر باسی، پیر و جواں، مرد و زن، شاہ و مفلس تحریر سکوائر میں جمع ہے۔ اس بحرِ انسانی کے انقلابی جذبے کی حرارت میں نے بوسٹن کے نواحی علاقے میں فروری کے ابتدائی ایام کی سخت سردی میں بھی محسوس کی۔ جب انقلاب کے جذبے سے لیس، لا تعداد لوگوں کا مجمع ”الشعب یرید، اسقاط النظام“ (جس کا ایک کام چلاؤ ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ ”ارادہ اس عوام کا، خاتمہ اس نظام کا“) کا نعرہ بلند کرتے تو حرکتِ قلب میں میں بھی اس کا سوز محسوس کرتا۔ میں بھی یہ خواہش کرتا کہ اس غیر منصفانہ نظام کی خاک پر اک نئی دنیا کی بنیاد رکھی جائے۔ یہ الربیع العربی، جسے اب عرب سپرنگ کہا جاتا ہے، کے ابتدائی ایام تھے۔ اس کی بازگشت اقوامِ عالم میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ فیس بک کے ذریعے نوجوانِ زندہ دلانِ مصر اس تحریک کو ایک نئی جہت بخش رہے تھے۔ کب اکٹھے ہونا ہے، کہاں ملنا ہے، پولیس کو چکما کیسے دینا ہے، فیس بک کے ذریعے یہ پیغام گھر گھر تک پہنچ رہا تھا۔ مگر مستقبل میں کیا ہوگا، کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ کچھ لوگ اضطراب میں تھے اور ہمارے جیسے بہت سے انتظار میں۔
حالات کے تغیر کے پیشِ نظر اب ہماری کانفرنس منسوخ ہو چکی تھی، میرے ٹکٹ کے پیسے اب کانفرنس منتظمین نے نہیں بھرنے تھے، مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ ہزاروں میل دور، میں اور نہ جانے کتنے ہی اور، تحریر سکوائر میں لکھی جانے والی نئی تاریخ کے پہلے حروف پڑھنے کے لئے شدت سے بے تاب تھے۔ ذہن میں اب بھی یہ اضطراب تھا کہ کہیں یہاں پر بھی حریت کی چنگاری ٹینکوں کے سرد آہن سے بجھا نہ دی جائے۔ گزشتہ نصف صدی میں بوڈا پیسٹ، پراگ، بیجنگ اور نہ جانے کتنے ہی اور شہروں میں اسی طرز میں لکھا ہوا ترانہِ آزادی نوحوں میں تبدیل ہوا۔ شروع کے چند روز جب قاہرہ کی سڑکوں پر یونیفارم میں ملبوس سپاہیوں کی نفری کی بڑی تعداد کی تصاویر دیکھیں تو اس امر کا امکان غالب نظر آیا، مگر بالٓاخر یہ خدشات ٹل گئے۔ ۱۱ فروری ۲۰۱۱ کو نائب صدر جنرل عمر سلیمان نے لگ بھگ ساڑھے گیارہ سیکنڈ پر محیط تقریر میں ایک نئے دن کی بشارت دے دی۔ حسنی مبارک کی حکومت کے استعفی کا اعلان کیا، افواجِ مملکت کے ہاتھ میں ملکی باگ ڈور سونپی، آخر میں اہلیانِ مصر کو دعا دی کہ رب العزت ان کا حامی و ناصر ہو، اور خاموشی سے اپنی راہ لی۔ تحریر سکوائر کے ولولے اور خوشی کی صدا ہم نے بھی اپنے ڈرائینگ روم میں سنی۔
الشعب یرید اسقاط النظام
۱۱ فروری ۲۰۱۱ کی لگ بھگ ساڑھے گیارہ سیکنڈ کی تقریر کے لگ بھگ ساڑھے گیارہ سال بعد میں تحریر سکوائر کے ایک کیفے یعنی ایک مقہی میں بیٹھا تھا۔ یہ مقہی سکوائر کے عین سامنے ہے۔ رات کے تقریبا ساڑھے نو بج رہے تھے۔ میری کرسی کی پشت کیفے کی طرف تھی اور میری نگاہ میرے سامنے کے تحریر سکوائر کی طرف۔ قاہرہ کی لامتناہی ٹریفک، چھوٹی بڑی گاڑیوں کے بے ہنگم ہارن کا تسلسل، سیاحوں کے لئے چلنے والے تانگے جس میں صرف امریکہ اور یورپ سے آنے والے سیاح سفر کرتے، کا ہجوم، کوچوان کی غیر مستند تاریخ پر ”واؤ، واؤ“ کے نعروں کی بازگشت، نو بیاہتا جوڑوں کی سڑک کے برابر سیلفیاں، پیدل چلنے والوں کا بڑی سڑک پر بے خوف و خطر چلنا، اور نیل کے اس جانب کے بڑے ہوٹلوں کے روشن مینار سے آنے والی زرد و سفید روشنی، سبھی کچھ تحریر سکوائر کے آمیزے میں شامل تھا۔ آج سے قبل میرا اور تحریر سکوائر کا تعارف صرف ٹی وی کیمرے کی وساطت سے تھا۔ ایک دہائی قبل کیمروں کی آنکھ سے دکھائی دینے والا تحریر سکوائر ہمارے ٹی وی پر ایک وسیع میدان معلوم ہوتا تھا، کہ جس کی حدود بظاہر غیر معمولی تھیں۔ جب یہاں آئے تو مرزا سودا یاد آ گئے
؎ سوداؔ جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ
کیا جانئے تو نے اسے کس آن میں دیکھا
اگر میں تحریر سکوائر کی وسعت کا موازنہ ہمارے ہاں کے کسی چوک سے کروں تو شاید مجھ پر بد ذوقی کا الزام لگ جائے، مگر یہ چوک میں نے صبح میں بھی دیکھا تھا اور اس سے ملاقات کا شرف سرِ شام اور پسِ شام بھی حاصل ہوا تھا، مگر اس کی وسعت سے میں قطعاً متاثر نہ ہو سکا۔ مگر پھر یاد آیا کہ تاریخ کی قد آور شخصیات ضروری تو نہیں کہ اصل میں بھی دراز قامت ہوں۔ میں نے ایک عرب کافی کی پیالی منگوا نے کا ارادہ کیا۔ یہاں پر کام کرنے والے صاحب انگریزی سے ناواقف تھے، جس میں کوئی تعجب اور اچھنبے کی بات نہیں، اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ میں ان کے دیس میں وارد ہوا تھا، اور میں ان کی زبان سے نابلد تھا۔ گو کہ میں عربی سے مکمل طور پر پیدل نہیں، اور اپنے تئیں میں نے کچھ کوشش بھی کی، مگر اس روز نہ وہ سمجھے نہ ہم سمجھے۔ اس سے پہلے کہ اشاروں کی زبان میں بات ہوتی اور نہ جانے میں کیا منگوا لیتا، کیفے کے اندر سے ایک صاحب، جو کہ پہلے اس کرسی پر براجمان تھے جہاں مینیجر بیٹھتا ہے، میرے میز پر تشریف لے آئے۔ فر فر انگریزی بول رہے تھے۔
کیا لیجئے گا؟
عرب کافی! سنا ہے کہ مقامی لوگ اس میں ڈھیر ساری الائچی ڈالتے ہیں، اگر ممکن ہو تو مقامی رنگ میں رنگی ہوئی عرب کافی۔
موصوف نے ایک لمحے کے لئے سوچا اور پھر مسکرا دئے، غالباً سوچ رہے تھے کہ ایک اور غیر ملکی کسی ویب سائٹ کو پڑھ کر پتا نہیں کیا مانگ رہا ہے اور مجھے بتا رہا ہے کہ مقامی لوگ کیسے کافی پیتے ہیں۔
جی ضرور۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔
ایک بلند آواز میں انہوں نے میرا آڈر دہرایا اور باورچی نے اثبات میں اپنے کونے سے اس کے موصول ہونے کی صدا بلند کی۔
وہ مڑنے کو تھے کہ میں نے فوراً سوال کیا۔ یہ کیفے کیا آپ کا ہے، یعنی مالک ہیں کیا آپ اس مقہی کے؟
جی۔ میرے دادا نے یہ جگہ خریدی تھی، اور پھر میرے والد نے یہ کاروبار سنبھالا، اور اب میں اس کو چلا رہا ہوں۔
آپ کا اسمِ گرامی؟
ابراہیم۔
کب سے چلا رہے ہیں اس کیفے کو؟ میں نے سوال کیا۔
۱۹۹۲ سے۔ تیس برس ہو گئے۔ میرے دادا نے یہ جگہ ۱۹۵۲ میں خریدی تھی۔
میں تو کیفے کے باہر سجی کرسیوں پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے اندر کے کمرے میں نظر دوڑائی تو بہت سی پرانی تصاویر نظر آئیں۔ کچھ اس کیفے کی، اور کچھ اس علاقے کی۔ تصاویر کے نیچے سال تو درج نہ تھے، مگر ان تصاویر میں سڑکوں پر موجود گاڑیوں سے دہائیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اکثر ۱۹۶۰ کی دہائی اور کچھ ۱۹۷۰کی دہائی کی تصاویر تھیں۔ گو یہ سکوائر انیسویں صدی کے وسط میں تعمیر ہوا، اس کا نام عرفِ عام میں تحریر سکوائر، یا میدان التحریر (یعنی میدانِ آزادی) ۱۹۱۹ کے انقلابِ مصر کے بعد پڑا۔ تاہم سرکاری طور پر اس کا نام میدان التحریر ۱۹۵۲ میں ایک اور انقلاب کے بعد رکھا گیا۔ ۱۹۵۲ کے انقلاب میں مصر کی بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور جمال عبدالناصر کی قیادت میں ایک جمہوری ریاست کی داغ بیل ڈالی گئی۔ یہ وہی برس ہے کہ جس میں ابراہیم صاحب کے دادا نے اس کیفے کی بنیاد ڈالی۔
ابراہیم صاحب کیا آپ قاہرہ سے ہیں؟
جی۔ میں پیدا یہیں ہوا تھا، مگر ہمارے آبا و اجداد اصل میں النوبہ (جسے انگریزی میں نوبیہ کہتے ہیں) سے ہیں۔
النوبہ کے نام سے مجھے کچھ آشنائی تھی۔ النوبہ کا وسیع علاقہ سوڈان کے شمالی اور مصر کے جنوبی علاقے پر محیط ہے۔ یہاں کے باسیوں کے خدوخال مصر کے شمالی علاقوں سے قدرے مختلف ہیں اور رنگت بھی نسبتاً سیاہی مائل ہے۔ مصر کے مرحوم صدر انور سادات کی والدہ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتی تھیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بالوں اور چہرے کے خدوخال پر افریقی اثر نسبتاً زیادہ تھا۔
میں نے ابراہیم صاحب سے النوبہ کے بارے میں پوچھا تو بولے کہ وہاں پر اب بھی بہت سے گھروں میں مقامی زبان بولی جاتی ہے، اور بہت سے نوبی لوگ افواجِ مصر میں کام کرتے ہیں۔ پھر خود ہی بولے کہ ۱۹۷۳ کی مصر اسرائیل جنگ میں صدر سادات اپنے کچھ قریبی ساتھیوں سے نوبی زبان میں بات کرتے تھے، جو اسرائیلی خفیہ اداروں کی سمجھ سے باہر تھی، اور یوں ہماری زبان نے نہ جانے کتنے مصریوں، اور ہمارے شہروں کو دشمن کی جارحیت سے محفوظ رکھا۔
اپنی زبان کے اس کارنامے کا سوچتے سوچتے ابراہیم صاحب کے چہرے پر ایک فخریہ مسکراہٹ آ گئی۔
اتنی دیر میں کافی آ گئی۔ سنہری سی کیتلی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سے پیالی۔
ابراہیم صاحب میرے برابر کی کرسی پر بیٹھ گئے۔
کافی انتہائی لذیذ تھی، اور قوی بھی۔ امریکہ کی بہت سی دوکانوں میں ملنے والے سیاہی مائل پتلے شوربے سے یکسر مختلف۔ الائچی کو اس قدر کوٹ کر ملایا گیا تھا کہ پیالی کے پیندے میں ایک تہ جم گئی تھی۔ ابراہیم صاحب نے ایک چمچی مہیا کی کہ اس سے پیندے میں مقیم الائچی کو ہلاتا رہوں۔ یہ تو پتہ نہیں کہ اہلیانِ مصر اس طرح سے کافی پیتے ہیں کہ نہیں لیکن اگر نہیں پیتے تو ان کو ضرور ایسا شروع کر دینا چاہیے۔ اچھی عادات کسی بھی عمر میں شروع کی جاسکتی ہیں، بھلے تہذیب کی عمر ہزاروں سال ہی کیوں نہ ہو۔
میری نگاہ میدان التحریر کے اس مرکز پر تھی جہاں پر ٹریفک کے گھومنے کے لئے ایک دائرہ ہے، جس کے اردگرد چار عدد مجسمے، جو کہ مصر کے مختلف علاقوں سے آثارِ قدیمہ کے ماہرین نے وقتاً فوقتاً نکالے، نصب ہیں۔ عین درمیان میں ایک نادر اوبیلسک/مجسمہ (جسے عربی میں مسلہ کہا جاتا ہے) نصب ہے۔ یہ مجسمہ قدیم مصری شہنشاہ ریمزیز کے زمانے کا ہے اور مصر کے شہر صان الحجر (جسے انگریزی میں تانس کہا جاتا ہے) میں کھدائی کے دوران دریافت ہوا تھا۔ اس دائرے کے ارد گرد گھاس اور حسین پھول لگائے گئے تھے۔ اس جاذبِ نظر منظر کی تاثیر کو مگر ایک چیز نے ماند کر دیا تھا۔ دائرے کے ساتھ، ہر طرف، سفید وردی میں ملبوس پہرے دار موجود تھے۔ رات کا وقت تھا، اور پہرے دار انتہائی بیزار دکھائی دے رہے تھے۔
یہ جانتے ہوئے کہ مصر میں اس وقت ہر موضوع پر بات کرنا آسان نہیں، اور سیاسی امور پر گفتگو کے نتائج ناسازگار بھی ہو سکتے ہیں، میں نے ڈرتے ڈرتے ابراہیم صاحب سے سوال کیا۔
یہ پہرے دار یہاں کیوں کھڑے ہیں؟
ابراہیم صاحب نگاہیں ملائے بغير بولے. تاکہ کوئی تحریر کے وسط میں آ کر ہنگامہ نہ برپا کر دے۔
کیا یہ ہر وقت یہاں پر ہوتے ہیں؟
جی۔
چند لمحوں کے لئے خاموشی رہی۔ میں نے مزید ہمت کی۔
۲۰۱۱ میں کیا آپ یہاں تھے؟ یہ بتانے کی ضرورت نہ تھی کہ میں ۲۰۱۱ کے کس روز، کس مہینے کا ذکر کر رہا تھا۔
ہاں بالكل۔ ابراہیم صاحب کی آواز میں ایک جوش پیدا ہوا، جس سے مجھے بھی مزید ہمت ملی۔
کیسا ماحول تھا؟
میں نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ ایک سمندر تھا لوگوں کا۔
کتنے لوگ تھے تقریباً؟
میرے خیال میں پندرہ سے بیس لاکھ کے درمیان۔ شاید اس سے بھی زیادہ۔ ابراہیم صاحب بولے۔
مگر اتنے لوگوں کی جگہ کہاں ہے کہ وہ یہاں سما سکیں۔
وہ میری طرف دیکھنے لگے اور مسکرا کر بولے۔ یہ سڑکیں اور گلیاں دیکھ رہے ہیں آپ؟
انہوں نے تحریر سکوائر سے منسلک بہت سی چھوٹی بڑی گلیوں اور سڑکوں کی طرف اشارہ کیا۔
جی۔
یہ سب بھر گئی تھیں۔ اس قدر لوگ تھے کہ زمین نظر نہیں آتی تھی۔ اور میلوں جانے والی سڑکیں بھی بھر چکی تھیں۔
ابراہیم صاحب خود ہی اپنے خیالوں میں کھو گئے اور کہانی آگے بڑھاتے ہوئے بولے۔
لوگ یہاں پر گویا واقعی مقیم تھے۔ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں رہنا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ کچھ اپنے ساتھ کھانا لے کر آتے اور کچھ تو یہاں پر پکانا شروع ہو گئے۔ یہیں پر بیٹھتے، بات چیت کرتے، نماز کے وقت نماز پڑھتے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو ڈاکٹر بھی یہاں موجود تھے۔
آپ کیا ہر روز یہاں آتے تھے؟
ہاں ہر روز۔ ابراہیم صاحب نے فوراً جواب دیا۔
پھر بولے، میں سامنے سے تو نہیں آ سکتا تھا، پہلی بات تو یہ کہ سامنے سے آنے کی جگہ ہی نہیں تھی، اور دوسری بات یہ کہ شروع شروع میں مجھے یہ خدشہ تھا کہ نہ جانے حالات کس طرف چلے جائیں اور ہنگاموں کے ساتھ توڑ پھوڑ شروع ہو جائے۔
کیا ایسا کچھ ہوا؟ میں نے سوال کیا۔
نہیں۔ قطعاً نہیں۔ میں ہر روز صبح پچھلے دروازے سے داخل ہوتا، میں یہاں اکیلا ہوا کرتا تھا، کوئی اور کام کرنے والا نہیں آتا تھا۔ میں ایک کھڑکی تھوڑی سی کھول دیتا تھا اور حالات پر نظر رکھتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمت کر کے میں نے اپنا مین شٹر بھی تھوڑا سا کھولنا شروع کر دیا۔پھر آہستہ آہستہ نئے دوست بننا شروع ہو گئے، میں نے اپنا شٹر مزید کھولا، تاکہ ان نئے دوستوں کو اندر بلا سکوں اور کچھ کھلا پلا سکوں۔
اور پھر مسکرا کر بولے ۔ خوب بکری ہوئی ان دنوں میں۔
خدا کا شکر ہے پاکستانی ہونے کے باعث میری بڑی اچھی تربیت ہوئی ہے، ہم لوگ نام لئے بغیر بھی اپنا مفہوم سمجھا دیتے ہیں۔ ہم وضع دار لوگ ہمیشہ کبھی ادارہ، کبھی اہم شخصیت، کبھی اسٹیبلشمنٹ کا پردہ رکھتے ہیں، مگر نام نہیں لیتے۔ اسی تربیت کو بروئے کار لاتے ہوئے، اور حسنی مبارک صاحب کا نام نہ لیتے ہوئے میں نے ابراہیم صاحب سے سوال کیا کہ جب انقلاب آ گیا، اور پچھلی حکومت چلی گئی تو آپ کیسا محسوس کر رہے تھے؟
اس قدر خوش تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ لگتا تھا کہ دوبارہ زندگی ملی ہے۔ ہر طرف ایک بے پناہ مسرت تھی۔ لوگ گلے ملے رہے تھے، سڑکوں پر ناچ رہے تھے، یوں لگتا تھا کہ ساری عمر کی خوشی ایک ساتھ مل گئی ہو۔
اس موڑ پر آ کر نازک مرحلہ شروع ہونے کو تھا۔ ۲۰۱۱ کا انقلاب تو بمشکل دو سال رہا، اور پھر ایک اور صورتحال پیدا ہوئی تھی، جس کے بارے میں اب بھی بات کرنا آسان نہیں۔ ایک اور بار حکومت بدلی، ایک اہم شخصیت نے پچھلی حکومت کو چلتا کیا اور وہ اہم شخصیت، کہ جس کی تصاویر ہر کونے اور ہر چوک میں آویزاں تھیں، اب بھی برسرِ اقتدار تھی۔
میں نے گلا کھنکارا، اور پوچھا ایک اور کپ اسی مرکب کا مل سکتا ہے؟
جی ضرور۔
ابراہیم بھائی نے آواز لگائی اور ایک اور کپ میرے سامنے نمودار ہو گیا۔ گفتگو مزید آگے نہ چل سکی، اس محفل کی پرواز اب خاتمے کی جانب گامزن تھی، پرواز کی مزید رفعت سے میرے پر جل جاتے۔
آدھی رات ہو چلی تھی، مگر میدان التحریر کی رونق ویسے ہی باقی تھی۔ وہی ہارن، وہی تانگہ، وہی ٹریفک سے بے پرواہ سڑک کو پار کرنے والے من چلے، اور وہی گارڈ جو ہر ایک پر نظر رکھے ہوئے، اپنی شفٹ کے ختم ہونے کے منتظر تھے۔
میرا ہوٹل زيادہ دور نہ تھا، مگر جانے کے دو راستے تھے۔ ایک طرف کے راستے میں مصری قائد اور حریت پسند عمر مکرام کا مجسمہ تھا۔ سر پر ٹوپی، ہاتھ میں کتاب، اور انگشتِ شہادت کو بلند کئے ہوئے یہ وہی عمر مکرام تھے جنہوں نے اٹھارویں صدی کے آخر میں ہونے والی فرانسیسی یلغار، جس کی سربراہی نپولیئن کر رہا تھا، کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، اور ان کی، اور ان کے ساتھیوں کی قیادت، جوانمردی، ہمت اور حب الوطنی کے باعث فرانسیسی فوج کو شکست ہوئی اور ۱۸۰۱ میں اسے پلٹ کر لوٹنا پڑا۔
دوسری جانب کے راستے میں صدرِ مملکت کی مسکراتی اور بلند قامت تصویر اور اس کے نیچے مدح کے کلمات جلی حروف میں درج تھے۔
میں نے عمر مکرام کے راستے کو چنا۔
الشعب یرید اسقاط النظام