میرے ابُّو: میاں خالد محمود (تحریر: سجاد خالد)
باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو / پھر پسر قابلِ میراثِ پدر کیونکر ہو(اقبال)
ہم اپنے والدین کا قرض نہیں اُتار سکتے، کتنے دیوان درمدحِ والدین اور کتنی جلدیں اُس احسانِِ عظیم پر لکھی جائیں، کتنی زندگیاں اُن کی کوششِ ناتمام کے تذکار پر صرف ہوں تب بھی محبت کے اُس بحر کی بیکرانی شرمندہِ ضبطِ ساحل نہ ہو سکےگی۔ یہ کچھ یادیں ۔۔۔ کچھ اشارے ہیں جن کو سمجھنے کے لئے والدین کے احسان کی نعمت سے سرشار دل چاہییں۔ ان کی شرح وہ دِل ہی کر سکتے ہیں۔
میاں خالد محمود، سال پیدائش۔ 1934،َ چنیوٹ۔ سال وفات۔ 2006، کراچی

ابو جنہیں ہم بچپن میں ابّی جی کہتے تھے، تمام عمر میرے خطاطی، تحریر، ڈرائنگ، زبان وادب اور حفظِ مراتب کے اُستاد رہے۔ میرا تعارف تادمِ آخر ایک کہکشانِ اہلِ دل و اہلِ علم وفن سے کرواتے رہے۔ جن میں اُستاد اللہ بخش، مولانا مودودی، غلام محمد (گاما پہلوان رُستمِ زماں)، عبدالرحمٰن چغتائی (مصور)، وی شانتا رام (اداکار،رائٹراورڈائریکٹر)، سہراب مودی (اداکار، ڈائریکٹر)، آغا حشر کاشمیری (انڈین شیکسپئر)، سید محمد عبداللہ (پرنسپل اوریئنٹل کالج)، الطاف حسین حالی، سرسید احمد خان، علامہ اقبال، محمد علی جناح، فاطمہ جناح، حاجرہ مسرور، سعادت حسن منٹو، عبد المجید سالک، مولانا غلام رسول مہر، مولانا امین حسن اصلاحی، علامہ شبلی نعمانی، مولاناعبدالماجد دریاآبادی، علامہ عنایت اللہ مشرقی، ابولکلام آزاد ، مولانا محمد علی جوہر، مجروح سلطان پوری، ساحر لدھیانوی، فیض احمد فیض، ابوالاثرحفیظ جالندھری، شورش کاشمیری ،خمار بارہ بنکوی، اے حمید ، شیرمحمد ابنِ اِنشاء، مشتاق احمد یوسفی، شفیق الرحمٰن، تاج الدین زریں رقم (مؤسس بیٹھک کاتباں لاہور)، عبدالمجید پرویں رقم (موجدِ نستعلیق لاہوری)، خورشید عالم خورشید رقم، محمد صدیق الماس رقم، راکا پینٹر، فیض مجدد آرٹسٹ، سلیم الزماں صدیقی، پطرس، مولانا عطاءاللہ حنیف، شیخ محمد حسن، خواجہ حسن نظامی، امیر خسرو، عمرخیام، عطاءاللہ شاہ بخاری، ابوبکر غزنوی، مولانا احمد علی لاہوری، چارلی چپلن، مارلن برانڈو، الفریڈ ہچکاک، انتھونی کوئن، صوفیہ لورین، کلنٹ ایسٹ وُڈ جیسے لوگ شامل تھے۔
بچپن میں ٹائیفائڈ کے پے در پے حملوں نے ابو کو عمر بھر صحتمند ہونے کا احساس نہ ہونے دیا۔ جوانی میں معدے کے السر نے آ لیا۔ والدین کی ادھیڑ عمرمیں پیدا ہونے والا یہ نادر انسان لڑکپن سے ہی انہیں بوڑھا دیکھ رہا تھا۔ تعلیم اے لیول تک رہی جس کا انہیں بہت احساس تھا۔ سات بہنوں کے دو بھائی اور دونوں میں پندرہ برس کا فاصلہ۔ بڑی بہنوں کی علمی قابلیت کا بھی ذکر کرتے تھے اورخود میں نے بھی انہیں دیکھا تھا۔ جن میں سے ایک میری پھوپھو رضیہ تھیں۔ جو دادا کی سیکرٹری اور سٹینو بھی تھیں۔ میں نے اپنے والد سے زیادہ خوشخط اگر کسی اور انسان کی تحریر اب تک دیکھی ہے وہ رضیہ آپا ہی کی تھی ۔ جو میری پیدائش کے شاید دو برس بعد بہت سے دُکھ جھیل کر بیماری کے ساتھ دنیا سے رُخصت ہو گئیں۔
بڑے بھائی مسعود احمد اُن کے برعکس مجلسی، وسیع المشرب اور نسبتاً زیادہ تعلیم یافتہ تھے۔ اللہ نے میرے تایا کو ابو کی وفات کے بعد بھی زندگی دی جنہیں ہم پنجابی میں چاچا جی کہتے تھے۔ چاچا جی 2012 میں اپنے چھوٹے بھائی، بہنوں، بیٹے اور نواسے کا غم اور بہت سے دُکھ سمیٹ کر تقریباً چورانوے برس کی عمر میں رُخصت ہوئے۔ ابو انہیں پنجابی میں ’بھا جی‘ کہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے پر جان دیتے تھے لیکن ناراض ہونے کاحق بالاتفاق ابو کے پاس رہا۔ وہ اپنے لڑکپن ہی میں کہیں ’اینگری ینگ مین‘ بن گئے تھے یا قحط الرجال کے دُکھ میں آدم بیزار ہو گئے تھے۔ سرمائے، آسائش، دکھاوے اور نفاق کے کُھلے دشمن تھے۔ مسلسل محنت، ایک غیر مختتم جدوجہد، ایک ہمیشہ زندہ رہنے والا درد، ایک سچا، سیدھا اور کھرا انسان جسے پہچاننے کے لئے بڑے فہم کی ضرورت تھی لیکن وہ فہم ناپید ہے۔۔۔ وہ سمجھ عنقا ہے۔۔۔ وہ آنکھ اس تہذیب میں کب کی بند ہے۔۔۔ کب کی بند۔۔
میں چالیس برس کی عمر تک اس آغوش میں پروان چڑھا۔ میرے ہرخاکے میں انہی کے خطوط، میری ہر تصویر میں وہی نقوش، میرے ہر قدم میں انہی کی تحریک۔
کبھی شاہد احمد دہلوی کی ’اُجڑا دیار‘، کبھی ’ساحل‘ میں حکیم محمد سعید شہید (ہمدرد یونیورسٹی کراچی) پرخالد جامعی کا مضمون، کبھی مشتاق احمد یوسفی کی ’چراغ تلے‘، ’زرگذشت‘ اور ’آبِ گم‘، کبھی قدرت اللہ شہاب کی ’شہاب نامہ‘، کبھی جاوید احمد غامدی کی ’مثنوی خیال وخامہ‘، کبھی ابنِ انشاء کی ’اردو کی آخری کتاب‘، کبھی ہفت روزہ الاعتصام، کبھی مولانا ابولکلام کا البلاغ اور الہلال، کبھی جوہر کا کامریڈ، کبھی عاصی کرنالی، کبھی عبدالحلیم شرر، پڑھ کر سناتے اور کبھی کہتے کہ یہ ضرور پڑھنا۔
وہ سارا دن ادب پاروں میں سے اعلٰی ترین حصوں کو نشان زد کرتے، پیروں کے پیرے، صفحوں کے صفحے میرے گھر پہنچنے تک دودھ میں سے مکھن کی طرح نکال رکھتے۔ شام کو میرے گھر آنے پر مجھ سے کہتے ’یار کپڑے بدل لو‘ اور امی سے کہتے ’اس کا کھانا یہیں میرے پاس رکھ دو‘۔ تو پھر ایک مختصر سی تمہید کے بعد وہ آبِ زم زم میں دُھلی ہوئی اُردو، شفاف اور مترنم آواز، ٹھہرے ہوئے پختہ لہجے میں مناسب ترین وقفوں کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے۔ یہ چشمہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں میری استعداد کی رعایت سے تھم جاتا۔ درمیان میں ہم دونوں کسی جملے، کسی استعارے، کسی مصرعے پر والہانہ داد دیتے یا ابو کسی بات کا پس منظر بیان کرتے تاکہ میرا تجربہ جس حد تک ممکن ہو مکمل کر سکیں۔
تقسیمِ ہند سے پہلے دادا کی سرکاری ملازمت کے دوران گھر میں خدمت گاروں کے ساتھ ابو کی رازداری رہتی۔ یہ رازداری فیروزپور میں گھر کے پیچھے جنگل میں گھُسنے، وہاں سے پرندے پکڑنے اورسانپوں کا مقابلہ کرنے کے لئے نیولے کا بچہ ڈھونڈ کر اُسے اپنے ہی گھر میں چھُپا کر پالنے سے متعلق تھی۔ باورچی سے سلام دُعا اپنے پالتو جانورروں کے لئے دودھ اور دوسری خوراک کی چوری کے لئے رکھنی پڑی۔ کوچوان اور ڈرائیور کے طور پر جان محمد اسی گھر میں رہے تھے۔ جان محمد نے اس گھر میں ملازمت بھی کی اور تعلیم بھی پائی۔ یہاں سے نوکری ختم ہوئی تو سرکاری سکول میں ٹیچر بھرتی ہو گئے اور ہیڈ ماسٹر کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ جان محمد میرے لڑکپن تک باقاعدگی سے ابو کو خط لکھتے رہے اور ابو پوری محبت اور ذمہ داری سے جواب دیتے رہے۔ ابو کے بچپن کے دوستوں میں مُلا بشیر بھی تھے جو علمی کُتب خانہ لاہور میں ملازمت کرتے تھے اور اچھرہ میں رہتے تھے۔ یہ دوستی ابو کی زندگی کے ساتھ ختم ہوئی۔ ابو اپنی کسی خاص کتاب کی جلد کی مرمت کے لئے ملا بشیر سے کہتے اور وہ بخوشی اس خواہش کو پورا کرتے۔
آدم بیزاری نے جانوروں سے محبت کی جو پنیری لگائی تھی وہ جوانی میں بےحد کم وسائل کے باوجود تناور درخت بن گئی تھی۔ اس شوق میں وہ چڑیا گھر چلے جاتے اور انگریز کیوریٹر سے دوستی ہو گئی۔ پھر اُن کے معاون کے طور پر کچھ عرصہ اعزازی خدمت بھی سرانجام دی۔ جانوروں کو اُن کے ناموں سے یاد کرتے۔ اُن کے ماں باپ کے نام بھی یاد تھے۔ بالآخر جانوروں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور اپنے حالات کے پیشِ نظر اس خدمت کو خیرباد کہہ دیا۔
ویسے تو تمام عمر ابو کے پاس کوئی نہ کوئی جانور رہا جس کی خدمت اور تربیت جاری رہی (آپ مجھے پہلے سے اس میں شامل کر چکے ہیں)۔ لیکن میرے بچپن کا ایک زمانہ وہ بھی تھا جب گھر ایک چھوٹے سے چڑیا گھر کا منظر پیش کرتا تھا۔ ٹولنگٹن مارکیٹ سے خریدی گئی سُرخیں، فنچز اور آسٹریلیئن طوطے، بڑے مرتبان میں ننھی پریوں جیسی چمکتی، بل کھاتی مچھلیاں، اپنے ہی گھر میں امرود کے درخت سے پکڑا گیا میاں مٹھو، پندرہ بیس دیسی مرغیاں اور کچھ ولائتی چوزے، انہی مرغیوں کی آغوش میں بطخ کے انڈوں سے نکلے ہوئے سنہرے سے چوزے، ایک بکرا (ببلُو)، ایک فاکس ٹیریئر کتیا (ٹومی)، لکّا کبوتروں کے دو جوڑے اور چار پانچ خرگوش۔ اِن میں سے جن جانوروں کو میں نے ابو کی ٹریننگ کے بعد حیرت انگیز کام کرتے دیکھا تھا، اُن میں ٹومی، ببلُو، مٹھو اور ولائتی مرغا کمال کی حدوں کو چھُو رہے تھے۔
یہ سب جانور اپنے ناموں سے پکارے جاتے۔ ان کے صبح اُٹھنے، دوپہر اور رات کو سونے، کھانے اور رفعِ حاجات کے اوقات طے تھے۔ ان کی حجامت کی تاریخیں کیلنڈر پر مارک ہوتیں۔ گھر کے کون سے حصوں میں کس جانور کو کس وقت آنے کی اجازت ہے، یہ طے تھا۔ خلاف ورزی پر سزائیں اورعمل کرنے پر غیر معمولی پیار ملتا تھا۔ ایک خاص وقت گزرنے کے بعد کسی جانور کو قید نہیں رکھا جاتا تھا اور نہ ہی باندھا جاتا تھا۔ میں نے ایک بار سُرخوں اور آسٹریلیئن طوطوں کو ابو کی جیل سے آزاد کروا کر دیکھ لیا تھا۔ پہلے تو وہ اُڑ کے ہمارے گھر کے دو درختوں پر جا بیٹھے پھر دو ایک گھنٹے کے لئے غائب ہو گئے اور شام کو واپس آکر ڈنر کا تقاضا کرنے لگے۔ اسی طرح ٹامی کو دو بارانتہائی دور رہائش پذیر مختلف دوستوں کے حوالے کیا گیا لیکن وہ بیس پچیس کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پورے شہر کو چیرتی ہوئی ، راستے کے شیر جیسے کتوں کے دانتوں اور پنجوں سے انتہائی زخمی حالت میں منزلِ مراد پر بھوکی پیاسی پہنچی۔ دوسری بار ایسا ہونے پر گھر آئی اور کچھ دِن کے بعد ہم سب کو دیکھتے دیکھتے دُنیا سے رُخصت ہو گئی۔ اُس کے دو بچے تھے ایک میں نے اپنے کلاس فیلو جاوید کو دیا تھا اور دوسرا ابو نے ماسٹر فریاد (ابو کے شاگرد اور ہمارے اُستاد) کو دیا تھا۔ یہ دونوں بچے اپنی ماں سے ملوانے لائے جاتے تھے۔
بلیوں کی سُنیے، جو ہماری مرغیوں، دوسرے پرندوں اور خرگوشوں کے شکار کو آتیں تو ہمارے مرغے کے غضب کا شکار ہو کر نشانِ عبرت بنی پھرتیں۔ ہماری فضائیہ کا ولایتی چیف مرغا جب انہیں بھگا کر فاتحانہ انداز میں واپس لوٹتا تو اُس کی چونچ اور پنجوں میں بلی کی پیٹھ کے اچھے خاصے بال موجود ہوتے جو وہ ہمارے سامنے پہنچ کر فاتحانہ انداز میں جھاڑ دیتا۔ یہی حال ببلو (بکرا) کا تھا۔ ببلو کے اندر بھی مارشل سپرٹ پیدا کر دی گئی تھی۔ کُتیا کی غیرموجودگی میں زمینی افواج کا سربراہ وہی ہوتا۔
ابو کے پسندیدہ مضامین میں شکاریات اور وائلڈ لائف کے ساتھ ساتھ جانوروں کی تربیت کے لئے چھپنے والا لٹریچر بھی تھا۔ کتوں اورگھوڑوں کے انسائکلوپیڈیاز، جِم کاربٹ کی سُندربن کے آدم خوروں پر کتاب، ماہنامہ حکایت میں شکاریات پر شائع ہونے والے مضامین اور نیشنل جیوگرافک، اینیماکس یا اینیمل پلینٹ پر نشر ہونے والے چوبیس گھنٹے کے پروگرام اُن کی دُنیا تھے۔ ان کے علاوہ میں ابو کے لئے برٹش کونسل اور امیرکن سنٹر لائبریری سے جانوروں سے متعلق ویڈیو ٹیپس بھی لا کر دیتا تھا جسے وہ خود پر احسان تصور کرتے تھے۔ مجھے گھوڑوں اور کُتوں کی مختلف نسلوں کے نام اور خوبیاں یاد ہو گئے تھے۔
وہ جوانی میں ائرفورس میں بھرتی ہونے کا کوئی ابتدائی امتحان پاس کر آئے تھے جسے ہماری دادی اماں کی اجازت نہ ملنے پر چھوڑنا پڑا۔ اس مایوسی نے ایک نئے شوق کی بنیاد ڈال دی اور وہ تھا طیاروں کی اقسام اور نام یاد رکھنے کا شوق جو مجھے بھی دو سال کی عمر میں رٹوا دئے۔ اسی طرح گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے مشہور برانڈز اور ماڈلز کے نام بھی لکھ کر رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ائر فورس، بری اور بحری افواج کے تمام عہدے بھی یاد کئے اور مجھے بھی کروائے۔ 23 مارچ ہو، 14 اگست ہو یا 6 ستمبر، ٹی وی پر افواجِ پاکستان کی پریڈ اور اسلحے کی نمائش بیحد دلچسپی سے دیکھتے۔ نیوز کاسٹرز اور مبصرین میں اس حوالے سے لئیق احمد، اظہر لودھی اور ابصار عبدالعلی، شائستہ زید، ادریس احمد اور خالد حمید کو پسند کرتے تھے۔ کچھ نیوز کاسٹرز کے نام میرے ذہن سے محو ہو چکے ہیں۔
نوجوانی میں والی بال کے اچھے کھلاڑی رہے تھے۔ کرکٹ اور ہاکی کو دیکھنے کی حد تک پسند کرتے تھے۔ ٹی وی پر میچ دیکھتے ہوئے شدید ردِ عمل کا مظاہرہ کرتے اور اپنے ہاتھ سے، اپنی نوٹ بُک پر سکور بورڈ کو ایڈٹ کرتے رہتے تھے۔ پاکستانی ٹیم کی بُری کارکردگی پر فارسی، اُردو اور پنجابی کے ملامتی اشعار لکھ لکھ کر کاغذ بھر دیتے۔
ہم قافیہ، ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کے گروہ بنانا اور اُن کو یاد کر کے لکھنا اور پھر مجھے سُنانا اُن کا محبوب مشغلہ تھا۔ اسی طرح انڈیا اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ذاتوں کی فہرستیں بنانا، ایک ہی لفظ کے مختلف زبانوں میں متبادل ڈھونڈنا اور لکھ رکھنا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کون سا مشہور آدمی کِس کا بیٹا، بھائی یا باپ تھا، کِس پوزیشن یا عہدے پر رہا، کس حال میں رُخصت ہؤا ۔۔۔ یہ خلاصے اُن کی نوکِ زبان پر دھرے تھے۔ آپ نام لیں اور ایک دلچسپ کہانی سُن لیں۔
ایک رجسٹر تھا جو بجائے خود فن پارہ تھا۔ اس میں اُن کے پسندیدہ شعراء اور ادیبوں کی تحریریں اُردو، فارسی اور انگریزی میں کٹی ہوئی نِب کے ساتھ لکھی ہوتیں۔ کبھی ملا تو اُس کی تصاویر دکھاؤں گا۔ اسی رجسٹر میں اخباروں کے تراشے جن میں اُن کے ہیروز اور ہیروئینوں کی تصویریں نفاست سے کاٹ کر چسپاں کی گئی تھیں اور اُن کے ساتھ ان شخصیات کی کوئی بات، موزوں اشعار یا کوٹیشنز خوشخط تحریر ہوتیں۔
گانے والوں میں اختری بائی فیض آبادی، کے ایل سہگل، طلعت محمود (جو شاید مولانا عبدالماجد دریاآبادی کے بھانجے بھی تھے)، ہیمنت کمار، مناڈے، محمد رفیع، نور جہاں، لتا منگیشکر، آشا بھوسلے، شمشاد بیگم، ثریا، امانت علی خان، حبیب ولی محمد، ناشاد وغیرہم شامل تھے۔ خود کچھ عرصہ ریڈیو پاکستان پر خبریں پڑھنے کا شوق بھی پورا کیا اور اپنی متلون مزاجی یا کسی کی افسری کے ہاتھوں مجبور ہو کر جلد ہی چھوڑ آئے۔ وہ نیم کلاسیکی، غزل، ترانہ، گیت، قوالی اور نعت پسند کرتے تھے۔ بھجن آ جاتا تو گانے والے پر منحصر تھا کہ وہ سُننے پر مجبور ہوں ورنہ بند کروا دیتے۔ اسی طرح انڈیا کا کوئی ترانہ یا قومی نوعیت کا گیت بھی نفرت سے دیکھتے تھے۔ وہ نیشنلسٹ بھی تھے اور کچھ لوگوں کو سرحد سے پار چاہنے پر مجبور بھی۔ ابوالکلام کی سیاست سے اختلاف کے باوجود غبارِ خاطر، الہلال اور تذکرہ کو پسند کرتے تھے۔ ہندو اور کانگریس دُشمنی کہیں اندر دبی ہوئی تھی جس کا اظہار تُند لہجے میں کر تے۔
اشراق، الاعتصام، ہیرلڈ، نیوزویک اور انڈین فلم انڈسٹری سے متعلق رسالے (شمع وغیرہ) تھے جن کے نام میرے ذہن میں شاید زیادہ نقش نہ ہو سکے۔ فلمی رسالے لا کر دینے کی مقدس قومی ذمہ داری بھاجی ادا کرتے تھے۔ بھاجی اور ابو ہالی وڈ، انڈین، یوروپئن اور پاکستانی فلم انڈسٹری کے چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیاز تھے۔
دو کتابیں ساری زندگی اُن کے ساتھ رہیں۔ پہلی اُردو کی لغات اور دوسری انگریزی کی ڈکشنری۔ اُردو کی لغات میں وہ نوراللغات اور کشور اللغات کے ساتھ کتابستان کی اُردو لغات کو پسند کرتے تھے۔ فرہنگِ آصفیہ ہمارے پاس نہیں تھی۔ انگریزی کی ڈکشنری میں انگریزی سے انگریزی اور اُردو کے سلسلے میں وہ جناب بشیر احمد قریشی کی مرتب کی ہوئی کتابستان کی ڈکشنری کو تمام مقامی ڈکشنریوں پر ترجیح دیتے تھے۔ بشیر احمد قریشی پرائمری یا ہائی سکول میں میرے ابو کے اُستاد رہے تھے اس لئے وہ اُن کی لیاقت کے بیحد قائل تھے۔ فیروزاللغات کا ایک درمیانہ ایڈیشن بھی گھر میں تھا جسے غصے کی حالت میں ’فراڈ اللغات‘ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اس میں الفاظ کے پورے کے پورے گروہ غائب تھے اور یہ بات مایوس کُن تھی۔ اِن ڈکشنریوں میں سلیقے سے کاٹے ہوئے کاغذ کے پرزوں پر ابو وہ الفاظ و معانی لکھ کر رکھتے تھے جنہیں وہ سیکھنا یا یاد کرنا چاہتے تھے۔ کاغذ کے یہ پرزے ہم بچوں کی ضائع شدہ کاپیوں سے لیے جاتے تھے یا پھر اُن کی سگریٹ کی ڈبیا سے نکلنے والی پنی کی پشت پر خوشخط لکھتے جو لغات میں جیسے اِستری کر کے رکھی ہوئی ملتی۔ یہ ٹکڑے بجائے خود فن پارے ہوتے تھے جن کی قدر سے وہ خود کچھ بے نیاز تھے لیکن اُن پر لکھے ہوئے لفظ انہیں عزیز تر تھے۔
درویش صفت نابغوں میں ڈاکٹر امیر الدین اور مولانا حسرت موہانی اُن کے رول ماڈل رہے جبکہ پسندیدہ شخصیات میں میرے دادا شیخ عبدالرحیم علیگ ایڈووکیٹ جو ایم اے او کالج علی گڑھ کی 1910 سے 1914 کی ہر دلعزیز شخصیت، سر اسٹیچی ہال یونین کے سیکرٹری جنرل اور مصنف سفرنامہ ’ پیرِ حرم اور زائرِ حرم‘ تھے۔
اسی طرح دادا کے دوستوں میں سے شیر محمد سید (دینی محقق/بیوروکریٹ)، جسٹس ریٹائرڈ غلام علی (دینی محقق ، قانون دان، جماعتِ اسلامی)، مولوی دوست محمد (ہیڈ ماسٹر اسلامیہ سکول چنیوٹ) کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے۔ سعادت حسن منٹو اپنی بیباکی اور انتظار حسین اپنی زبان اور نازکی کی وجہ سے پسند رہے تھے۔
مولانا مودودی اور عنایت اللہ مشرقی اچھرہ میں ابو سے قریب رہتے تھے۔ ابو مشرقی صاحب کو بہت پسند کرتے تھے۔ صبح مولانا مودودی کا خانساماں، ابو اور عنایت اللہ مشرقی ایک ہی سبزی والے اور ایک ہی قصائی سے خریداری کرتے۔ مولانا مودودی کے گھر میں ان دنوں ٹیلی فون کی سہولت موجود تھی اور ایمرجنسی میں انہی کے گھر پہلے پیغام پہنچتا تھا۔ ابو کو جماعتِ اسلامی سے شدید نفرت تھی۔ مولانا مودودی انہیں کبھی پسند نہ ائے۔ میں نے جب اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت اختیار کی تو انہیں بہت دکھ پہنچا۔ مولانا کی کتابیں میرے پاس دیکھ کر ایسا ایسا کاٹ دار جملہ کہتے کہ خدا کی پناہ۔ چند برس بعد جاوید احمد غامدی صاحب سے میری واقفیت ہوئی اور میں نے بتایا کہ اب مولانا امین احسن اصلاحی کے درسِ حدیث میں شریک ہوتا ہوں تو بہت خوش ہوئے۔
شورش اور منٹو جیسے باغی ابو کو پسند کرتے تھے۔ منٹو کی وفات کے بعد ان کے گھر کے لیے دوستوں سے چندہ جمع کر کے بھی پہنچایا تھا۔ مولانا صلاح الدین احمد، سعید لخت سے دوستی تھی۔ میرے لیے رسالہ تعلیم و تربیت اور ہمدرد کا نونہال جاری کروا رکھا تھا۔
سادہ ترین اور سستے کپڑے، بیحد کم خوراک، انتہائی کم خرچ اور کم آمیز۔ اپنے کپڑے استری نہ کرواتے بس انہیں سوکھنے کے بعد قرینے سے تہہ کر کے تکیے کے نیچے رکھ لیتے۔ لوہے کی تار والی ٹوکری اُن کی سائیکل کے ہینڈل سے جُڑی تھی، پچھلے پہیے پر ایک کیریئر جس کے ساتھ صاف سُتھری رسی یا سیبے کا ایک ٹکڑا کمال سلیقے سے بندھا ہؤا تھا۔ اسی پہئیے پر گول تالا لگا ہوا تھا۔ ہینڈل پر ایک گھنٹی بھی تھی جو پورے سُر میں رہتی۔ یہ سائیکل غالباً 1970 میں خریدی گئی تھی جسے وہ نفاست کا نمونہ بنائے رکھتے۔
ہروہ سہولت جس پراُن کی نظر میں زیادہ خرچ آتا ہو قابلِ نفرت تھی اور ہرضروری چیز جس پر معمولی سا خرچ ہو جائے اُن کے لئے قیمتی ہو جاتی۔ وہ سب کچھ سنبھال کر رکھتے تھے۔ سگریٹ کی ڈبیاں اوراُن کے اندر کی پنیاں اور گتے، ماچس کی ڈبیاں اور جلی ہوئی تیلیاں، چلتے چلتے بند ہو جانے والے بال پوائنٹ اور جام ہوئے فاؤنٹین پین، خاکی، اخباری اور مومی لفافے، اخبار، لکڑی اوراینٹوں کے ٹکڑے، ریت، بجری، سیمنٹ جو بھی بچ جاتا اُسے ایسے سلیقے سے باندھ لیتے اور ایسی جگہ محفوظ کرتے کہ وقت آنے پر کہیں باہر جانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ لکڑی کا کام ہو یا بجلی کا، مستری کا کام ہو یا مزدورکا، پلمبر کا کام ہو یا کتابیں جلد کرنے کا اُن کے پاس ہر کام کے بنیادی اواز الگ الگ ٹول باکس میں صاف سُتھرا مل جاتا۔ ایسا لگتا تھا اُن کے زیرِتصرف ہر چیز اُن سے خوش ہے اور اُن کے بغیر رُل جائے گی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سنبھالی ہوئی چیزوں کا کیا کرتے تھے تو میں کہوں گا کہ غربت کے ساتھ اگر علم اور کفایت شعاری ہو تو غربت خوبصورتی کے ساتھ کٹ جاتی ہے اور تنگ دستی کے ساتھ اگر جہالت اور بے سلیقگی ہو تو دُنیا میں جہنم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ معروف ادیب میرا جی کے بارے میں جب پڑھا کہ وہ لوہے کے دو گولے ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے جو انہیں سڑک پر پڑے ملے تھے تو مجھے ابو بہت یاد آئے۔ میرا جی کی کی شکل ابو سے کچھ کچھ ملتی تھی۔
میں چھوٹا سا تھا تو مجھ سے مرغی ذبح کروائی۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے بچپن میں مرغی مسجد میں لے جا کر مولوی صاحب سے ذبح کروائی جاتی تھی اور ظہر کی نماز کے بعد مسجد سے ایک لڑکا خالی پلیٹ لے کر دروازہ کھٹکھٹاتا تھا کہ سالن دے دیں۔ انہیں یہ بات پسند نہیں تھی کہ مسلمان نکاح اور جنازے اور دعائے خیر کے لیے مولوی صاحب کے محتاج ہوں۔
ابو کے پاس سفید اور آسمانی نیلے رنگ کا لیمبریٹا سکوٹر تھا جو دو ہزار تین تک اس طرح رہا جیسے پیکنگ سے نکالا ہو۔ میں چھتیس برس کا ہو چکا تھا لیکن وہ ابھی چمچما رہا تھا۔ جیسے عمر صرف میری بڑھ رہی تھی۔ ایک پنکچر تھا اور وہ بھی سٹپنی میں۔ موسم ابر آلود ہونے کی خبر سنتے ہی اضافی کپڑا چڑھا دیتے اور خراب سڑک کی بجائے صاف اور لمبا راستہ اختیار کرتے۔ جتنا وقت اس پر سوار ہوتے، اس سے زیادہ وقت واپس آ کر اس کی صفائی پر لگا دیتے۔ روزمرہ کے ہر کام کے لیے ایگل سائیکل استعمال ہوتی جس کے ہینڈل پر تار سے بنی ٹوکری لگی تھی اور فریم پر میرے لیے چھوٹی گدی لگوائی گئی تھی۔ پچھلے مڈ گارڈ کے اوپر کیرئر اور اور اس کے نیچے گول تالا لگا ہؤا تھا۔
ایک بار امی ابو کے ساتھ ہم پانچ بہن بھائی اس پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے تو ایک گورے نے تصویر لینے کے لیے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا۔ ابو نے انگریزی میں پوچھا کہ کیا کرو گے تصویر کا۔ کہنے لگا کہ میں اٹلی میں لیمبریٹا کمپنی کا اینجینئر ہوں۔ پاکستان میں ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے آیا تھا۔ سکوٹر دس برس چلنے کے بعد اس حالت میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ یاد رہے کہ لیمبریٹا کی سٹپنی کو لٹا کر فٹ کیا گیا تھا اور اس پر دو بچوں کے لیے آرام دہ گدی لگوائی گئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ سکوٹر کے انجن کا کور کس احترام سے اتارا جاتا تھا اور کس احتیاط سے صاف جگہ پر رکھا جاتا تھا کہ خراش کا احتمال تک نہ رہے۔
اُنہیں ابتدائی عمر سے مولوی سے کچھ بیرسا ہو گیا تھا۔ جو حضرت سپارہ پڑھانے آتے تھے وہ سبق یاد نہ ہو سکنے پرانگلیوں میں پنسل کو پرو کر ہاتھ یوں دبایا کرتے تھے کہ دینی تعلیم اس نازک اور بیمار بچے کے لئے اذیت بن گئی تھی۔ دادا ابو کچھ سخت اساتذہ کو پسند کرتے تھے اور اُن کا علمی رعب بھی اس قدر تھا کہ چھوٹے بیٹے میں یہ جراءت کبھی نہ پیدا ہو سکی کہ علی الاعلان بغاوت کر دیتا۔ میں ذرا بڑا ہوا تو قربانی کا جانور میرے ہاتھ سے ذبح کروایا۔ جانور کی کھال اُتارنا سکھایا، ہڈیوں، پٹھوں اور جوڑوں کو میرے سامنے تدریسی انداز میں کاٹنے کا بار ہا مظاہرہ کیا لیکن جو مجھے نہ سیکھنا تھا نہ سیکھ سکا۔
سائیکل، سکوٹر اور موٹرسائیکل کی دیکھ بھال اور صفائی کا فن اُن پر ختم تھا۔ اپنی جان سے زیادہ اپنے پالتو جانوروں، اوزاروں، سٹیشنری، کتابوں اور سواری کا خیال رکھنے والی بات محاورتاً نہیں لکھی، یہ سب کچھ تو آنکھوں دیکھا حال ہے اور وہ بھی زندگی بھر کا۔ وہ بہت کم گالی دیتے تھے لیکن کبھی بے اختیار غصے میں کسی کو حرام الدہر، پرانی لعنت اور سؤر وغیرہ کی اولاد کہہ ڈالتے۔ زندگی میں ایک آدھ بار قدرے ناقابلِ اشاعت گالی بھی اُن کی زبان سے سُنی جس سے اُن کے زمانے میں فارسی کے غلبے کا اندازہ ہوتا تھا۔ میں نے بی اے میں فارسی زبان رکھی تو میرا ٹیسٹ لیا جس میں مجھے فیل کر دیا۔ شاید 100 میں سے بیس نمبر دئیے۔ جب بی اے کا نتیجہ آیا تو میرے نمبر سو 100 میں سے اسّی 80 تھے۔ میں نے نمبر بتائے تو افسوس سے کہنے لگے اب تو میرا اس نظامِ تعلیم سے بالکل اعتبار اُٹھ گیا ہے۔
تعلق میں وہ مان لینے یا منوا لینے کی بنیاد پر چلتے تھے۔ اگر انہوں نے کسی کی فضیلت کو دِل سے تسلیم کر لیا تو اُس پر جان بھی نثار اور اگر نہیں مانا تو بات کرنا بھی ضروری نہ سمجھتے تھے۔ جن لوگوں کو کبھی کم علم یا کم فہم سمجھ کراپنا راستہ الگ کر لیا، جب وہ ابو کے علم کے قائل ہو گئے اور اپنے عمل سے گواہی دیتے تو اُن کی بھی خدمت کرنے لگ جاتے۔ وہ سچے، سادہ، غریب اور صاحبِِ علم وفن پر فدا ہو جاتے تھے۔ ڈائری لکھنے کی عادت پرانی تھی لیکن اُسے پرائیویٹ رکھنے کے لئے انگریزی میں لکھتے۔ جب امی یا ان کے رشتہ داروں کے خلاف مجھ سے برملا کچھ کہنا ہوتا تو اُن کی موجودگی میں برجستہ انگریزی میں بات کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ امی یا کوئی بھی پرانا شکار خود ہی سمجھ جاتا کہ بات اُسی سے متعلق ہے اور ہے بھی عیب جوئی۔ اپنا مافی الضمیر لکھنے اورکہنے پراس درجے کا کمال تھا کہ پڑھنے والا اور سُننے والا وہ الفاظ، وہ لہجہ اور وہ جذبہ کبھی نہ بھُلا پاتا۔ اسی طرح اُن کی غصیلی طبیعت سے مزاح کی اُمید عموماً کسی کو نہیں ہوتی تھی لیکن جب کوئی اُن کے غضب کا نشانہ بنتا تو اُن کی زبان و قلم سے برآمد ہونے والا مواد طعن وتشنیع، طنزومزاح اور ہجو واحتجاج کا شاہ پارہ بن جاتا۔
جن لوگوں سے دادا کی نسبت سے ابو کا رابطہ رہا ان میں سے اشفاق احمد (جنہیں ہمارے گھر میں پیار سے شقّو پکارا جاتا تھا)، اشفاق صاحب کے بڑے بھائی اور درویش صفت آفتاب احمد (جو میرے دادا کے اسسٹنٹ یا منشی تھے اور ابو اُن کو اشفاق احمد کے برخلاف بہت پسند کرتے تھے) اشفاق احمد کی والدہ، مولانا غلام رسول مہر، مولانا عبدالمجید سالک، مولانا ظفرعلی خان، مولانا عطاءاللہ حنیف بھوجیانی، مولانا چراغ حسن حسرت، ابوالاثر حفیظ جالندھری، مولانا ابوالاعلٰی مودودی، مولانا امین احسن اصلاحی، ڈاکٹر سید محمد عبداللہ، شورش کاشمیری، مولانا متین ہاشمی، قاضی عبدالباقی (مولانا سلیمان منصورپوری کے پوتے)، نواب سمسام الدین فیروز (دادا جان کے علی گڑھ کے کالج فیلو)، اللہ بخش یوسفی (مدیر مجلہ سرحد – دادا کے علی گڑھ کے کالج فیلو)، ڈاکٹر مسعود (معروف ہومیو پیتھ)، علامہ عنایت اللہ مشرقی، کمال احمد (اداکار)، شیر محمد سید، جسٹس غلام علی اور ڈاکٹر امیر الدین جیسے ستارے تھے۔
ایسے لوگ جن کا ذکر وہ کبھی کبھی کرتے یا جنہیں پسند کرتے تھے یا تو بچپن میں دادا سے ملے تھے یا تقسیمِ ہند کے بعد اُن سے بالمشافہ ملاقات نہ ہو سکی۔ اُن میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، بی اماں، غلام حُسین (مدیر کامریڈ)، ابوالکلام آزاد، شیخ محمد عبداللہ (صدر آزاد کشمیر)، خوشی محمد ناظر (کشمیری شاعراورسیاستدان)، بلراج سانی (ایکٹر اور سماجی کارکن)، منشی پریم چند، رتن ناتھ سرشار، آغا حشر کاشمیری، سرسید احمد خان، محمد مارماڈیوک پکتھال، عبداللہ یوسف علی، نواب بہادر یار جنگ، نواب صدیق حسن خان، مولانا عبدالماجد دریآبادی، غلام احمد پرویز، سر عبدالقادر (مدیر مخزن) اور علامہ محمد اقبال کے نام مجھے یاد رہ گئے۔
میں نے تمام عمر انہیں معدے کی تکلیف میں مبتلاء پایا۔ دو ہزار تین میں اپنی بڑی ہمشیرہ کی میّت کے ساتھ چل رہے تھے، قبرستان میں پاؤں ٹیڑھا پڑا اور معمولی فریکچر ہو گیا۔ کسی کو اندازہ نہیں ہوا۔ ایک ماہ بعد میں نے زبردستی ایکسرے کروایا تو علم ہوا۔ وہ اپنی تکلیف بتانے کے قائل نہیں تھے۔ چند ماہ بعد کھانسی شروع ہوئی۔ شادباغ میں نوجوان ڈاکٹر بلال غریب دوست اور دبنگ آدمی تھا۔ ابو اسی سے دوا لیتے لیکن مرض بڑھتا رہا۔ ایک سال گزر گیا۔ کراچی میں چھوٹے بھائی کے گھر چند دنوں کے لیے رہنے گئے تو وہاں طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ ٹیسٹ کروائے گئے تو سینے کا سرطان نکلا۔ اس تشخیص کے بعد علاج شروع ہوا لیکن مزید ایک ڈیڑھ برس میں وہ بے انتہا تکلیفیں سہتے ہوئے 2006 میں رخصت ہو گئے۔
ویسے تو وہ ہر روز، ہر شب یاد آتے ہیں لیکن عید پر ان کی کمی کچھ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ میں آج بھی ان کے تراشے ہوئے قلم سے ان کی دی ہوئی دوات میں بنی روشنائی سے لکھتا ہوں۔۔۔۔۔۔ میاں خالد محمود
تم میں اپنے آپ کو دیکھا، خود میں تم کو پایا / آگے جا کر دل نے سوچا، تو نے دھوکا کھایا / ایک کتاب کی پیشانی پر عکس تمہارا دیکھا / ایک مزار کی لوح پہ میں نے اپنے نام کو پایا
سجاد خالد، جون 2022، بروز عید الاضحیٰ


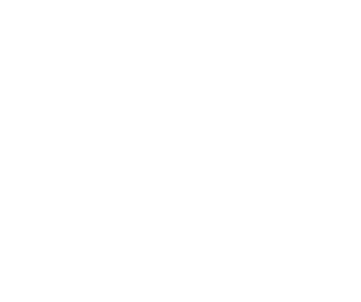
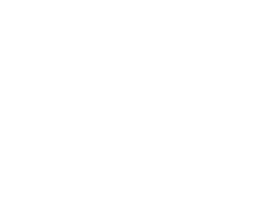

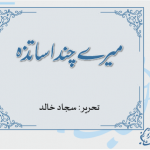

اسے خاکہ نگاری کہیے یا خونِ رگِ جاں سے کی گئی یادوں کی آبیاری۔ کسی بھی بڑے کی یاد میں تمام بڑوں کی یاد کے عکس ہوتے ہیں۔ بہت خوب سجاد بھائی۔ اللہ آپ کے والد اور تمام گزرے ہوئے بزرگوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ آمین۔