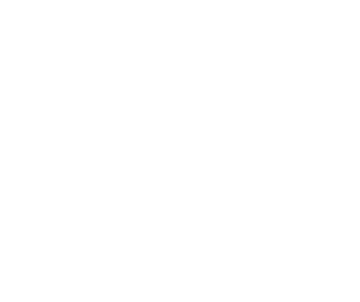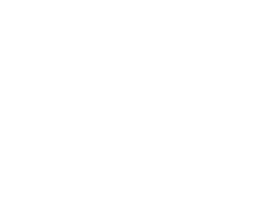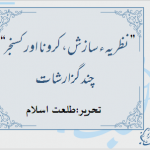مرگِ امید کا نوحہ، انتظار حسین کے اوائلی افسانے: محمد عمر میمن (ترجمہ: اسد فاطمی)
آج پرانبساط شور و غل[1] کا یہ وقت، انتظار حسین کے ناول ’بستی‘ پر 34 برس کی خاموشی کے بعد، بدیر سہی، لیکن ان کے ابتدائی کاموں پر بات کرنے کے لیے شاید بہت مناسب ہوگا۔ ’بستی‘ کو کسی خلا میں نہیں لکھا گیا۔ یہ درحقیقت مصنف کے شروع کے ضخیم ادبی ترکے کے بہت سے تانوں بانوں کی جمع بندی اور ماحصل ہے۔ یہاں میں ان کی افسانوی کاوش کے ایک حصے کی اپنی سی ایک قرأت آپ کو پیش کرنا چاہوں گا۔
1963 میں لکھے گئے ایک مضمون ’’ ہمارے عہد کا ادب ‘‘ میں حسین نے خود اپنی اور قیام پاکستان کے بعد کے عشرے کی کچھ دیگر ادیبوں کی سوچ پر چھائی ہوئی رجائیت اور امید کی عمومی فضا کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس عشرے کی تحاریر میں وہ بٹوارے کی بابت مجموعی طور پر تین مختلف رویوں کی نشاندہی کرتے ہیں: ترقی پسندوں کا ایک پیچیدہ صورتحال کو سادگی سے دیکھنے کا رویہ، جنہوں نے اس واقعے کو ہیچ جانا اور انسانیت کے نام پر گروہی قتل عام کو رد کیا؛ سعادت حسن منٹو جیسے لکھاری کا رویہ، جنہوں نے ایک بحرانی گھڑی میں انسانی امکان کی حدوں کو دریافت کیا؛ اور مختار صدیقی، قیوم نظر اور یوسف ظفر جیسے شعراء کا رویہ، جنہوں نے سوچے سمجھے انداز میں اس واقعے کا ذکر کرنے سے گریز کیا کہ ادب اپنے مقام سے گر کر صحافت بن کے نہ رہ جائے۔
ایک ابھی نیا نیا رویہ بھی تھا جو ذرا متردد لیکن واضح انداز میں ظاہر ہو رہا تھا۔ اس رویے نے ’ہجرت‘ کو اس وقت کے عہد ساز تجربے کے طور پر دیکھا، اور اس تجربے کو کسی تخلیقی سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت سے اس کی نمود ہوئی۔ خود انتظار حسین بھی اسی رویے کے حامل تھے۔
1974ء میں جب میں نے ایک طولانی مصاحبے کے دوران حسین سے اس مضمون کے بارے میں استفسار کیا، تو انہوں نے اپنی اوائل کی رجائیت کا اعتراف کیا، ساتھ میں کہا: ’’ لیکن آج، ہمارے سیاسی اتار چڑھاؤ کے کئی ادوار کے بعد، میں خود کو ایک مختلف کیفیت میں پاتا ہوں۔ اب مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایک قوم ایک عظیم تجربے کو گنوا رہی ہے۔ [۔۔۔] میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی قوم ہر زمانے میں اپنی تاریخ کو اپنے حافظوں میں زندہ رکھتی ہے، یا رکھنا چاہیے۔ [۔۔۔] سو، وہ تجربہ، یعنی ’ہجرت‘ کا تجربہ، بدقسمتی سے ہم نے ہار دیا ہے، یا ہم اس کے آگے ہار گئے ہیں۔ اور اس تجربے سے تخلیقی سطح پر کچھ بنا پانے اور [۔۔۔] ایک نئے تابناک شعور اور حساسیت کے پیدا کرنے کی عظیم توقع جو تھی، وہ اب دھندلا گئی اور ہم سے دور چلی گئی ہے۔‘‘
اپنے ملک کی، قیادت میں ناکامی کے ہاتھوں، سبھی امیدیں لُٹا بیٹھے ایک شخص کے طور پر، حسین کی اداسی پوری طرح بجا ہے۔ جمہوریت پر وار، سویلین حکومت کا سقوط، فوجی آمریت کا آغاز – یہ سب جو 1958 میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک ہی جھپٹے میں کر دکھایا؛ 1965 میں ہندوستان کے ساتھ عسکری تصادم کے دردناک نتائج؛ اور، شاید سب سے زیادہ ہتک آمیز، 1971 کی عوامی جنگ، جس نے پاکستان کی نازک سی وحدت کو ہمیشہ کے لیے پارہ پارہ کر دیا- اور یہ محض چند ایک افسردہ امر ہیں جو اُن کی اداسی میں ایک المیہ گونج پیدا کرتے ہیں۔
حسین ملک کی تباہی اور دولخت ہونے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ من جملہ، وہ 1947 (قیامِ پاکستان) اور1971 (پاکستان کی دو لختگی) کے درمیان کے عرصے کو ایک ایسے عمل کے طور پر دیکھتے ہیں جس دوران فرد میں شعور کی شمع رفتہ رفتہ بجھ گئی ہو۔ آدمی کی انسانیت کو پھر سے پانے کی شوریدہ کاوشیں رفتہ رفتہ تہہ و بالا ہو گئی ہوں، یہاں تک کہ وہ ہر طرح کی اخلاقی تمیز گنوا بیٹھا ہو۔
حسین کی 1970ء تک کی تخلیقی کاوشوں کا جائزہ لیتے ہوئے، جاوید قاضی نے انہیں تین مختلف مرحلوں میں تقسیم کیا ہے اور دکھلایا ہے کہ کس طرح سے ہمارے لکھاری کے ادبی موضوعات، کسی بھی مرحلے میں بنیاد سے بدلے بغیر، مختلف تاکیدات کو سامنے لاتے اور مختلف تکنیکوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ سو پہلا مرحلہ، 1950ء کی دہائی، معاشرتی، ثقافتی اور مذہبی علامات پر اصرار؛ دوسرے مرحلے میں، 1960ء کی دہائی، حیوانات کی پیکر کشی اور استعارہ پر؛ اور تیسرے مرحلے میں، 1970ء کی دہائی، ذات اور ذات کی پہچان پر۔ آدمی کی اپنی انسانیت، یا بشریت کو استوار رکھنے کی سعی، اور اس سعی میں اس کا عجز اور ناکامی وہ نکتہ ہے، جہاں ان تینوں تخیلات کی وحدت ہوتی ہے۔
یہ حسین کے ادبی کاموں پر میری اپنی تصریحی تقسیم سے بجا طور پہ قریب کا لگّا کھاتی ہے، جسے میں سفر کے ایک استعارے کے طور پر دیکھتا ہوں۔ یہ اس آگاہی سے شروع ہوتا ہے کہ کچھ بہت برا تو ہوا ہے، کچھ اور ہے، جو وافر تخلیقی امکانات کے ساتھ حاصل بھی ہوا ہے۔ میں خیالیوں کی ایک تکون (thematic triad) کھینچوں گا جو اس سفر کے تین پڑاؤوں کو واضح کرتی ہے: (1) حافظے کی بازگیری، اس منصوبے میں اول اول کامیابی، لیکن آخرِ کار ناکامی اور پھر (2) آدمی کی اخلاقی گمراہی اور گراوٹ، نتیجۃً (3) زندگی میں تمامتر تخلیقی اصول کی معدومی۔
پہلے ایک مضمون میں، میں نے اپنی دلیل کو سہارنے کے لیے متعدد افسانوں کا جائزہ لے کر خیالیوں کی اس تکون کا جامعیت سے برتاؤ کیا ہے اور اس امر کے مقابل خبردار بھی کیا ہے کہ مبادا تینوں میں سے کسی ایک پڑاؤ میں آئے افسانوں کو کسی ایک خیالیے کے ساتھ غیر ناقدانہ اور بے لچک طرح سے شناخت کیا جائے۔ جبکہ یہ درست ہے کہ ہر پڑاؤ اپنی حاوی خیالیہ تان کا حامل ہے، وہ تان دوسرے پڑاؤوں سے منہائیت میں نہیں ملے گی، جس سے اس تان کی بالکل نئی بنتیں سامنے آئیں گی، یا ایسی نئی موشگافیاں ملیں گی جو بنیادی پڑاؤ میں اب تک بالکل ناپید تھیں۔
مختصراً، داستان 1947 سے شروع ہوتی ہے۔ تقسیم ہند کے بعد مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کی ایک بھاری آبادی کو ایک دردناک دربدری سے گزرنا پڑا۔ دیس نکالا یا دربدری ہمیشہ ایک بھیانک تجربہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے، بہرکیف اس میں بڑی سرفرازی بھی ہے۔ حسین کے ہاں، یہ دربدری اپنے اندر مستقبل کے لیے لامحدود تخلیقیت کے جرثومے بھی ساتھ لائی ہے۔ یہ ایک تجدید اور تازہ شروعات کا وقت بھی ہے۔ حسین، ماضی کی طرف ایک بیباکانہ پرتخیل جست بھرتے ہوئے، 1947ء میں ہندوستانی مسلمانوں کے دیس نکالے کو – صحیح یا غلط – پیغمبر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلّم) کی 622ء میں مدینہ کی طرف ہجرت کا ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی پہلی مہاجرت، حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے اصحاب کے لیے جدائی سے پیوستہ تکلیف کے باوجود، نوزائیدہ مسلم برادری کے لیے ایک شاندار تخلیقی لمحہ بن کر سامنے آئی، وہ برادری جو وقت آنے پر سیاسی طاقت سے بہرہ مند ہوئی۔ 1947ء میں مسلمانوں کی تازہ ہجرت، ایک طرح سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی سنت کا اعادہ تھی، یا کم از کم ایک مسنون تجربے کے ساتھ تعلق کی تجدید ضرور تھی۔ جیسا کہ حسین نے بیان کیا ہے، اس ہجرت میں ایک روحانی واردات کی سی کیفیت تھی، جو امکانات اور امید کی حامل بھی تھی۔
1947 کی ہجرت کے تخلیقی امکانات سے استفادہ حاصل کرنے کی غرض سے، مسلمانوں کو اپنے ماضی کی طرف مڑ کے دیکھنے اور اپنا ثقافتی تشخص متعین کرنے کی ضرورت تھی۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں توقعات کے بر آنے میں ناکامی ہوئی۔ امید لڑکھڑا سی گئی۔ معاشرے کی تعمیر نو کا ہدف پانا ایک امرِ محال سا بن گیا۔ اول اول کی کچھ کامیابی کے باوجود، اس کوشش کو آخرِ کار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یادداشت کا کھو جانا -دوسرے لفظوں میں، پہچان کا کھو جانا- تباہی، یہاں تک کہ موت کا پیش خیمہ بنا، جو بہرکیف، دبے پاؤں یا بن بتائے نہیں آئی تھی۔ یوں ایک اخلاقی خبث پیدا ہو گیا، جب ایک قوم کا شعور تاریک پڑ گیا اور خوب و زشت کے درمیان تمیز کرنے کی تمامتر طاقت زائل ہو گئی۔
ہجرت اگرچہ ایک عارضی واقعہ ہے، لیکن اس کی ایک اساسی تجربے کی سی حیثیت کی کوئی زمانی حد و بند نہیں ہے۔ مسلمان جب بھی کسی تاریخی جبر کے ہاتھوں گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں، ہجرت بجا لائی جا سکتی ہے۔ سو اس میں تضاد والی کوئی بات نہیں ہے کہ اسے ایک عہد کے حاوی تجربے کا مقام ملے، خواہ کسی خاص علاقے کے کُل مسلمان بذات خود اس تجربے سے نہ بھی گزرے ہوں۔ موجودہ پاکستان کی آبادی کا محض ایک حصہ ہے جو ہندوستانی مہاجرین پر مشتمل ہے۔ باقی سب جہاں تھے، وہیں رہے۔ لیکن انہوں نے بھی اپنے عہد کے حاوی تجربے میں شرکت کی، جیسا کہ حسین نے مجھے دیے گئے ایک انٹرویو میں یاد دلایا ہے، اور وہ 1963 کے اپنے ایک مضمون میں وہ پہلے کہہ آئے ہیں۔ ان کی شرکت، بہرکیف، زیادہ تر روحی یا نفسی تھی۔
تقسیمِ ہند نے مسلم ثقافت کے تواتر میں سخت خلل ڈالا۔ پاکستان میں اپنے شروع کے دنوں میں، واقعات کے لڑھکتے ہوئے تودے کے آگے، وہ سمت کی سوجھ گنوا بیٹھے اور انہوں نے اپنی شناخت کے دھاروں کو اس کے سوتوں سے کٹا ہوا محسوس کیا۔ یوں حسین کے پہلے دو افسانوی مجموعوں ’ گلی گوچے ‘ اور ’ کنکری ‘ کے اوائلی افسانے ایسے کرداروں کو سامنے لاتے ہیں جو اپنے ماضی سے پھر سے جا ملنے، اور پس ازاں اپنی مجروح شناخت کی تشکیل نو، دراصل اسے ایک قابل فہم کُل کے طور پر نیا روپ بخشنے کی کوششوں میں ہیں۔ چونکہ بیشتر کردار شیعہ ہوتے ہیں، یہ بازیافت قوی شیعیانہ علامتوں اور شبیہوں کو برت کے ممکن بنائی گئی ہے۔
بازیافت اور بازآفرینی کے عمل کو بڑے دلخراش انداز میں دکھایا گیا ہے، مثال کے طور پر، جیسا کہ افسانہ ’ سیڑھیاں ‘ والے سیّد کی جدوجہد میں نظر آتا ہے۔ وہ یادوں سے خالی پاکستان پہنچتا ہے، جس کی ماضی کی حس اور اپنی شخصیت لٹ پٹ چکی ہے، اس حالت کی ایک نشانی اسکی خواب دیکھ پانے سے محرومی ہے۔ حسین کے ہاں خواب عام طور پر حافظے کو فعال بنانے میں مدد دیتے ہیں، اور حال اور ماضی کے درمیان ایک پل بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ سید ایک عجیب و غریب معلق ہونےکی کیفیت میں رہنے لگتا ہے، تاوقتیکہ ایک رات اس کے ساتھی مہاجروں میں تعبیر الرویاء کا موضوع بات میں آ جاتا ہے۔ جس وقت رضی اپنے خوابوں پر نظر دوڑاتے ہوئے قبل از تقسیم ہندوستان میں اپنی زندگی کی جھلکیوں کو ذہن میں لانا شروع کرتا ہے، وہ بے ارادہ سیّد کے اب تک جکڑے ہوئے حافظے کو متحرک بنا دیتا ہے۔ ماضی سے شبیہوں کا ایک ہجوم سا وارد ہونے لگتا ہے۔ افسانے کے اختتام تک، سیّد اپنا ماضی پھر سے جی چکا ہوتا ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ کہ، وہ پوری طرح اپنے ماضی کے اندر بحال اور زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ آگاہی پوری طاقت سے افسانہ کے آخر میں دکھائی گئی ہے: ’’ سید نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں، رضی کی طرف دیکھتے ہوئے پراسرار لہجے میں بولا، ’ میرا دل دھڑک رہا ہے، کوئی خواب دِکھے گا آج ‘ ۔ ‘‘
وہ کتنا ہی بھٹک گیا ہو، سیّد نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس لیے، یادداشت کا کھو جانا اس کے معاملے میں عارضی ہے اور وہ نسبتاً آسانی سے واپس آ جاتی ہے۔ لیکن گزرتے وقت اور بہتری کے بہت کم آثار کے حامل ملک کی سیاسی تقدیر میں، اس کھو گئے حافظے کے واپس لانے کے بارے میں ایک گہری غیر یقینی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یادوں کو پھر سے جمع کرنے کی سعی اور بھی زیادہ گھمبیر اور فوری و ضروری ہو جاتی ہے۔ افسانہ ’ اپنی آگ کی طرف ‘ کے بے نام مرکزی کردار کے معاملے میں یہ دراصل ایک سودائی سی سعی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ بے نام کردار ابھی ایک جلتی ہوئی عمارت کے حصے سے نمودار ہوا ہے۔ وہ ایک دوست کی طرف دوڑا دوڑا آتا ہے، جو اسے سہارا دینا چاہتا ہے۔ لیکن وہ منع کر دیتا ہے اور سمجھاتا ہے: ’’ شیخ علی ہجویری نے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے۔ پہاڑ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آگ کے اندر ایک چوہا ہے کہ سخت اذیت میں ہے۔ اور اندھادھند چکر کاٹ رہا ہے۔ چکر کاٹتے کاٹتے وہ پہاڑ سے اور پہاڑ کی آگ سے باہر نکل آیا۔ اور باہر نکلتے ہی مر گیا۔ ‘‘ وہ چپ ہوا۔ پھر آہستہ سے بولا، ’’ میں مرنا نہیں چاہتا۔ ‘‘
دوسرے لفظوں میں، وہ واقف ہے کہ عمارت سے باہر – جو شاید ایک مستحکم اور قائم بالذات کائنات ہے – وہ اپنی ذات کے جوہر سے ناقابل واپسی طور پر اجنبی ہو چکا ہے۔ استعارے کو پھیلائیے اور دیکھیے کہ اپنی روایت سے باہر ایک تخلیقی زندگی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس لیے، اگر اس کے اندر موت بھی ہو، اسے گلے لگا لیا جائے – جیسا کہ ’ایک بن لکھی رزمیہ ‘ میں پچھوا کرتا ہے یا ’ اندھی گلی ‘ میں ارشد اور نعیم کرتے ہیں – جو اپنے ترکیبی عنصر، اپنی آگ کی طرف لوٹ جاتے ہیں، کیونکہ اس سے باہر اس سے بھی کڑا کرب ان کا منتظر ہے۔
اخلاقی گراوٹ کا خیالیہ، انتظار حسین کے دوسرے ادبی پڑاؤ کا راہبر ہے۔ ’ آخری آدمی‘ (1967)، ان کے تیسرے مجموعے کو، گیارہ افسانوں میں ایک ناول کہیں تو بہتر ہوگا، جس کی ہر کہانی اپنی تمام تر مسحور کن قوت کے ساتھ اخلاقی ضمیر کو رفتہ رفتہ دیمک کھا جانے اور نتیجۃً تخیلاتی ادراک کے زوال، اور پھر بالآخر شخصیت کے کھوکھلے ہو جانے کے عمل کو بیان کرتی ہے۔ ان افسانوں میں ایک متامل دل کو پہلے بدی کا بہکاوا ملتا ہے، جس کے ساتھ میں شک کا ظہور ہوتا ہے، بالآخر وہ ارتکابِ گناہ میں سر کے بل کود پڑتا ہے۔
یوں افسانہ ’ ٹانگیں ‘ میں، کوچوان یاسین کا پاکستانی زندگی کا تجربہ شخصی اخلاق کے زوال کو نمایاں کرتا ہے۔ ایک تازہ دم کر دینے والی سادگی کا حامل، اور اپنے پیارے بھولپن میں بالکل بچگانہ سا، لیکن، سب سے بڑھ کر، ایک باطنی اخلاقی ضابطے پر چلنے والا، یاسین خود کو نئے ملک میں بار بار دغا کھاتا ہوا پاتا ہے۔ ہندوستان میں اس کے پرانے آبائی شہر سے ایک ساتھی مہاجر، جسے یاسین نے پورا ایک مہینہ چھت فراہم کی، اس کے تانگے سے گھوڑا چُرا لے جاتا ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ فطرت بھی اس ملک کے خلاف سازش میں مصروف ہے۔ دسویں یا گیارہویں صدی کے قابلِ تعظیم، شیخ علی ابن عثمان جُلابی (المعروف، الہجویری، جنہیں لوگ عقیدت سے داتا گنج بخش کے نام سے جانتے ہیں)، کے روضہ کے میناروں کو ایک زوردار آندھی آ لیتی ہے۔ یاسین کے لیے، مقدس عمارات، حرمت میں لپٹی ہوتی ہیں اور کچھ حد تک وقت اور فطرت کے الٹ پھیروں سے مبرّا ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ اس کی سوچ سمجھ سے باہر ہے؛ وہ کہتا ہے: سیّد صاحب، آندھیاں آگے بھی بہت تیز چلی ہیں۔ سیلاب بھی آئے ہیں۔ دربار داتا کے قدم چومنے تو بہت دفعہ آیا۔ پر سیڑھیاں نہیں چڑھا۔ ‘‘
یاسین حیران ہوتا ہے: ’’ صاب دلی کی جمعہ مسجد لوہا لاٹھ ہے۔ جب فساد ہوئے تھے تو سنگھ والوں نے اسے پھونکنے کی ٹھانی۔ پر مسجد جل کے نہیں دی! ‘‘ ۔ ’’ داتا صاب کے مینار کس نے گرائے؟ ‘‘ – یاسین بہت اندھیری سی سوچ میں غرق ہو جاتا ہے – ہو نہ ہو یہ خود پاکستانیوں کا کیا دھرا ہے! لیکن کیوں؟
عمومی اخلاق اتنا گہرا ڈوب چکا ہے کہ دینے دلانے اور ’’ جان پہچان کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ‘‘ ۔ اور جونہی ایک بالکل دیانت دار، بھلے مانس، خدا ترس آدمی، ملک کے دارالحکومت اور اقتصادی گڑھ کراچی میں پیر دھرتا ہے، وہ کسی معمولی سے بھی اخلاقی احساس سے کہیں پرے ہو جاتا ہے۔ اور ایک کامل لفنگا بن جاتا ہے! ’’ سالا برا زمانہ آ گیا ہے، ‘‘ یاسین یہ افسوسناک نتیجہ نکالتا ہے، ’’ جینے کا مزہ نہیں رہا ان دنوں۔ ‘‘ سب کے ساتھ بکرے کی ٹانگیں اگ آئی ہیں – یہ ذاتی اخلاق کے انہدام کا استعارہ ہے۔
جہاں ’ پرچھائیاں ‘ اور ’ ہم سفر ‘ جیسے افسانے ذات اور شناخت کے بارے شبہات کے سر اٹھانے کی مصورانہ عکاسی کرتے ہیں، ’ آخری آدمی ‘ اور ’ زرد کتا ‘ جیسی کہانیاں آدمی کی اپنی انسانیت، یا پھر اپنی بشریت کو استوار رکھنے کی پرزور کوشش، اور آخر کار ناکامی کو نمایاں کرتے ہیں۔ ’کایا کلپ ‘ بالباطن ثانیالذکر خیالیے کی ایک صورت ہے، جس میں شخصیت کا کھو جانا ایک ارادی عمل بن کر اور بھی المناک ہو جاتا ہے۔ یوں یہ محض عہد کے اخلاقی زوال کا معاملہ نہیں رہتا، بلکہ خود آدمی کی روح کا ایک ناسور بن جاتا ہے۔
کہانی میں شہزادہ آزاد بخت کا انجام دوسری مقبول اساطیر کے شہزادوں سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ عمومی داستانی شہزادوں کے برعکس سفید دیو کو نہیں مار گراتا اور نہ ہی وہ مصیبت میں پھنسی شہزادی کو چھڑا کے لاتا ہے، بلکہ وہ اپنے قابل ذکر طور پر گہن زدہ سے اینٹی ہیرو والے کردار کے آگے سر کو خم کیے ہوئے ہے جسے اس کی آدمیت کے متواتر زوال پذیر ادراک نے جنم دیا ہے۔ جو ہر شام دیو کے لوٹنے کی آہٹ سنتے ہی مکھی میں بدل دیا جاتا ہے، اور ہر صبح دیو کے چلے جانے پر شہزادی کے دھیرے سے چھوتے ہی پھر سے انسان میں بدل جاتا ہے، شہزادہ آزاد بخت اپنی انسانی شناخت کی آخری چھاپ تک اتار کر پھینک چکا ہے، جس کے حتمی انہدام کا اشارہ اس نصیب والی شام ملتا ہے جب شہزادی تو اسے مکھی کی جون میں نہیں بدلتی، لیکن وہ اپنی مرضی سے خود کو مکھی میں بدل لیتا ہے۔ وہ مکھی کی جون کے لیے اپنے انسانی خواص خود سے تیاگ دیتا ہے! ظاہری تبدیلی اس باطنی تغیر، جو انسان میں اپنے تصورِ ذات کے بارے میں رونما ہوتا ہے، کا محض ایک استعارہ ہے۔
اس نئے – پاکستانی – فرد کے دو ظاہر اوصاف اس کا بے شخصیت ہونا اور اس کی سراسر بے رحمی ہیں۔ اپنے آپ سے بے خبر شخص ہی دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے جس میں کسی روک ٹوک یا تمیز کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ بلا شبہ اس قسم کے آدمی نے سابقہ مشرقی پاکستان میں جو بھیانک گل کھلائے ان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ لیکن وہ ایسا جبھی کر سکتا تھا جب وہ اپنے ادراک کی شمع گل کر چکا ہو۔
کھردری غیر انسانیت اور اپنے تصورِ ذات کو کھو دینے کے باہم مربوط خیالیے، انتظار حسین کے چوتھے مجموعے ’ شہرِ افسوس ‘ (1973) میں بار بار نظر آتے ہیں۔ البتہ، یہ کہانیاں جان بوجھ کر عجیب و غریب سی ناواقعیت کی بندش میں باندھی گئی ہیں تاکہ انہیں کسی مخصوص زمان یا مکان سے منسوب نہ کیا جا سکے۔
’ وہ جو کھوئے گئے ‘ میں شخصیت یا تصورِ ذات کے سقوط اور موت کی ایک کرخت مثال ہمیں ملتی ہے۔ اس میں چار کردار ہیں، ناموں سے محروم رکھے گئے، تاکہ ان کی شخصی انا کے کھو جانے کے احساس کو علامتی طور پر ابھارا جا سکے، اور انکا تذکرہ صرف اپنے ظاہری حلیے سے کیا جاتا ہے: باریش آدمی، نوجوان، تھیلے والا، اور زخمی سر والا۔ کسی مقام پر کسی کربناک واقعے سے اپنے فرار کے دوران، انہیں یہ شک گزرنے لگتا ہے کہ ان میں سے ایک بندہ کم ہے۔ چونکہ ان کی کوئی یادداشت نہیں ہے، وہ اس ایک گمشدہ شخص کا چہرہ یا نام یاد نہیں کر پاتے، یا پھر، یہ کہ آیا گمشدہ شخص مرد تھا کہ عورت۔ وہ بار بار گنتی کرتے ہیں۔ ہر بار جب ان میں سے کوئی گنتی کرنے لگتا ہے، تو خود کو شمار کرنا بھول جاتا ہے۔ جس سے یوں لگتا ہے کہ لاپتہ شخص، دراصل، وہ خود ہے۔ یوں ایک سچ مچ کے آدمی کی جگہ ایک غیرموجود آدمی لے لیتا ہے، جبکہ گوشت پوست کا آدمی، شعورِ ذات کے فقدان کی بدولت غیر موجود میں گم ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں مضمر المیہ-طربیہ تناقض اس وقت پورے ہیجانی انداز میں بے نقاب ہو جاتا ہے جب ’’ زخمی سر والے آدمی ‘‘ کو یہ لگتا ہے کہ اس کا وجود اس کے اپنے آپ کے شعور پر اتنا منحصر نہیں جتنا کہ دوسروں کی خوشنودی پر ہے جو اس کے وجود کو شمار میں لا رہے ہیں۔ وہ ’’ باریش آدمی ‘‘ سے مخاطب ہوتا ہے: ’’ سو اگر تم اپنی گواہی سے پھر جاؤ تو پھر میں بھی نہ رہوں گا۔ ہے نا؟ ‘‘
افسانہ ’ شہرِ افسوس ‘ ، جو کہ ساختی اعتبار سے ’وہ جو کھوئے گئے ‘ سے مشابہہ یا اس کا فکری تسلسل معلوم ہوتا ہے، میں اخلاقی گراوٹ اور نتیجۃً شخصیت کی موت کے دو عمل ایک تخلیقی اصول کے طور پر باہم آن مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ 1971ء میں پاکستان کی سیاسی دولختگی کے کچھ ہی بعد لکھا گیا تھا، تاہم اِس میں اُس واقعے کا کوئی براہِ راست حوالہ نہیں ہے۔ ’ وہ جو کھوئے گئے ‘ میں اخلاقی گراوٹ اور موت کے دو عمل (اول الذکر محض ایک دھندلے سے اشارے کے طور پر، مؤخر الذکر ایک حاوی استعارے کے طور پر) بڑے جلی انداز میں اس افسانے میں جلوہ فرما ہیں۔
’ شہرِ افسوس ‘ کا اثر اور سحر انگیز طاقت کچھ اور بھی نکھر کر سامنے آئے گی اگر آپ ان حالات و واقعات سے واقف ہوں جن کے تحت بنگلہ دیش ایک الگ قوم بنا۔ جہاں 1947ء میں مذہب کی بنیاد پر برصغیرِ ہند منقسم ہوا، وہیں 1971 میں یہ شک پوری طرح رفع ہو گیا کہ کسی عوام کو باہم جوڑے رکھنے کے لیے مذہب سے کچا دھاگا اور کوئی نہیں۔ 1947ء میں جہاں ایک عقیدے کے ماننے والے دوسرے والے کے سامنے آ کھڑے ہوئے، وہیں 1971ء کے واقعات نے مسلمانوں کو مسلمانوں کے مقابل لا کھڑا کیا۔ صرف دم توڑتا اور بالآخر مسمار ہوتا انفرادی اخلاقی احساس ہی انسانیت کے اس فقدان کی وضاحت کر سکتا ہے۔ ’ شہرِ افسوس ‘ میں، حسین نے ایسی ہی ایک وضاحت پیش کی ہے۔ اگر ’ وہ جو کھوئے گئے ‘ کے چاروں کردار احساسِ ذات کھو چکے ہیں، ’ شہرِ افسوس ‘ کے تینوں کردار بھی نام اور پہچان سے محروم چلتی پھرتی لاشیں بن چکے ہیں۔ وہ افسوس کے شہر میں، اپنے گناہوں اور عدم انسانیت کا بوجھ اٹھائے ہوئے، مارے مارے پھرتے ہیں کہ کوئی آ کر انہیں دفن کرے۔ وہ اتنے مسخ ہو چکے ہیں کہ انہیں پہچانا نہیں جا سکتا۔ ان کی موجودہ حالت ان کے اعمالِ بد کا نتیجہ ہے۔
اخلاقی موت کے خیالیہ کی رونمائی ابتدائی سطر میں یوں کی گئی ہے: ’’ پہلا آدمی اس پر یہ بولا کہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے کہ میں مر چکا ہوں ‘‘ اور یہ خیالیہ کہانی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس کی موت کا سبب کیا تھا؟ 1971 کے عوامی دستورِ نظم میں خلل اور اس کے نتجے میں تب کے مشرقی پاکستان کے اندر خلفشار میں، پہلے آدمی نے، اس کے اپنے اعتراف کے مطابق، ایک نوجوان، غالباً ایک بنگالی، کو مجبور کیا کہ وہ اپنی بہن کو برہنہ کرے، ایک ایذا پسندانہ شوق و ذوق سے اس کا تماشا کیا، اور پھر اس کی آبرو لوٹے۔ یہ عمل، جس کے سبب کسی بھی آدمی کو شرم سے مر جانا چاہیے، پہلے آدمی کو اس پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ جب دوسرا آدمی اس سے پوچھتا ہے، ’’ اور تو مر گیا؟‘‘ وہ کہتا ہے، ’’ نہیں، میں زندہ رہا، ‘‘ جس پر تیسرا آدمی حیران رہ گیا، ’’ زندہ رہا؟ – اچھا؟ ‘‘
پہلا آدمی اخلاقی جرائم کا ایک پورا سلسلہ، اور اس کے بعد سب سے تباہ کن جرم، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے زندہ رہتا ہے،: اس کی اپنی بیٹی کی آبروریزی، کسی اور کے نہیں بلکہ خود اس کے اپنے ہاتھوں، اور وہ بھی اب کے اسی بنگالی نوجوان کے اعلانیہ حکم پر، جو قسمت کے الٹ پھیر سے، اب کے بالادست تھا۔
دوسرا اور تیسرا آدمی بھی ایسے ہی انسانیت سے گران دینے والے ایک عمل سے گزر چکے ہیں، فرق یہ ہے کہ ثانیالذکر مرا نہیں بلکہ ’’ کھو گیا ‘‘ ہے – یہ مرنے سے بدتر تقدیر ہے۔ پہلے اسے خود کو ڈھونڈنا ہے، پھر مرنا ہے، اس کے بعد کہیں دفن ہونے کی فکر کرنی ہے۔ وہ باقی دونوں کے انسانی ملبوں پر نظر ڈالتا ہے؛ کہ کہیں وہ بھی خود کو ڈھونڈ لانے سے پہلے کاہلی میں نہ جا پڑے، اور اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر ان سے آزاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن دوسرے دونوں آدمی کسی طرح اسے اس کوشش کے لاحاصل ہونے پر قائل کر لیتے ہیں۔ ’’ پھر؟ ‘‘ تیسرا آدمی مایوسانہ پوچھتا ہے۔ دوسرا آدمی اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ اسے لگتا ہے کہ وہ جامد ہو جائے گا۔ بالآخر وہ کہتا ہے: ’’ پھر یہ کہ اے کھوئے ہوئے آدمی بیٹھ جا، مت پوچھ کہ تو کہاں ہے، اور جان لے کہ تو مر گیا ہے۔‘‘
ایک اور افسانے ’اسیر‘ میں 1971ء کے واقعات کے بارے میں پاکستانی موقف کی حقانیت پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ یہ کہانی ان سوچ سے عاری رنگ رلیوں، مطلق بے نیازی، اور بھونڈی مادیت پسندی پر، جو عین اس وقت مغربی پاکستان کے مزاج پر طاری تھی جب بنگلہ دیش میں خونی واقعات رونما ہو رہے تھے، ایک لطیف فردِ جرم بھی ہے ۔ جاوید، جو بنگلہ دیش کے ہیبت ناک منظر سے بھاگ کے نکلا ہوا ہے، لاہور میں اپنے پرانے دوست انور سے ملتا ہے۔ انور یہ جاننا چاہتا ہے کہ مشرقی پاکستان میں ہوا کیا تھا۔ جاوید اپنی آنکھوں دیکھی ہیبتوں پر بات کرنا چاہتے ہوئے بھی، عجیب طور سے ایسا نہیں کر پاتا؛ اپنے آس پاس کی رنگ رلیوں اور بے نیازی نے اس میں اپنے تجربے پر نگاہ ڈالنے کی مہین سی خواہش کو بھی مار دیا ہوا ہے۔ الٹا وہ مرزا، ایک شخص جس کا پچھلے دن انور نے ذکر کیا تھا، کے بارے مزید کچھ جاننا چاہتا ہے۔ انور اسے بتاتا ہے کہ مرزا کو ایک سیاسی جلوس، جو ابھی ابھی ختم ہوا تھا، سے نکلتے ہوئے گولی سے اڑا دیا گیا ہے۔
جاوید کانپ اٹھتا ہے۔ اسے یہ جان کر حقیقی دھچکا لگتا ہے کہ اس کے مارے جانے کی کوئی واضح وجہ نہیں تھی، نہ ہی مارے جانے کے بعد کوئی احتجاج یا واقعہ ہوا۔ یہاں تک کہ انور نے بھی واقعے کو کچھ خاص توجہ نہیں دی۔ کہانی یوں ختم ہوتی ہے: ’’ یار ‘‘ اس نے ڈرتے ڈرتے ایک بار پھر کریدا۔ ’’ تم نے تو وہاں اس سے بہت زیادہ دیکھا ہو گا۔ ‘‘ ’’ کیوں؟ ‘‘ جاوید نے تامل کیا۔ ’’ ہاں ‘‘ اس نے افسردہ لہجے میں کہا ’’ تم ٹھیک ہی کہتے ہو __ مگر ہم کو یہ تو پتہ تھا کہ کیوں ہو رہا ہے ___ اور یہ احساس تو تھا کہ کیا ہو رہا ہے ___ ‘‘
دوسری طرف، ایسے ہی ایک افسانے ’’ نیند ‘‘ میں، جب اسلم، زیدی اور ظفر مشرقی پاکستان کی زندگی سے بھاگ کر آئے ہوئے سلمان کو دق کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے آنکھوں دیکھے پرہیبت مناظر کے بارے انہیں کچھ بتائے، سلمان کو اس دردناک تجربے پر مکرر نظر کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اس کی بجائے وہ بار بار اونگھنے لگتا ہے۔ آخر کار، وہ انہیں کہتا ہے کہ اسے نیند آئی ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے۔
انور اور سلمان دونوں سانحے کے بارے گفتگو کرنے کی بے ثمری، جو ویتنام جنگ کے کئی سپاہیوں کے اسی تجربے کی یاد دلاتی تھی، کے کرب سے واقف ہیں۔ ایک باطنی احساس انہیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ انہیں جو کچھ کہنا ہے اسے شاید ہی کوئی سمجھ پائے۔ وطن کو یہ سب نہیں جاننا ہے۔ اور پھر، مشرقی پاکستان کا یہ تجربہ ہی اتنا ڈراؤنا ہے کہ اسے لفظوں میں سمونا یا باشعور ذہن کی سرگرمی سے سمجھ پانا آسان نہیں۔ نیند کے اُس کنارے کا نرم اور ملائم احساس اس کی نسبت بہتر آؤ بھگت کر سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انتظار حسین کے کام میں نیند شاید ہی کبھی فرار کا رستہ رہی ہو۔ وہ اسے نیم روشنی کی ضمانت دیتی ہوئی ایک ایسی اقلیم کے طور پر دیکھتے ہیں جس میں بصارت کی آوارگی کچھ اور سریع ہو جاتی ہے، تحت الشعور ابھر کے سطح پہ آ جاتا ہے اور دھندلے خیالات میں بہت تابندہ متعینات، ارتکاز اور گھمبیرتا داخل کر دیتا ہے۔ اس لیے تعجب نہیں کہ انتظار حسین کہتے ہیں: ’’ میں سب سے زیادہ تب سوتا ہوں، جب میں کوئی کہانی لکھنے کا سوچ رہا ہوتا ہوں اور اس کی جزویات پر کام کر رہا ہوتا ہوں! ‘‘
جب ایک آدمی کو سردمہری کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس پر کسی ہلکے سے ردعمل کو بھی اکساوا نہیں ملتا تو یہ یقیناً بے حسی، اور سوچ سمجھ کے ایک بحران کی نشانی ہے۔ ایک بےمعنی موت صرف ایک بےمقصد زندگی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مغربی پاکستان کی بالکل مختلف صورت حال کا تقابلہ اس طرح مشرقی پاکستان کی صورتحال سے کیا جاتا ہے، جہاں برسرِ جنگ گروہوں کو کم از کم اس بات کا واضح ادراک تو تھا کہ وہ کس بات کے لیے یا کس کے خلاف لڑ رہے تھے۔
حسین کچھ یوں کہنا چاہتے ہیں: جب تک پاکستان کا مغربی حصہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہ مشرقی حصے کو نہیں سمجھ سکے گا۔ کیونکہ اپنے آپ کو جانے بغیر ہم دوسروں کو نہیں جان سکتے: اور اپنی ذات کا معتبر علم خود پر ایک صحتمند شک سے پھوٹتا ہے۔
آخری چار افسانے، اور ساتھ میں ’ ہندوستان سے ایک خط ‘ اور ’ کچھوے ‘ اور ناول ’ بستی ‘ کو ملائیں تو حسین کا وہ ادبی ترکہ بنتا ہے جسے 1971ء کے واقعات سے متاثر ہو کر لکھی گئی تحاریر کہا جاتا ہے۔ تاہم ان کہانیوں میں ایسا کچھ نہیں ملے گا جو خود کو حتمی طور پر 1971ء کے ساتھ جوڑتا ہو۔ حسین کے بنیادی محرکات اخلاقی ہیں۔ وہ علم التواریخ نہیں، تاریخ کے اندر انسان کی حقیقت کے تعاقب میں ہے۔
ماخذ: ڈان
حواشی
1۔ اشارہ غالباً 2012کے اواخر میں ’بستی‘ کے انگریزی ترجمے کی اشاعت، یا پھر انتظار حسین کی مین بُکر پرائز 2013 کے لیے نامزدگی کی طرف ہے۔