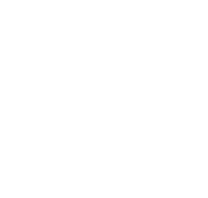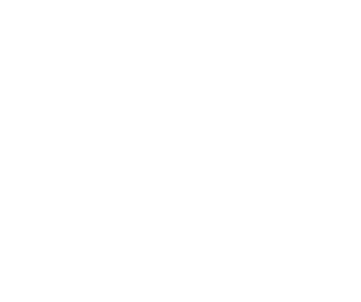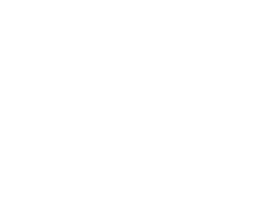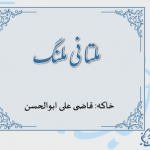رئیس فروغ کی یاد میں۔ گفتگو: احمد جاوید صاحب (حروف کار: عاصم رضا)
نوٹ: احمد جاوید صاحب کی یہ گفت گُو تقریباً چار برس قبل یوٹیوب پر شیئر ہوئی تھی جسے یہاں سے براہ راست سُنا جا سکتا ہے۔ اس بات کا اعادہ ضروری ہے کہ حروف کار ہی پیراگراف، رموز ِ اوقاف اور بعض فقروں کے دروبست میں تھوڑی بہت تبدیلی کا سزاوار ہے۔
آج میں ایک ایسے صاحب کے بارے میں کچھ تھوڑی سی باتیں کروں گا جو میرے لیے محبوب ترین شخصیتوں میں سے ایک تھے۔ میرے تعلق میں جتنے بھی لوگ آئے اُن میں جو کچھ لوگ جن سے مجھے جاں نثارانہ محبت ہے (یہ) اُن میں سے ایک تھے۔ نہایت عمدہ شاعر تھے لیکن ایک ایسا حُسن اور ایک ایسی روشنی میں گوندھی شخصیت تھے کہ اُن کی شاعری گویا اُن کی شخصیت کی جمالیاتی گہرائی اور اخلاقی بلندی کا بہت ہی جزوی اظہار ہے۔ وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے اظہار سے زیادہ بڑے ہوں۔ رئیس فروغ (1926ء تا 1982ء) یقیناً بل کہ سو (100) کے سَو بار یقیناً، اُنھی نادر شخصیات میں سے ایک تھے۔ اور وہ بھی شاعروں میں ہونا، یہ بہت ہی مشکل بات ہے کیوں کہ شاعروں میں اظہار اُن کی شخصیت سے بے شُمار گنا زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب، شاعر اپنے مقطع میں جو خود کو ظاہر کرتا ہے وہ اتنا ہوتا نہیں ہے۔ شاعری اظہار کا فن ہے جواظہار کی عادت بن جاتی ہے۔ لیکن یہ (بات) کہ یہ ساری عُمر شاعروں ہی میں رہے۔ مذہبی خاندان کے تھے۔ مولانا نعیم الدین مُراد آبادی (1887ء تا 1948ء) کے نواسے تھے۔ بہرحال ساری عُمر شاعروں میں رہے لیکن اپنی شخصیت کو شاعرانہ پن سے محفوظ رکھا۔ یہ تھے رئیس فروغ صاحب جن کے دو تین مجموعے (رات بہت ہوا چلی، سورج چاند ستارے) بھی آ چکے ہیں۔ بچوں کے لیے اتنی اچھی نظمیں شاید ہی کسی نے لکھی ہوں جیسی فروغ صاحب نے لکھی ہیں اور پھر یہ کہ غزلوں میں بھی نہایت منفرد شاعر اور بہت خوش گَو، بہت ملائم شاعر۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ اُن کی بنائی تصویر زیادہ دل کش ہے یا اُس تصویر کو بیان کرنے والا لہجہ زیادہ ملائم ہے۔ میں کیا کہوں اُن کے بارے میں، وہ بہت ہی بڑے آدمی تھے۔
بہرحال اب اِس کا تھوڑا سا مَیں بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ مَیں سن 1966ء میں جب میٹرک میں تھا تب سلیم احمد (1927ء تا 1983ء) سے مِلا اور پھر جیسے اُنھی کا ہو کے رہ گیا۔ اُس کے بعد سے میرے تمام تعلقات، ادبی اور غیر ادبی ہر طرح کے تعلقات یعنی محبت کے تعلقات، وہ سلیم احمد کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ مطلب، اگر کہ میرا کوئی قریبی عزیز بھی سلیم احمد کے بارے میں کوئی ناگوار بات کہہ دیتا تو میں اُس سے ترکِ تعلق کا ارادہ کرلیا کرتا تھا۔ مطلب، سلیم احمد جیسے ہمارا محورِ زندگی بن گئے تھے، تو ساری زندگی اُنھی کے گرد گھومتی تھی۔ اب سلیم بھائی کا اپنا مزاج یہ تھا کہ وہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے تھے جو اُن سے اختلاف کریں۔ مطلب، اپنے انتہائی چھوٹے برخوداروں کو بھی اختلاف پہ اُکسایا کرتےتھے۔ مجھ سے اگر وہ ناراض رہے تو صرف اس وجہ سے ناراض رہے کہ میں اُن کے سامنے بولتا نہیں تھا۔ خیر اب کیونکہ سلیم احمد کا ذوقِ تعلق ایسا تھا کہ وہ اختلاف کرنے والوں کو زیادہ قریب کر لیتے تھے اور اُن کے جو قریب ترین دوست تھے اُن میں سے اکثریت جو ہے وہ سلیم احمد سے اختلافِ رائے میں بہت بےباک تھی (یعنی) اُن کے سامنے اور وہ اُن کے قریب ترین دوست تھے۔ اِن دوستوں میں، اختلاف کرسکنے والے اور کرتے رہنے والے دوستوں میں، سب سے نمایاں نام قمر جمیل صاحب (1927ء تا 2000ء) کا تھا۔ قمر بھائی کو سلیم احمد کے تمام ادبی، مذہبی اور غرض ہر طرح کے تصورات سے مکمل اختلاف تھا۔ مطلب، جیسے اُنھوں نے طے کر رکھا تھا۔ وہ اپنی مکمل اختلاف کا بہت جارحانہ اور بعض اوقات پیغمبرانہ لہجے میں اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ قمر بھائی ہمارے بہت ہی دلچسپ آدمی تھے اُن کے بارے میں کسی وقت اور میں کہوں گا۔ وہ بھی بہت زبردست شاعر تھے، بہت عُمدہ critic (نقاد) تھے۔ تو قمر بھائی کا اکثر موضوع سلیم احمد ہوا کرتے تھے اور وہ اُنھیں کہتے تھے مولوی سلیم احمد۔ وہ (یہ) سب کرتے تھے ۔ سلیم احمد کو سب کچھ معلوم تھا لیکن اِس کے باوجود اُن سے بہت ہی قریب کا تعلق رکھتے تھے۔
سلیم بھائی کے ہی کہنے پر مَیں قمر جمیل صاحب سے ملا۔ اُس کی وجہ یہ ہوئی کہ قمر جمیل صاحب جدید شاعری کے مطلب، عالمی شاعری کے بہت جاننے والے تھے اور جدیدیت کیا ہے، یہ اُن سے ملے بغیراُس ماحول میں سمجھ نہیں آ سکتی تھی جس ماحول میں مَیں تھا۔ اُس کے لیے سلیم بھائی نے مجھے کہا کہ تم قمر جمیل صاحب سے ملا کرو۔ قمر جمیل صاحب بھی ریڈیو پاکستان میں تھے، سلیم ا حمد بھی ریڈیو پاکستان میں تھے۔ ریڈیو پاکستان (کراچی) کی کینٹین جیسے لاہور کا پاک ٹی ہاؤس ہے اِس طرح کی حیثیت رکھتی تھی۔ مَیں اُن سے ملنے لگا اور دو چار ملاقاتوں ہی میں مجھے قمر جمیل صاحب سے بہت شدید محبّت ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے گھر کے کوئی بڑے ہیں اور اتفاق یہ ہے کہ وہ میرے ہم شہر تھے۔ مطلب، ہمارا جو آبائی شہر ہے الٰہ آباد، قمر صاحب بھی الٰہ آباد کے تھے۔ مگر الٰہ آباد کا ہونا اُس (محبّت) کا سبب نہیں تھا۔ اُن کی شخصیت میں ایک عجیب طرح کی دل کشی تھی نوجوانوں کے لیے اور نوجوان جیسے خود کو اُن کی کشش سے بچا نہیں سکتے تھے اگر ادب اور شعر اُن کا مسئلہ ہو۔ تو مجھے بھی اِن سے شدید محبّت ہو گئی تھی۔ مَیں اُس زمانے میں بالکل اکیلا تھا تو سلیم بھائی نے مجھ سے کہا کہ قمر جمیل صاحب کے گھر کا اگلا حصہ خالی ہے وہ اُن کی بیٹھک تھا، تو تم وہاں رہنے لگو۔ اُنھوں نے قمر بھائی سے کہا کہ اب یہ یہاں رہے گا۔ وہ بہت خوش ہو گئے اور بہت خوشی سے اجازت دِی۔ پھر وہ ایک الگ داستان ہے کہ وہاں کیا ہوتا تھا۔ اب یہ میرا یہ معمول بن گیا تھا کہ یعنی قمر بھائی کے ہاں رہنے کا جب (طے) ہو گیا تو معمول یہ تھا کہ زیادہ وقت پھر بھی سلیم بھائی کے ساتھ گزارتا تھا اور باقی سارا وقت قمر جمیل صاحب کے ساتھ رہتا تھا۔ کراچی شہر میں سلیم احمد کے بعد سب سے بڑی نشست، مطلب اِن کی ہوا کرتی تھی۔ کراچی میں رواج تھا کہ آپ جس کے شاگرد ہیں یا جس سے ملنے آئے ہیں، کوئی نشست ہونی ہے تو وہ بیٹھکوں میں ہوتی تھی اُن صاحب کے گھر میں۔ اُن کے گھر میں نوجوانوں کا ایک ہجوم رہتا تھا، مطلب ان کا حلقہ بھی بہت بڑا تھا جس میں شہر بھر کے جو جِدت پسند ادیب اور شاعر تھے وہ شامل ہوا کرتے تھےاور قمر بھائی اُن کے لیے بالکل گُرو کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ جب میں قمر جمیل پر کچھ عرض کروں گا تو پھر مزہ آئے گا اُن باتوں کا۔ مطلب یہ کہ جیسے کسی کو کہہ دیا کہ تم ملارمے (Stephen Mallarme: 1842 – 1898) سے بہت بڑے شاعر ہو، کسی کو کہہ دیا کہ تم فراق (1896ء تا 1982ء) سے بڑے شاعر ہو اور اس طرح کہتے تھے کہ اُس کو پورا یقین ہو جاتا تھا کہ ایسا ہی ہے۔ اِس کے بعد وہ باہر نکل کے اپنے اس نئے مرتبے کے مطابق behave کرتا تھا اور مذاق کا نشانہ بنتا تھا۔ وہ ایک پوری داستان ہے۔
خیر اِس حلقے میں قمر جمیل صاحب کے یہاں جو مستقل حاضر باش حضرات تھے اُن میں کچھ لوگ بہت ہی نادر صلاحیتوں کے (حامل) تھے اور مشہور لوگ تھے۔ اُن میں ایک صاحب تھے ضمیر علی بدایونی صاحب۔ مَیں نے جدید فلسفے پر اور ادب پر ایسی مہارت رکھنے کوئی دوسرا نہیں دیکھا جیسی ضمیر علی صاحب رکھتے تھے۔ اُن کی دو تین تنقیدی کتابیں بھی ہیں۔ ایک تو یہ تھے اور دوسرے طلعت حسین (1940ء تا 2024ء)۔ وہ اُس زمانے میں وہ ریڈیو کے بڑے صدا کاروں میں سے تھے اور ٹی وِی کے تو بادشاہ تھے۔ مطلب، بہت بڑے اداکار سمجھے جاتے تھے۔ لیکن اِن سب حیثیتوں سے قطع نظر کیوں کہ اِن حیثیتوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں تھا اُن سے، وہ جو تھے جدید مغربی ادب وغیرہ کے بھی بہت ماہر تھے۔ بہت پڑھتے تھے اور اُنھوں نے شاعری بھی تھوڑی بہت کی لیکن پھر چھوڑ دی۔ بہت با کمال آدمی ہیں۔ اللہ اُنھیں زندہ رکھے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ (نوٹ: اس گفت گو کی ریکارڈنگ کے دِنوں میں طلعت حسین صاحب زندہ تھے۔ 2024ء میں انتقال ہوا۔ از حروف کار)۔ اِن کے علاوہ وہاں احمد ہمیش (1940ء تا 2013ء) رہتے تھے۔ میرے ساتھ دو آدمی اور رہتے تھے قمر جمیل صاحب کے شاگردوں میں۔ ایک احمد ہمیش اور دوسرے محمود کنور۔ احمد ہمیش کا نام اب لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے زمانے میں بہت ہنگامہ خیز شخصیت رہے ہیں۔ ہندوستان پاکستان میں کہہ سکتے ہیں کہ اُن کا نام ہر ادب شناس جانتا تھا۔ یہ خود کو نثری نظم کا اردو میں بانی کہتے تھے /سمجھتے تھے اور بہت منفرد شاعر لیکن نثری نظمیں لکھتے تھے۔ بہت اچھی کہانیاں اِنھوں نے لکھیں۔ اِن کی ایک کہانی کے کئی ترجمے ہوئے اور اُس کو شاید کوئی ایوارڈ وغیرہ بھی ملا یونیسیف وغیرہ کی طرف سے۔ اُس کا عنوان تھا ”مکھی“۔ مطلب، بہت creative (تخلیقی) آدمی تھے۔ اِن کے ساتھ ہوتے تھے محمود کنور۔ وہ بالکل جاگیردارانہ مزاج اور مفلسانہ حالات رکھتے تھے۔ وہ بڑے دبنگ آدمی تھے۔ (ذات کے) کنور تھے، مطلب راجپوت تھے اور پنجاب کے تھے لیکن انتہائی تخلیقی آدمی تھے۔ غزل، نظم سب میں بہت ہی گہرائی کے ساتھ چیزوں کو بیان کرتے تھےاور بہت نُدرت کے ساتھ۔ مطلب، اُن کا شاید ہی کوئی شعر یا کوئی نظم ایسی ہو گی جس میں نُدرت کا پہلو نہ پایا جائے۔ یہ اب فوت ہو گئے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے۔ یہ جو لوگ تھے یہ سب مجھ سے عُمر میں بڑے تھے۔ میری عُمر کے لوگوں میں ثروت حسین (1949ء تا 1996ء) تھے، (ثروت حسین کے چھوٹے بھائی) شوکت عابد تھے، انورسن رائے (پ 1950ء) وغیرہ تھے۔ یہ لوگ جو میری عُمر کے نوجوان تھے یہ بھی بہت تخلیقی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اللہ کا شکر ہے میرا اِن سب لوگوں سے فرداً فرداً دوستی کا تعلق تھا اور آج بھی ہے۔ مطلب، انور سن رائے وغیرہ یہ میرے لیے بھائیوں کی طرح ہیں اور آج بھی ہیں۔
لیکن میرا جو سب سے زیادہ تعلق تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے بغیر مَیں رہ نہ سکتا، وہ تھے رئیس فروغ صاحب۔ رئیس فروغ صاحب سے، مطلب، مجھے ایسی محبّت تھی اب سوچوں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اشارہ کر دیتے تو میں خوشی خوشی اپنی جان دے سکتا تھا۔ ایسی محبّت ظاہر ہے کہ زندگی میں کم لوگوں سے ہوتی ہے۔ تو وہ ایسے تھے۔ یہ جو رئیس فروغ صاحب ہیں جن کا آج ہم ایک دو تین شعر سنائیں گے ان شاءاللہ۔ اُس تھوڑی بہت گفت گُو کریں گے۔ اِن میں دو اور صاحب کم از کم ایسے تھے میں اُن کا کہہ سکتا ہوں کہ رئیس فروغ صاحب سے جس قرب تک مَیں پہنچا ہوں کوئی پہنچا سوائے قمر جمیل صاحب کے۔ قمر جمیل صاحب تو اُن کے گُرو تھے۔ وہ ابھی بتاتا ہوں اُن کے تعلق کا (کہ) کیا تھا۔
یہ جو رئیس فروغ صاحب جو ہیں اِنھیں ہم لوگ دادا کہا کرتے تھے۔ اِن کو قمر جمیل صاحب نے دادا کہہ کے مخاطب کرنا شروع کر دیا تو ہم لوگ بھی کہنے لگے۔ دادا مطلب یعنی بھائی کے معنی میں۔ اِن کی انتہائی خلوت اور اِن سے انتہائی رازداری کا تعلق رکھتے ہوئے دو چیزیں مَیں نے اِن کی دیکھیں جن کی خلاف ورزی کا ایک واقعہ بھی میرے عِلم اور مشاہدے میں نہیں ہے۔ وہ ہیں انکسار اور غیبت سے مکمل پرہیز۔ اب آپ خود سوچیے کہ انکسار اور غیبت سے پرہیز، یہ اولیا اللہ کے اوصاف ہیں، اللہ کے دوستوں کے اوصاف ہیں۔ کُجا یہ کہ ہوٹلوں میں بیٹھنے والے ایک شاعر کو یہ نصیب ہوں۔ میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو غیبت سے اتنا پرہیز کرتا ہو۔ مَیں اُنھیں اُکساتا تھا کہ فلاں آپ کا مخالف (ہے)، فلاں آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے۔ کیوں کہ اُس زمانے میں جھگڑے بہت ہوتے تھے شاعروں کے، تو مسکرا کے کہتے تھے کہ چھوڑو یار۔ یا اُس کی کوئی تعریف کر دیتے تھے۔ اس طرح نہیں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، غیبت میرے سامنے نہ کرو۔ بالکل اس طرح کا کوئی تاثر نہیں دیتے تھے۔ ہنسنے لگتے تھے (یا) کوئی اور بات شروع کردیتے تھے، یا جِس کی میں غیبت کررہا ہوتا تھا اُس کی تعریف میں کوئی جملہ کہہ دیتے تھے۔ یا کہتے تھے کہ یار ہم لوگ اب اپنی باتیں کریں، چھوڑو جو کرتے ہیں کرنے دو۔ اِس طرح کا اُن کا رویہ ہوتا تھا اور یہ رویہ بھی انکسار کے ساتھ ہوتا تھا۔ اِس طرح نہیں کہ مَیں چلو غیبت سے بچ رہا ہوں لیکن میں غیبت سے اُتنا بچ نہیں رہا جتنا بچنے کا دِکھاوا کر رہا ہوں اور بچنے کا میرا انداز ایسا ہے کہ مَیں بہت بڑا آدمی ہوں، اِس طرح کی گھٹیا باتوں میں نہیں پڑ سکتا۔ یہ اُن میں بالکل نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ میرے والد صاحب کی عمر کے ہوں گے۔ مَیں اُن کے آگے اُن کی اولاد جتنا تھا، تو مَیں باتونی تھا اُن کے سامنے اِدھر اُدھر کی تقریریں کرتا رہتا علمی اور ادبی، اپنی دانست میں، اور وہ گھنٹہ گھنٹہ خاموش بیٹھتے اور بیچ بیچ میں مُسکرا مُسکرا کے یا واہ واہ کہہ کے گفت گُو سنا کرتے تھے، بالکل جاہلانہ گفت گُو، اور پھر دوسروں میں تعریف کرتے تھے۔ یہاں تک کہتے تھے کہ فُلاں نے مجھے یہ سکھایا۔
خیر، انتہائی نرم گفتار اور جیسے مٹھاس سے بھرے ہوئے آدمی تھے۔ ہمارے مرحوم دوست ممتاز رفیق نے اِن کا خاکہ لکھا ہے۔ اُس کا عنوان رکھا ہے ”کپاس کا پھول“۔ اِس کی ایک صوری مشابہت بھی ہے کہ اِن کے بال گھنے تھے آخری عُمر تک اور بالکل سفید تھے، تو اس کی نسبت سے بھی وہ کپاس کا پھول تھے۔ نرمی کی اور خوب صورتی کی جہت سے بھی وہ کپاس کا پھول تھے۔ ایسے ایسے ٹکراؤ رکھنے والے معمولات کو وہ گویا ایک کر لیتے تھے کہ حیرت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر زیادہ وقت اُن کا گھر سے باہر گزرتا تھا اور رات کو دیر سے وہ گھر جاتے تھے۔ قمر جمیل صاحب جہاں ہیں وہاں وہ ہیں۔ تو کبھی ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں کبھی قمر جمیل صاحب کے گھر بیٹھے ہیں۔ بس اُن کا (معمول) ہوتا۔ رات کو دیر سے گھر جاتے تھے لیکن انتہائی ذمہ دار والد تھے، انتہائی شفیق شوہر تھے۔ غرض ایک صاحبِ خانہ کو، ایک سربراہِ خانہ کو جو ذمہ داریاں پوری کرنی چاہییں گھر کی وہ یہ اَحسن اور آئیڈیل طریقے سے پوری کرتے تھے۔ اِن کے بیوی بچے اِن سے بہت خوش رہا کرتے تھے، بہت مطمئن۔ جب کہ معمول یہ تھا کہ رات کو گئے، صبح پھر دفتر۔ اِن میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جو ہر طرح کی سچویشن میں اِن سے بہترین کردار ادا کرواتی تھی۔ یہ لوگ بھی کم ہوتے ہیں۔ اِن کے بچے تو جیسے اِن پر جان نچھاور کرتے تھے اور اِن کے سب دوستوں کا آج بھی بہت ادب کرتے ہیں، رئیس فروغ صاحب کے بیٹے بل کہ پوتے بھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اِن کے بچے ہی نہیں بل کہ آگے کی نسلیں بھی اِن کی ڈالی ہوئی روایت کو نبھا رہی ہیں۔ بہت اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے لگتا ہے کراچی کا حافظہ یا تو کمزور ہے یا کراچی میں بعض اسباب کی وجہ سے تعلق کی صلاحیت کمزور پڑچکی ہے کہ اب کراچی میں بھی اِن حضرات کا نام لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ اِن خضرات کو یاد کرنے والی مجلسیں نہیں ہوتیں اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر۔ جیسے وہ ضمیر علی بدایونی صاحب کا مَیں نے عرض کیا کہ اُن جیسا ماہر جدید فلسفے کا خصوصًا وجودیت کا اور وجودیت کی روایت میں produce ہونے والے شعر و ادب کا اتنا بڑا جاننے والا آج تک مَیں نے نہیں دیکھا اور (اُنھوں نے ) بہت ہی زبردست کہانیاں بھی لکھی ہیں existentialism (وجودیت) کی ادبی روایت میں۔ بہت زبردست آدمی تھے لیکن یہ کہ جب اُن کا انتقال ہوا تو جنازے میں بہت ہی بوڑھے لوگ شریک تھے۔ تو یہ بہت زیادہ لگتا ہے کہ کراچی جو ہے اندر سے dehumanize (غیر انسانی) ہوتا جا رہا ہے اور یہ سمجھیں کہ یہ عمل الطاف حسین کی وجہ سے بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا۔
خیر ہمارے فروغ بھائی جو ہیں نظم کے بھی بہت اچھے شاعر، غزل کے بھی نہایت عمدہ شاعر، لیکن ان کے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ قمر جمیل سے عمر میں کچھ بڑے ہی ہوں گے۔ اچھی خاصی عُمر میں یہ کے پی ٹی (کراچی پورٹ ٹرسٹ) میں ملازمت کرتے تھے۔ اُس زمانے میں یہ قمر جمیل صاحب سے ملے۔ قمر جمیل صاحب تو جیسے خطابت کرتے تھے۔ جیسے ہمارے سلیم احمد گفت گُو کے آدمی تھے۔ قمر جمیل کے یہاں بیٹھنے والا سامع ہوا کرتا تھا۔ اُن سے مکالمہ مشکل تھا کیوں کہ وہ بالکل خطیبانہ آہنگ میں بات کیا کرتے تھے جس میں وہ تجدید یا اختلاف یا اضافے کی کوئی گنجائش ہی روا نہ رکھتے تھے۔ پھر باتوں کو انتہائی پُر تاثیر اور خوب صورت بنانے کے فن میں اُن کی برابری کرنے والا اُس وقت کوئی نہیں تھا۔ بہت خوش گوار گفت گُو کرتے تھے اور مجذوبانہ خطابت تھی اُن کی۔ یہ جب اُن سے ملے تو مشاعروں میں پڑھا کرتے تھے۔ روایتی قسم کے شاعر تھے۔ اِن کا اُس زمانے کا، قمر جمیل سے ملنے سے پہلے زمانے کا، ایک شعر سناتا ہوں جو بہت مشہور ہے کہ
اپنے حالات سے میں صلح تو کر لوں لیکن/ مجھ میں روپوش جو اِک شخص ہے مر جائے گا (یا مجھ میں پوشیدہ جو اِک شخص ہے مر جائے گا)
یہ بہت مشہور شعر ہے اُن کا۔ (مشہور) تھا۔ اب تو لوگوں کا نہیں کہہ سکتے کہ ہے یا نہیں۔ اِس طرح کے وہ شاعر تھے اور مشاعروں میں بہت زیادہ داد حاصل کرتے تھے۔ ان کی شاعری اس طرح کی تھی۔ قمر جمیل صاحب تو جس سے بھی ملتے تھے اُن کا واحد اصرار اس بات پر ہوتا تھا کہ جدید بنو، جدید شاعری کرواور جدید وہی سب realist شاعری۔ اب لوگ کہاں وہ جدید وغیرہ کرتے، وہ انگریزی الفاظ وغیرہ غزلوں میں استعمال کرنا شروع کر دیتے تھے۔ رئیس فروغ صاحب تو بے چارے بہت دھیمے، بہت submissive آدمی تھے، تو وہ ظاہر ہے قمر جمیل کے trance میں آ گئے۔ مطلب، قمر جمیل سے اِتنا اثر مَیں نے کسی دوسرے کو قبول کرتے نہیں دیکھا۔ اُنھوں نے پورا اپنا جو شعری دروبست اور شعری مزاج ہے اُس کو بدل دیا۔ وہاں اُن کے جتنے مضامین تھے (یعنی) قمر جمیل صاحب کی دلچسپی کے مضامین تھے اُن سب کو غزلوں میں کھپا کے دکھایا اور اِس طرح کھپایا کہ اُن اشعار کی روایت پسند لوگ بھی تحسین کرتے تھے۔ جیسے وہ (شعر ہے کہ )
سڑکوں پہ گھومنے کو نکلتے ہیں شام سے/آسیب اپنے کام سے ہم اپنے کام سے
اِس (شعر) کو سلیم احمد بہت پسند کرتے تھے۔ سلیم احمد شعریات میں روایتی آدمی تھے۔ وہ کہتے تھے عجیب شعر کہا ہے بالکل۔ ویسے بھی روایتی اِن کا دَور ہو یا جدید شاعری کا دَور ہو، اِن کے یہاں originality مضمون میں بھی ہوتی تھی اور image میں بھی ہوتی تھی۔ مطلب، اتنی اچھی imagery جدید شاعروں میں کم دکھائی دیتی ہے جو اِن کے یہاں ہے۔ ابھی تو وہ عرض کروں گا جس شعر پر تھوڑی سی گفت گُو کرنی ہے کیوں کہ بھئی، میرا ایک جذباتی مسئلہ ہے۔ مَیں نہ اپنے بڑوں کو بھولنا چاہتا ہوں اور نہ اپنے چھوٹوں کو اِس طرح دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے بڑوں کو یاد نہ رکھیں۔ بس اُسی کا بہانہ آج نکالا ہے۔
جو میں کہہ رہا تھا کہ امیجری، احساس کی نرمی اور تازگی یعنی ان کا احساس وزنی اور پیچیدہ نہیں ہوتا۔ بہت loaded (لَدا ہوا) احساس نہیں ہے کہ غم بہت زیادہ ہے، غصہ بہت زیادہ ہے، خوشی بہت زیادہ ہے۔ بالکل نہیں، (بل کہ) ایسا لگتا ہے جیسے احساسات ہم سے باہر بھی موجود ہیں اور اُن کے ہونے کا ایک الگ نظام چل رہا ہے۔ رئیس فروغ صاحب کی شاعری میں احساسات کا کردار کچھ اِس طرح ہوتا ہے۔ مطلب، اُس احساس میں جو ایک تازگی ہوتی ہے وہ تو ہم فوراً محسوس کر لیتے ہیں کہ یار، اِس طرح محسوس کرنا تو ہمیں نہیں آتا تھا۔ لیکن ایک فرحت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اُس احساس میں جو نُدرت ہوتی ہے اُس کو ذرا غور کریں تو وہ بھی سامنے آ جاتی ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ ایک شخص کی بنائی ہوئی تصویریں بھی منفرد ہوں اور ایک شخص کا جو احساساتی دروبست ہے، تانابانا ہے شاعری کا، وہ بھی بہت لطیف ہو؛ بہت سُبک ہو؛ بہت تازہ ہو؛ اور جیسے ایسا ہو کہ بہت impersonalized (غیر شخصی) ہو۔ مطلب یہ کہ اِن کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ احساسات کی حرکت جیسے تھمتی نہیں ہے۔ (بل کہ) جہاں یہ اپنا حوالہ بھی اگر دیں ناں تو اِن کا حوالہ زائد معلوم ہوتا ہے۔ مطلب، وہ احساسات کو بالکل شخصیتوں کے طوق سے نکال دیتے ہیں، آزاد کروا دیتے ہیں۔ کچھ شعر میں ویسے سناتا ہوں، پھر وہ قابل فخر شعر ہے بعد میں سناؤں گا۔ اب اِن دونوں پہلوؤں یعنی احساس اور image سے دیکھیے گا۔
آج کی رات کوئی بیراگن کسی سے آنسو بدلے/ گیبہتے دریا اڑتے بادل جہاں بھی ہوں ٹھہرا دینا
آپ نے دیکھا کہ اس احساس کا کوئی subjective source (موضوعی ماخذ) نہیں ہے۔ یہ جیسے احساسات کا بھی ایک نظام چل رہا ہے اور واقعات کا بھی ایک نظام چل رہا ہے اور ایک آدمی اِن سب سے باہر بیٹھا ہوا اُن کے درمیان balancing کر رہا ہے۔ اُن کے توازن کو برقرار رکھ رہا ہے۔
ایک شعر ہے چھوٹی بحر میں (اور) ہماری عارفانہ روایت میں بھی یہ شعر کھپ سکتا ہے کہ
میں تو اُس کا سناٹا ہوں/ وہ میری تنہائی ہے
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ میرا سادہ شعور اُس کی transcendence (ماورائیت) کے احساس سے بنا ہے۔ سناٹا اس کو سمجھیں کہ اُس کی beyond Time Space transcendence جو زمان و مکاں میں نہیں سما سکتی وہ میرے دل میں سمائی ہوئی ہے۔ مَیں اُسی کی form ہوں اُس کا container ہوں۔ مطلب، میرے ہونے کا اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ میں اُس transcendence کا container بننے میں کامیابی حاصل کروں۔ وہ میری تنہائی ہے۔ یہاں تنہائی کا مطلب ایسا ہے کہ اگر رومؔی استعمال کرتے تو ایسی کرتے۔ مطلب، یہ تنہائی عام تنہائی نہیں ہے۔ یہ تنہائی خود سے بھی خالی ہے کہ مَیں اُس کے یہاں اُس کا حصہ ہوں، مَیں نہیں ہوں۔ اب جس کو بھی اَعیانِ ثابتہ وغیرہ کا فلسفہ آتا ہو وہ اِسے appreciate کرے گا۔ تو وہ میری تنہائی ہے یعنی میری transcendence اُس کے پاس ہے اور اُس کی transcendence میرے پاس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ایک جیسے ہلکا خوب صورت سا شعر جو کراچی ہی میں کہا جا سکتا تھا۔ یہ بہت شہری اور دیہاتی اور ہر طرح کی جو سچویشن ہو سکتی ہے احساسات میں بیداری پیدا کرنے والی، (تو) یہ مختلف سچویشنز کو اس طرح manage کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ شہری بن کے شعر کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے شہر کی بُو اِن میں سما گئی ہے۔ کراچی میں ایک رواج تھا کہ لوگ ایسے ہی سڑکوں پر سیر کرتے تھے۔ یہ رواج تھا ہماری نوجوانی میں۔ (کراچی صدر میں) ایلفنسٹن سٹریٹ ایک جگہ تھی اور اس طرح کے کچھ بھرے بازار ہوتے تھے وہاں بڑی خوب صورت دوکانیں وغیرہ (ہوتی تھیں) تو کراچی میں walk کا یہ تصور نہیں تھا کہ آپ باغ میں جا کے ٹریک پر walk کریں۔ (بل کہ) یہ تھا کہ آپ نکلیں گے، ایلفنسٹن سٹریٹ گھوم آئے، وکٹوریہ روڈ (عبداللہ ہارون روڈ) گھوم آئے (وغیرہ وغیرہ)۔ مطلب، کم لوگ ہوتے تھے جو دفتر سے سیدھے گھر جاتے تھے۔ مطلب، گھومتے ہوئے چلے گئے۔ بے پردگی وہاں عام تھی۔ اب اِس پس منظر میں (یہ شعر دیکھیے کہ)۔
آنکھوں کے کشکول شکستہ ہو جائیں گے شام کودن بھر چہرے جمع کئے ہیں کھو جائیں گے شام کو
کیا کہنے ہیں یعنی شہروں کا جو دیکھنا ہے وہ اِس میں سمایا ہوا ہے کہ ان کا دیکھنا melt کر جاتا ہے۔ یہ جو دیکھتے ہیں اُس کی حفاظت نہیں کر پاتے اور دوسرے یہ کہ یہاں حُسن اور عشق کا جو bipolar order ہے یہ لوگ اُس کے لائق نہیں ہیں۔ اب subjectivity (موضوعیت) دیکھیے۔ تو یہ اپنے باہر کا بیان کیا ہے اُنھوں نے اور بہت subjectivize کر کے کیا۔ اب دیکھیے ایک objectivity (معروضیت) کا بیان کر رہے ہیں اُسے subjectivize کر رہے ہیں۔
کئی دن سے کوئی آوارہ خیال/راستہ بھول رہا ہے مجھ میں
آپ ذرا کمال دیکھیں کہ اِس میں سامنے کا لفظ تھا راستہ جو مَیں پڑھتے پڑھتے رہ گیا کہ راستہ ڈھونڈ رہا ہے مجھ میں۔ اِس خیال کی منزل میرے اندر روایتی طور پر مضمون بھی بن جاتا کہ اُس خیال کی منزل میرے اندر ہے مجھ سے باہر نہیں ہے۔ تو وہ اب باہر کی سیر کر کے تھک ہار کے بالآخر میرے اندر اُتر گیا ہے اور اپنی منزل کو میرے اندر تلاش کر رہا ہے۔ یہ ایک روایتی پورے تصورِ انسان کے مطابق ایک مضمون بن جاتا۔ لیکن اِنھوں نے یہ نہیں کہا۔ انھوں نے کہا ہے کہ ’راستہ بھول رہا ہے مجھ میں‘۔ یہ بھی نہیں کہا کہ چلو، دوسرا اہم تھا کہ راستہ بھول گیا ہے مجھ میں (یا) راستہ بھول چکا ہے مجھ میں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اُس کا بھولنا جاری ہے۔ اِس میں جو ’بھول رہا ہے‘ کا phrase ہے وہ محسوس کر کے دیکھیے۔ وہ بہت ہی عجیب سا لگے گا۔ اب خیال کو میں کھولتا ہوں ذرا سا کہ اس میں شرح مقصود نہیں۔ خیال کہتے ہیں اُس form کو جس کی ٹھوس تصدیق نہ ہو پائے یعنی وہ entified form نہ ہو، اُس کی entification نہ ہوئی ہو یعنی ٹھوس اپنے سے باہر اُس form کو پایا نہیں جا سکتا (لیکن) ہے وہ form۔ یعنی وہ ذہنی دنیا کی ایک صورت ہے جو خارجی دنیا میں اپنا مترادف نہیں رکھتی۔ (آپ) خیال کو یہ سمجھیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی خیال اپنی entification کے لیے مجھ میں راستہ بھول رہا ہے۔ یعنی مجھے تو اُس نے پا لیا، میرے اندر تک تو اُسے رسائی حاصل ہو گئی۔ لیکن میرے اندر کا جو پورا ہونے کا ایک نظام ہے، میرے اندر جو حقائق کی داخلی طور پر manifested صورتیں ہیں وہ اِس خیال سے زیادہ ہیں۔ مطلب، خیال باہر موجود صورتوں سے زیادہ ہے اور میرے اندر پہلے سے موجود presences اور صورتیں جو ہیں اِس خیال سے زیادہ ہیں۔اب وہاں بیزار تھا باہر کی دنیا میں یہ خیال۔ یہ خیال سمجھیں کہ وجود کے دماغ سے اُبھرا ہے تو یہ باہر کی یعنی دنیا کی صورتوں میں گھوم گھوم کے بیزار تھا اور اندر کی دنیا میں حیران ہے۔ ’بھول رہا ہے مجھ میں‘ اِس میں حیرانی ہے۔
دو تین شعر اور سن لیں۔
کچھ اتنے پاس سے ہو کر وہ روشنی گزری/کہ آج تک در و دیوار کو ملال سا ہے
اِس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نُدرت کتنی ہے۔ ابھی تک جتنے شعر مَیں نے پڑھے ہیں اُن میں آپ نے نُدرت کو احساس اور تصویر دونوں سطحوں پر ان شاءا للہ محسوس کیا ہو گا۔ اب اِس (شعر) میں دیکھیے کہ بالکل سادہ الفاظ ہیں اور image making پینٹنگ کی طرح نہیں لیکن image بناتی ہے۔ مطلب، بہت گہری تصویر نہیں بنائی۔ بہت رنگوں کو استعمال کر کے نہیں بنایا۔ ایک سادہ سی تصویر ہے لیکن وہ سادہ سی تصویر بھی ایسی ہے جو ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کی آپ عام توجیہ کر لیں، اس کا جمالیاتی تجزیہ کر لیں، تو بھی آپ ایک عجیب عالمِ تسکین میں پہنچیں گے۔ اس کا اگر آپ philosophical analysis کریں یا ہماری روایت کے مطابق عارفانہ انداز سے اس کو کھولنے کی کوشش کریں، تو یہ شعر تمام perspectives سے اپنا تجزیہ qualify کرتا ہے (یعنی) کسی بھی perspective سے۔ ہم سادہ سے perspective سے کر لیں کہ یہ منظر ہی بہت خوب صورت ہے کہ روشنی دَر و دِیوار کے پاس سے گزری اور در و دیوار کو آج بھی اُس کا ملال ہے کہ ہمیں اُس نے کیوں نہیں چھوا اور اِسی کو آپ ظہور و خفا، غیاب و شہود سب (perspective) سے کر لیں، تو تشبیہ و تنزیہہ کا پورا تصور اِس میں سے بلا تکلف اور بلا تصنع نکال سکتے ہیں۔
دو شعر اور ہیں۔ وہ ایک ہی غزل کے دو شعر ہیں۔
یادوں کی دہلیز پہ آیا/آدھا سورج آدھا سایہ
اِس میں بھی یادوں پر بہت لوگوں نے شعر کہے ہیں، یادِ ماضی پر۔ جیسے فراقؔ کا شعر بہت اچھا ہے کہ
دیکھ آئے ہم بھی یادوں کا نگر/ ہر طرف پرچھائیاں پرچھائیاں
بہت اچھا شعر ہے ۔ اور بھی لوگوں نے بہت کہا ہے اور خصوصًا 1940ء وغیرہ کے بعد nostalgic شاعری کی روایت نے زور پکڑا ہے تو یادوں پر بہت لوگوں نے شعر کہے ہیں ناصر کاظمی وغیرہ نے۔ اُن میں جو میری نظر میں بہتر شعر تھا وہ مَیں نے عرض کیا (یعنی فراقؔ کا)۔ (وہ) بہت اچھا شعر ہے اور بڑی اچھی imagery ہے لیکن (رئیس فروغ کا) یہ شعر اُس سے بھی بہتر ہے۔ فراقؔ سے کہیں آگے ہیں کیوں کہ اِس میں جیسے cosmic بنا دیا گیا ہے یاد کو۔ وہاں فراقؔ کے ہاں یادیں personal (ذاتی ) ہیں اور یہاں یادوں کو cosmic (آفاقی) بنا دیا گیا ہے۔ مطلب، اِس کا جواب کوئی نہیں ہے۔ ”آدھا سورج آدھا سایہ“ کو آپ ایک ہی کینوس پر دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کو دیکھنا سیکھنا چاہیے۔ یہ اتنی بڑی imagery ہے۔ اب سطحی تعبیر یہی ہے کہ آدھی کامیابیاں/خوشیاں بھی یاد آئیں، غم بھی یاد آئے، کامیابیاں بھی یاد آئیں، ناکامیاں بھی یاد آئیں ۔ لیکن اِس عام مفہوم کو اِس کی طرف نسبت دیتے ہوئے ہمیں شرم آئے گی۔ اس تصویر میں اتنی بڑی، اتنا کائناتی پن ہے۔ پھر یہ میری یادیں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے (لیکن) پتہ نہیں کیا ہے۔ یادوں کی اپنی کوئی کائنات ہے۔ یہ سب پہلو اِس میں سے جیسے پھوٹ پھوٹ کے ظاہر ہو رہے ہیں۔
یہ cosmic (شعر) تھا اور اب یہ دیکھیں کہ یہ personal (شعر) ہے۔
آنکھیں جو بے حال ہوئی ہیں/دیکھ لیا تھا خواب پَرایا
آنکھوں کو بے حال کہنا بہت مشکل کام ہے ۔اب اِسی سچویشن پر غور کریں تو کسی عجیب سی بنے گی کہ دوسرے کا خواب ہم نے دیکھ لیا ہے۔ بے حالی اور پرائے پن میں جو گہری نسبتیں ہیں وہ اگر دریافت کر لیں جائیں تو اِس شعر سے لطف اندوزی کی کوئی حد نہ رہے۔
(خیر) یہ تو جیسے مَیں نے تعارف میں (تمہید کہی)، ان شاءاللہ مَیں کوشش کروں گا محمد سلیم الرحمان صاحب کی نظموں پر نشستیں مکمل کر لیں رئیس فروغ صاحب پر بھی ایک سیریز کریں گے۔
جس شعر کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا وہ شعر مَیں نے بارہا سب دوستوں کو سنایا ہو گا۔ اُس کا مرتبہ متعین کرنے کے لیے جس شعر کو حوالہ بنا سکتے ہیں وہ شعر بھی میں نے عرض کیا ہوگا۔ لیکن آج جیسے مَیں اُس کو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔
نظیرؔی نیشاپوری اکثریت کی رائے کے مطابق فارسی زبان کا حافؔظ کے بعد سب سے بڑا غزل گو ہے اور حافؔظ کی روایت کا وارث ہے۔ اُس روایت میں اضافے کرنے والا ہے۔ اکثریت کی رائے یہی ہے کہ فارسی غزل کی روایت میں سب سے بڑا نام حافؔظ کا ہے اُس کے بعد نظیرؔی کا ہے جو اُسی کا فیض یافتہ ہے۔ نظیرؔی کا ایک منتخب شعر سُنا رہا ہوں۔ نظیرؔی کا یہ جو شعر مَیں سنانے جا رہا ہوں، دیوانِ نظیرؔی کا کوئی سخت سے سخت انتخاب بھی کیا جائے تو اس میں یہ شعر ضرور شامل ہو گا۔ مطلب، اُس کا کوئی کمزور شعر نہیں سنا رہا ہوں۔ وہ شعر یہ ہے کہ
ز شغلِ کارِ خودم یک نفَس رہائی نیستمحبتے کہ دہَد از خودم فراغ کجاست
مجھے اپنے جھگڑوں سے/ اپنے آپ میں مصروفیت سے ایک پَل کے لیے بھی نجات نہیں ملتی /چھٹکارا نہیں ملتا، تو وہ محبّت کہا ں ہے جو مجھے اپنے آپ سے فارغ کر دے/جو مجھے مجھ سے فارغ کر دے/آزاد رکھے۔ (یہ) بہت اچھا شعر ہے لیکن مضمون روایتی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک نظریۂ محبّت بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ چھوٹی جگہ پر کھڑے ہو کر بڑا شعر کہا ہے۔ کیوں کہ اس کو وہ جو statement of I’m-ness مطلوب ہے (لیکن) اِسے حاصل نہیں ہے۔ شعر بڑا ہے۔
اب یہی مضمون رئیس فروغ نے باندھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ شعر کہتے وقت اُنھیں نظیرؔی کے شعر کا پتہ نہیں ہو گا کیوں کہ جب مَیں نے اُن سے یہ بات کہی تو بہت حیرانی سے اُنھوں نے سُنا۔ اُنھوں نے جو کہا اُس شعر میں یہ (اہم بات ) ہے کہ نظیرؔی کا مطلوب یہاں حاصل ہے۔ نظیرؔی کے شعر اور نظیرؔی کے تجربے کی سطح آپ اُس کے مرتبے کے مطابق تصور کریں اور پھر ایک آدمی آ کر اُس کے بنائے ہوئے پڑاؤ سے آگے نکل جائے، اُس کی سطحِ اظہار سے بلند ہو کر اسی مضمون کو بیان کر دے۔ اُس مضمون کی روایتی، رسمی اور نظریاتی ساکھ کو توڑ کر اُسے اپنا تجربہ بنا کر اس طرح ظاہر کر دے کہ وہ دوسرے کو بھی پہلی نظر میں یہی محسوس ہو کہ یہ تجربہ میرا بھی ہے۔ لیکن غور کرنے پر پتہ چلے کہ یہ تجربہ مجھے ہو ہی نہیں سکتا۔ کہہ سکتے ہیں کہ گویا نظیرؔی نے مضمون شروع تو کیا، رئیس فروغ نے ختم کیا۔ اِن دونوں شعروں کی تاثیر، مضمون اور معنویت میں بہت فرق ہے۔ رئیس فروغ کا مضمون بہت آگے ہے۔ اب وہ شعر سُنیے۔
عشق وہ کار مسلسل ہے کہ ہم اپنے لیے/ایک لمحہ بھی پس انداز نہیں کر سکتے
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا جو حال ہوتا ہے وہ de-attachment کے ساتھ بیان ہوتا ہے۔ سب سے بڑی subjectivity کو object بنا کر بیان کرنا پڑتا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ عشق جو سب سے بڑا حال، سب سے بڑی state of being ہے تو اُس کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ”کارِ مسلسل“ ہے۔ یعنی عشق اصل میں تو حالِ مسلسل ہے تو حالِ مسلسل کہنا ہی نہیں (بل کہ ) اُس کا جو براہ ِ راست نام اُس کو دینا، اُس کو چھپا لینا ہے تو اُس کے لیے باہر موجود علامت کو دلالت کے طور پر استعمال کرنا۔ وہ گویا (یہاں ہے)۔ اب عشق حال ہے اُس کو فعل بنا کر دکھایا ہے اور فعل اس طرح دکھایا ہے کہ پڑھنے والا اُس کو فعل سمجھنے کی جرات نہیں کر سکتا /غلطی نہیں کر سکتا۔ عشق وہ ہے جو اعلیٰ اور ادنیٰ کو ایک دوسرے سے معنوی یکجائی کے عالم میں پہنچا دیتا ہے۔ باقی یہ کہ آپ لوگ بھی اِس پر غور کیجیے۔ آپ لوگوں کو بھی یاد ہو گا (یا پھر یاد ہو جائے گا) یہ شعر۔
اِس کا بس یہ پہلو ہی عرض کرنا تھا تاکہ ہمیں بھی تھوڑا اپنے لوگوں پر فخر ہو کہ نظیرؔی کو بھی کراس کر جاتے ہیں اور کراس کر جانا قمر جمیل صاحب کا روزمرہ تھا کہ وہ سید ساجد بودلیئر کو کراس کر گیا، مَیں فراق گورکھپوری کو کراس کر گیا۔ اُسی کی یاد میں کہہ رہا ہوں کہ اِس شعر میں رئیس فروغ نے اُنھیں کراس کر دیا۔ نظیرؔی کے اس شعر کو بہرحال وہ کراس کر گیا۔ یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ مَیں کبھی کبھی جیسے سوچتا ہوں کہ جب مَیں وہاں تھا تو دبستانِ کراچی کہا جاتا تھا۔ شاعری میں ایک دبستانِ کراچی، ایک دبستانِ پنجاب یا بلوچستان یا لاہور وغیرہ۔ اب مَیں سوچتا ہوں کہ دبستانِ کراچی کی پوری تاریخ میں، پوری شاعری میں، شعری ذخیرے میں اگر دو تین سب سے بڑے شعر نکالے جائیں (یعنی) کراچی میں سب سے بڑے جو شعر کہے گئے ہیں اُن میں سے ایک شعر رئیس فروغ صاحب کا ہے۔ دُعا کریں اللہ اُن کی قبر کو اُن کی قبر کو ٹھنڈا رکھے، اُن کی قبر کو روشن رکھے، اُن کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنائے۔ آمین
(ختم شد)