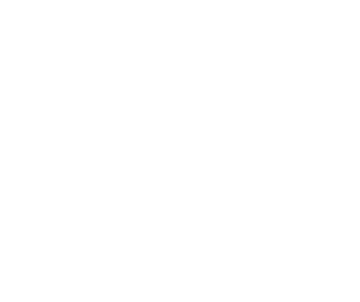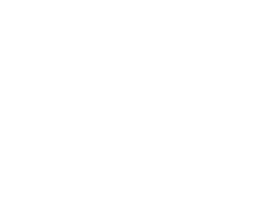ثمرِ محبوب: ہان کینگ (ترجمہ: عاصم بخشی)
۱
مئی کے آخری دنوں کی بات ہے جب مجھے پہلی بار اپنی بیوی کے جسم پر خراشیں نظر آئیں۔ ڈیوڑھی بان کے کمرے کے باہر کیاریوں میں گُلِ یاس کی ارغوانی پتیاں یوں نظر آتی تھیں جیسے باہر نکلی زخمی زبانیں ہوں ، بزرگ شہریوں کے سینٹر میں داخلی راستے کی فرشی سلیں پھولوں کی سوکھی ہوئی سفید پتیوں سے اٹی پڑی تھیں جو آنے جانے والوں کے جوتوں تلے پامال ہو رہی تھیں۔
سورج قریب قریب نصف النہار پہ تھا۔
رس بھرے شفتالو رنگ کی روشنی چھن کر بیٹھک کے فرش پر پڑتے ہوئے لاتعداد ریتلے ذرات اور زردانے نچھاور کر رہی تھی۔
نیم گرم سورج کی تلخ و شیریں روشنی میری سفید بنیان کے عقب میں پیوست ہو رہی تھی۔ میں اور بیگم اتوار کے اخبار کی ورق گردانی میں مشغول تھے۔
مہینوں سے محسوس ہوتی تھکن پچھلا پورا ہفتہ بھی بدستور قائم رہی۔ ہفتے کے اختتام پر کچھ سستانے کا وقت مل ہی جاتا لہٰذا میں ابھی چند منٹ قبل ہی جاگا تھا۔ پہلو کے بل لیٹے ہوئے میں نے آہستگی سے اپنے ناتواں اعضا کو ذرا آرام دہ حالت میں سمیٹا اور حد درجہ سست رفتاری سے اخبار پر نظر ڈالنے لگا۔
’ذرا دیکھو گے؟ نہ جانے یہ خراشوں کے نشان ختم کیوں نہیں ہو رہے۔‘
معنی خیز لگنے کی بجائے مجھے اپنی بیوی کے یہ الفاظ پردۂ سکوت میں ارتعاش پیدا کرتے محسوس ہوئے۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی جانب خالی خالی نظروں سے دیکھا۔خیر اخبار میں موجود خبر پر جس جگہ پہنچا تھا وہاں انگلی رکھی اور ہتھیلی سے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر سیدھا بیٹھ گیا۔ وہ اپنی قمیص کو انگیا تک چڑھا چکی تھی، کمر اور پیٹ پر گہری خراشیں نقش و نگار کا ایک نمونہ سا پیش کر رہی تھیں۔
’یہ کیسے ہوا؟‘
اس نے کمر کو اس حد تک بل دیا کہ میں اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے اس کی چُنٹ دار اسکرٹ کی زِ پ سے اوپر جاتے دیکھ سکتا تھا۔ کسی نوزائیدہ بچے کی مٹھی جتنی ہلکے نیلے رنگ کی خراشیں، اتنی واضح جیسے سیاہی سے پڑنے والے نقوش۔
’ بولو بھی ؟ یہ کیسے ہوا؟‘ میری تیز اصرار کرتی آواز ہمارے مختصر سے پیانگ یانگ فلیٹ کے سکوت کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔
’مجھے نہیں معلوم۔۔۔میں نے یہی سوچا کہ شاید انجانے میں کسی چیز سے ٹکرا گئی ہوں گی اور خراشیں خود بخود غائب ہو جائیں گی۔۔۔لیکن یہ تو مزید بڑھ رہی ہیں۔‘
وہ اس طرح نظریں چرا رہی تھی جیسے کوئی بچہ چوری چھپے شرارت کرتے پکڑا جاتا ہے۔ اپنے لہجے کی کاٹ پر ندامت محسوس کرتے ہوئے میں نے ذرا نرم خو لہجہ اپنایا۔
’کیا درد نہیں ہو رہا؟‘
’نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بلکہ خراشوں کی جگہ بالکل بے حس ہو گئی ہے۔ لیکن یہ تو اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات ہے۔‘
کچھ لمحے قبل نظر آنے والی ندامت کی جگہ اب ایک ہلکی سی بے محل مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ میری بیوی کے ہونٹوں پر کھیلتی وہ مسکراہٹ یہ سوال کرتی محسوس ہوتی تھی کہ کیا اسے ہسپتال جانا چاہیے؟
ساری صورت حال سے کچھ عجیب سی لاتعلقی محسوس کرتے ہوئے میں نے اپنی بیوی کے چہرے پر ایک سرد غیر جذباتی نگاہ ڈالی۔ سامنے موجود چہرہ اجنبی سا محسوس ہوتا تھا۔ نہ صرف اجنبی بلکہ تقریباً مصنوعی، گمان ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم چار سال سے ایک بندھن میں بندھے تھے۔
وہ مجھ سے تین سال چھوٹی تھی اور اِسی سال انتیس برس کی عمرکو پہنچی تھی۔ شادی سے پہلے ہم اکٹھے باہر نکلتے تو وہ شرمسار حد تک کم عمر نظر آتی، اکثر لوگ اسے کوئی اسکول کی بچی سمجھ بیٹھتے۔لیکن اب اس چہرے پر تھکن کے واضح آثار تھے جو اس کی بچگانہ معصومیت سے میل نہیں کھا رہے تھے۔ بعید از قیاس تھا کہ اب کوئی اسے اسکول کی بچی تو کیا یونیورسٹی کی طالبہ بھی سمجھتا۔ اب وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ لگتی تھی۔ کچے سیبوں کے سےرخسارجن میں ابھی سرخی آنا شروع ہوئی ہو ،گندھی ہوئی مٹی کی طرح دبے دبے تھے۔کمر جو کبھی ننھی سی شکر قندی کی طرح نرم و گداز تھی ،پیٹ جو زاویہ دار خوبصورت بل رکھتا تھا، اب قابل رحم طور پر دبلے نظر آتے تھے۔
بےساختہ وہ لمحہ ذہن میں دھندلایا جب میں نے اپنی بیوی کو آخری بار برہنہ دیکھا تھا ، یعنی اتنی روشنی میں کہ ٹھیک سے نظر آ جائے۔ اِس سال نہیں ،یہ تو خیر پکی بات تھی، میں تو پچھلے سال کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔
ایک ایسے انسان کے جسم پر موجود اتنی گہری خراشیں کس طرح میری نظر سے اوجھل رہ سکتی تھیں جس کے ساتھ میں رہتا تھا؟ میں نے اپنی بیوی کی آنکھوں کے کناروں پر موجود چمکتی شکنوں کو گننے کی کوشش کی۔ پھر اسے تمام کپڑے اتارنے کے لیے کہا۔ رخساری ہڈیوں کی سرحد پر شرم کی سرخی سی نمودار ہوئی جو اس کے گرے ہوئے وزن نے مزید نمایاں کر دی۔ اس نے دبا دبا احتجاج کیا ۔
’اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟‘
زیادہ تر فلیٹوں کی طرح جن کے سامنے کوئی باغ یا کار پارک تھا، ہماری بالکونی کا رخ مشرقی شاہراہ کی جانب تھا۔ چونکہ ہم نزدیک ترین رہائشی بلاک سے تین گلیاں دور تھے اور بیچ میں نہ صرف شاہراہ بلکہ چونگ نیانگ ندی بھی پڑتی تھی، ایک تیز ترین دوربین کے بغیر کسی کا تانکنا جھانکنا ناممکن تھا۔سڑک پر تیزی رفتاری سے رواں دواں گاڑیوں میں سے بھی کسی کو ہماری بیٹھک کی ایک جھلک ہی نظر آنی تھی۔ لہٰذا میں نے اپنی بیوی کے احتجاج کو بس شرم کی علامت سمجھا۔نئی نئی شادی ہوئی تو اسی بیٹھک میں، جس کے ایک طرف برآمدے میں جاتا ہوا شیشے کا دروازہ کھل رہا تھا اور دوسری طرف اگست کی تپش سے بھرپور گرمی کے توڑ کی خاطر کھڑکی کھلی ہوئی تھی، ہم دن دیہاڑے ایک دوسرےسے کئی کئی بار پیار میں مشغول رہتے، اناڑی پن سے اس نئے تجربے میں مصروف آخر کار تھک ہار جاتے۔
ایک آدھ سال گزرا تو محبت کے ان اولین تجربات کی شدت بتدریج ماند پڑ گئی۔ میری بیوی جلد سونے چلی جاتی ، اس کی نیند غیر معمولی طور پر گہری تھی۔ اگر رات کو دیر سے گھر لوٹتا تو مجھے یقین ہوتا کہ وہ پہلے ہی سو چکی ہو گی۔ داخلی دروازے کے تالے میں چابی گھما کر فلیٹ میں قدم رکھتا تو خوش آمدید کہنے کے لیے کوئی موجود نہ ہوتا،نہا دھو کر اندھیرے بیڈ روم میں داخل ہوتا تو اس کے سانسوں کا اتار چڑھاؤ مجھ پر ایک انوکھی سی مغمومیت طاری کر دیتا۔ تنہائی کو ختم کرنے کی امید پر بغل گیر ہوتا تو اس کی نیم وا نیند سے بھری آنکھیں بالکل سراغ نہ لگنے دیتیں کہ آیا وہ میری گرم جوشی کو دھتکار رہی ہے یا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ وہ صرف اپنی خاموش انگلیاں میرے بالوں میں پھیرتی رہتی یہاں تک کہ میرا جسم ساکت ہو جاتا۔
’سب کچھ؟ تم چاہتے ہو کہ میں سب کچھ اتار دوں؟‘
آنسو روکنے کی کوشش کرتے شکن دار چہرے کے ساتھ میری بیوی نے ابھی ابھی اتارے ہوئے زیر جامے کا گیند سا بنا کر ایک طرف لڑھکایا اور اپنے پشمی حصے کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔
سو یہ تھا اس کا برہنہ جسم، بہار کی دھوپ میں پوری طرح کُھلا ہوا۔واقعی کافی عرصہ ہو گیا تھا۔
اس کے باوجود مجھ میں خواہش کی ہلکی سی گدگداہٹ بھی نہ تھی۔ نہ صرف اس کے کولہوں بلکہ پنڈلیوں اور پسلیوں ، یہاں تک کے رانوں کی اندرونی سفیدی تک کو داغدار کرتی زردی مائل سبز خراشیں دیکھ کر مجھے غصہ نے جکڑ لیا۔ پھر اتناہی اچانک، یہ طیش اپنی پکڑ کو کمزور کرتا، اپنےپیچھے ایک ناروا دل شکستگی چھوڑ گیا۔ کیا ہمیشہ خیالوں میں گم رہنے والی اس عورت کے ذہن سے نیند نے ایک شام گلی میں نکل جانے کی یاداشت تک محو کر دی ہے؟ ممکن ہے نیند میں مدہوش، کسی سست رفتار گاڑی سے ٹکرا گئی ہو یا پھر پیر پھسلنے سے ہماری رہائشی عمارت کی ان اندھیری سیڑھیوں سے نیچے لڑھک گئی ہو جو کسی ہنگامی صورت حال کے لئے تعمیر کی گئی ہیں؟
اپنے جسم کے زیریں حصے کو ہاتھوں سے چھپائے، کمر پر اختتامِ بہار کی سورج کی دھوپ سمیٹے ، مجھ سے گم سم حالت میں ہسپتال جانے کا سوال پوچھتی میری بیوی کی تصویر اتنی غمگین، بدنصیب اور الم ناک تھی کہ میں کچھ بھی نہ کہہ سکا اور مجھے ایک ایسی شدیداداسی نے آ لیا جو میں نے نہ جانے کب سے محسوس نہ کی تھی۔ میں بس اس کے دبلے پتلے نازک جسم کو بازؤوں ہی میں بھر سکا۔
۲
میں نے سوچا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔اسی لیے بہار کے اس دن اپنی بیوی کا لاغر ڈھانچہ بانہوں میں لیتے ہوئے بولا،’اگر خراشیں تکلیف کا باعث نہیں تو پھر جلد ہی غائب ہو جائیں گی۔ تم تو کبھی ایسے مسائل کا شکار نہیں ہوتی، اس مصیبت میں کیسے پھنس گئی؟‘ لہجے کو ذرا نرم کرتے ہوئے میں نے رسمی سا قہقہہ لگایا۔
آغازِ گرما کی ایک رات گرم مرطوب ہوا اپنے چپچپاتے رخسار قدآور انجیرِ توت کے پتوں سے رگڑ رہی تھی اور گلیاں اپنی لال بھبوکا آنکھوں سے جگمگا رہی تھیں۔ کھانے کی میز پر سامنے بیٹھی میری بیوی نے اپنا چمچ تھالی میں پھینک دیا۔ اُس کی خراشیں میرے ذہن سے بالکل نکل چکی تھیں۔
’بھئی یہ تو کچھ عجیب سی حالت ہے۔۔۔ذرا دیکھنا تو۔‘
اپنی مختصر آستینوں سے نمودار ہوتے مریل بازوؤں کا معائنہ کرتے ہوئے میری بیوی نے فوراً اپنی ٹی شرٹ اور انگیا اتار دی۔ میرے منہ سے ایک ہلکی سی آہ نکل کر رہ گئی۔
خراشیں جو پچھلی بہار میں کسی نوزائیدہ بچے کی مٹھی جتنی تھیں اب تارو کے بڑے بڑے پتوں جتنی ہو چکی تھیں۔اس پر یہ کہ سیاہی مائل بھی تھیں۔ بیدِمجنوں کی شاخوں کی طرح بے چمک ، جس کی زردی مائل سبز رنگت گرما کی آمد کے ساتھ ہی ہلکی سی نیلاہٹ آمیز محسوس ہوتی ہے۔
کانپتا ہاتھ بڑھا کر اپنی بیوی کے خراشوں بھرے شانے کو تھپتھپایا تو یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی اجنبی جسم کو چھو رہا ہوں۔ یہ خراشیں کتنی تکلیف دہ ہوں گی؟
اب جومیں نے ذرا غور کیا تو نظر آیا کہ اس دن میری بیوی کا چہرہ بھی یوں نیلا ہو رہا تھا جیسے تیزابی پانی سے رنگا ہو۔ بال جو کبھی چمکدار ہوتے تھے اب مولی کے پتوں کی طرح سخت اور خشک تھے۔ آنکھوں کی سفیدی پر زرد بنفشی دھند کے سائے تھے جیسے اُس کی غیرمعمولی سیاہ پتلیوں کی سیاہی نکل کر بہہ گئی ہو۔ آنکھیں نمی سے چمک رہی تھیں۔
’میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ باہر جانے کا دل کرتا ہے لیکن جونہی باہر پہنچتی ہوں۔۔۔جیسے ہی سورج کی روشنی پر نظر پڑتی ہے، فوراً کپڑے اتار دینے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے میرا جسم لباس سے جدا ہونا چاہتا ہے۔ ‘ میری بیوی اٹھ کر کھڑی ہو ئی اور مجھے گزرے برس میں اپنے لاغر وجود ی ڈھانچے کا سب سے مکمل نظارہ پیش کیا۔ ’پرسو ں تن پر کسی کپڑے کے بغیر میں باہر بالکونی میں جا نکلی اور واشنگ مشین کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سوچے سمجھے بغیر کہ کوئی مجھے دیکھ لے گا۔۔۔خود کو چھپانے کی کوشش کے بغیر۔۔۔ میرا مطلب ہے جیسے کوئی پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہو!‘
میں گم سم اپنے ہاتھ میں موجود چاپ اسٹکس کے کناروں پر عالمِ اضطراب میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنی بیوی کے لاغر جسم کے اوپری حصے کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا ۔
’بھوک بھی مر چکی ہے۔معمول سے زیادہ پانی پی رہی ہوں۔۔۔پورے دن میں چاولوں کا ایک پیالہ بھی نہیں کھایا جاتا۔ شاید نہ کھانے ہی کی وجہ سے میرے معدے کی تیزابیت بھی دور نہیں ہوتی۔ خود پر جبر کر کے کچھ کھا بھی لوں تو ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتا اور بار بار قے آتی ہے۔ ‘ وہ گھٹنوں پر گری کسی ایسی کٹھ پتلی کی طرح اپنا سر میری گود میں رکھ چکی تھی جس کی ڈوریاں کٹ چکی ہوں۔ یقیناً وہ رو تو نہیں رہی تھی؟ میرے پاجامے کے پائنچوں تک ایک گرم مرطوب دھبا بنتا جا رہا تھا۔
’تمہیں معلوم بھی ہے کہ ایک دن میں کئی بار قے کرنا کیسا لگتا ہے؟ یوں جیسے ٹھوس زمین پر کھڑے کھڑے انسان ہچکولے کھانے لگے اور ابکائی آ جائے، بندہ کبڑا ہو جاتا ہے، سیدھا کھڑے ہونا ممکن نہیں رہتا۔ سر درد سے یوں پھٹتا ہے۔۔۔جیسے دائیں آنکھ اس میں سوراخ کر رہی ہو۔ کاندھے کسی چوبی تختے کی طرح اکڑ جاتے ہیں، فرشی سلوں پر ، سڑک کے کنارے موجود درختوں کی جڑوں میں آپ زرد تیزابی مادہ تھوکتے رہتے ہیں۔۔۔‘
جلتے بجھتے فلوری لیمپ سے کسی کیڑے کے ہُوکنے کی اونچی آواز سنائی دی۔ اس کی دبیز روشنی میں اپنی کمر پر کیٹلپا پتے جتنی خراش لیے میری بیوی نے اپنی رندھی ہوئی آواز کو دبانے کی کوشش کی۔
’ہسپتال جاؤ،‘ ،میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ’کل ہی سیدھے داخلی علاج کے شعبے کا رخ کرو۔‘
اس کا نم آلود داغ دار چہرہ بدزیب ہو چکا تھا۔اس کے اکڑے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ’اور دیکھو دھیان سے جانا۔ دوبارہ اپنے آپ کو زخمی نہ کر لینا۔ اب تم کوئی بچی نہیں کہ اِدھر اُدھر چیزوں سے ٹکراتی، گرتی پڑتی رہو۔‘
میری بیوی کے گیلے چہرے پر ایک کپکپاتی ہوئی مسکراہٹ آئی اور ہونٹوں سے چپکے ایک تنہا آنسو نے دراز ہوتے ہوئے خود کو علیحدہ کر لیا۔
۳
کیا میری بیوی ہمیشہ اسی طرح آنسو بہاتی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پہلی دفعہ اسے روتے دیکھا تو وہ چھبیس برس کی تھی۔
نوجوانی میں اسے ہنسانا زیادہ آسان تھا، اس کی آواز ہمیشہ ایک زیر لب تازگی لیے ہوتی، ہنسی جیسے رنگوں کی پھوار۔ اکثر مجھے اس آواز کی پرسکون بلوغت اس کی نوجوان شکل و صورت سے متضاد لگتی۔ جب پہلی بار تھرتھراتے ہوئے لہجے میں وہ یوں گویا ہوئی،’ مجھے سانگی ڈانگ کی فلک بوس عمارتوں میں رہنا پسند نہیں۔‘
’ ایک دوسرے میں دھنسے ہوئے سات لاکھ انسان ، یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں دم گھٹنے سے جان دے دوں گی۔ سینکڑوں ہزاروں یکساں عمارتوں سے گھن آتی ہے، ایک جیسی چھتیں، ایک جیسے بیت الخلا، نہانے کے ٹب، بالکونیاں اور لفٹیں، باغیچے، قیام و آرام کی جگہیں، دکانیں اور فٹ پاتھ۔ مجھے ان سب سے نفرت ہے۔‘
’ہائیں! ایسی بھی کیا قیامت آ گئی؟‘ اپنی بیوی کی بات کی بجائے اس کے لہجے کی نرمی پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے میں نے کسی زود رنج بچے کو بہلانے کے سے انداز میں کہا۔’بہت سے لوگوں کے ایک دوسرے کے قریب رہنے میں آخر ایسی بھی کیا برائی ہے؟‘
اُن آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میرا انداز ذرا درشت رُو سا تھا۔اس کی آنکھیں جلتی بجھتی سی محسوس ہوتی تھیں۔
’میں ہمیشہ یہی کوشش کرتی کہ جو بھی کمرے کرائے پر حاصل کیے جائیں وہ شہر کی رونقوں کے قریب ہوں۔ لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی جگہیں، گلیوں میں موسیقی کا شور شرابا اور سڑکوں پر ہارن بجاتا گاڑیوں کا ازدہام میرے لئے کشش رکھتا تھا۔اس کے بغیر زندگی بے معنی تھی۔ تنہائی جان لیوا تھی۔ ‘ میری بیوی جس تیزی سے اپنے رخساروں پر بہتے آنسو ہتھیلی کے پچھلے حصے سے صاف کیے جا رہی تھی ، اسی بہاؤ سے مزید ان کی جگہ لے رہے تھے۔’اور اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی موذی مرض کا نشانہ بننے والی ہوں۔ جیسے میں کبھی اس تیرہویں منزل سے نیچے نہ اتر پاؤں گی، جیسے میں کبھی باہر نہ نکل سکوں گی۔‘
’ بھئی کیوں رائی کا پہاڑ بنا رہی ہو؟ اب یہ اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں۔‘
ان اونچے فلیٹوں میں ہمارے پہلے سال کے دوران میری بیوی اکثر بیمار رہتی۔وہ سیٔول کے پہاڑی علاقوں کے فطری ماحول میں کرائے کے کمروں کی عادی تھی اور مرکزی طور پر برقی نظامِ حدت سے گرم کیے جانے والے اس چاروں جانب بند فلیٹ میں دم پخت رہنا اس کے جسم کے لیے ناقابلِ برداشت معلوم ہوتا تھا۔ جلد ہی اس کی جسمانی قوت اس حد تک گر گئی کہ بس دن میں ایک بار عمودی چڑھائی پر تیز قدموں سے چلتے ہوئے اُس اشاعتی ادارے کے دفتر تک پہنچ سکتی تھی جہاں وہ چھوٹی سی تنخواہ پر ملازم تھی۔
لیکن اُس کے نوکری چھوڑنے کی وجہ ہماری شادی نہیں تھی۔نوکری چھوڑنے کے بعد، بلکہ بہت عرصے بعد میں نے اس سے واضح لفظوں میں شادی کی بات کی۔ وہ اپنی تمام جمع پونجی بشمول ماہانہ تنخواہ، پینشن الاؤنس اور ہفتے کے آخر میں ہونے والے زائد جزوقتی کام کی رقم جوڑ کر ملک چھوڑنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔
’مجھے اپنی رگوں میں تازہ خون کی ضرورت ہے،‘ اس نے کہا۔ یہ وہ شام تھی جس دن اس نے اپنے افسر بالا کو استعفی تھمایا تھا۔اس نے مجھے یہی کہا کہ وہ اپنی رگوں میں جمع شدہ گندا خون خارج کر دینا چاہتی ہے اور اس کے تھکے ہوئے ضعیف پھیپھڑے تازہ ہوا کے متمنی ہیں۔ کہتی تھی کہ بچپن ہی سے اس کا خواب آزاد جینے مرنے کا ہے ، اس کی تعبیر کو بوجوہ مؤخر کرتی آئی تھی لیکن اس کے خیال میں اب وہ اتنا سرمایہ جمع کر چکی تھی کہ یہ خواب حقیقت میں بدل سکتا تھا۔ منصوبہ یہی تھا کہ وہ کسی ایک ملک کا انتخاب کرے گی، وہاں چھ سات ماہ قیام کرے گی اور پھر آگے بڑھ جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ ’تمہیں کیا بتاؤں، بس میں مرنے سے پہلے ایسے جینا چاہتی ہوں،‘ اس نے کھکھلاتے ہوئے کہا۔ ’میں دنیا کا آخری کنارہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ قدم بہ قدم دور نکل جانا چاہتی ہوں۔‘
لیکن آخر کار دنیا کی سرحد کی جانب رختِ سفر باندھنے کی بجائے میری بیوی نے اپنی تمام جمع پونجی ہمارے اس فلیٹ اور بیاہ کے اخراجات پر صرف کر دی۔ بس ایک مختصر سے جملے میں ہی اس نے پوری وضاحت کر دی،’کیوں کہ میں تم سے جدا نہیں ہو سکتی۔‘ تو پھر آزادی کا وہ خواب کتنا حقیقی تھا؟ شاید اتنا نہیں کیوں کہ وہ اتنی آسانی سے اس سے دست بردار ہو گئی۔ یہ سارا معاملہ ایک غیر حقیقی ، رومانوی سراب سے زیادہ نہیں رہا ہو گا ، اور اُس کے منصوبے بس اتنے ہی قابلِ عمل ہوں گے جتنا کسی بچے کے چاند پر جانے کے خیالی پلاؤ۔بالآخر اسے خود ہی عقل آ گئی ہو گی ۔ خود کو اس تاخیری آگہی کی وجہ جان کر میں دل ہی دل میں اپنے آپ پر ایک مبہم سا فخر کیے بغیر نہ رہ سکا۔
شاید یہ اس کا مستقل درد اور آہیں کراہیں تھیں لیکن جب میں نے اپنی بیوی کو بالکونی کے بلوریں دروازے سے رخسار لگائے، گوبھی کے مرجھائے پتوں کی طرح دبلےکاندھے لٹکائے دیکھا تو میرا دل ڈوب سا گیا۔ وہ اتنی ساکت تھی کہ صرف سانس کی نہایت مدھم آواز ہی زندگی کی بچی کھچی علامت تھی، گمان ہوتا تھا کہ کاندھوں پر دو موہوم سے بازو کس دیے گئے ہوں، جیسے کسی نادیدہ زنجیر سے منسلک کوئی جسیم آہنی گیند اسے جسم کا ایک پٹھا تک ہلانے سے روک رہاہو۔
رات گئے اور پھر صبح صادق میری بیوی سنسان گلی سے کبھی کبھار گزرنے والی کسی ٹیکسی یا موٹر سائیکل کی آواز سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی۔ ’یوں لگتا ہے کہ گاڑیوں کی بجائے سڑک تیزرفتاری سے آگے بڑھ رہی ہو، جیسے یہ فلیٹ سڑک کے ساتھ بہتا چلا جا رہا ہو،‘ وہ کہتی۔ یہاں تک کہ جب انجنوں کا شور دور فاصلوں میں کھو بھی جاتا اور نیند اسے دوبارہ آ لیتی ، میری بیوی کے خوبصورت چہرے پر موت کی زردی چھائے رہتی۔
اسی طرح کی ایک رات وہ جیسے خواب میں بڑبڑائی، اس کی گلو گرفتہ آواز بمشکل سنائی دیتی تھی: ’یہ سب کچھ کہاں سے آیا۔۔۔یہ سب کچھ کہاں بھاگتا چلا جا رہا ہے؟‘
۴
اگلی شام فلیٹ میں قدم رکھتے ہی میں نے اپنی بیوی کو دروازے پر خوش آمدید کے لیے موجود پایا، شاید اس نے برآمدے سے آتی میرے قدموں کی چاپ سن لی تھی۔ پاؤں ننگے تھے اور شاذ ونادر کترے جانے والے ناخنوں کی گولائی میں چمکتی سفیدی تھی ۔
’ہسپتال والوں نے کیا کہا؟‘
جواب ندارد۔ خاموشی سے مجھے جوتے اتارتے دیکھتے ، رخسار پر پڑی بالوں کی ایک لٹ کانوں کے پیچھے سرکاتی ہوئی وہ دوسری جانب مڑ گئی۔
اُف یہ سراپا، میں نے سوچا۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے پہلی ملاقات پر جب ہمیں ایک دوسرے سے ملوانے والا میرے دفتر کا سینئر ساتھی ہمیں تنہائی کے لمحے مہیا کرنے کے واسطے اٹھ کر چلا گیا تھا تو میں اپنی مستقبل کی شریکِ حیات کے چہرے پر یہ پراسراریت دیکھ کر کتنا مضطرب ہوا تھا۔یوں لگتا تھا کہ وہ دور کسی گمنام خفیہ جگہ پر آوارہ گردی کر رہی ہے۔پہلی نظر میں روشن اور حسین لگنے والی اس صورت میں میں ایک ایسا غیرمتوقع اکیلا پن دیکھ سکتا تھا جو کسی اور ہی شخص کا محسوس ہوتا تھا، اسی لیے مجھے ایک لمحے کو یقین سا ہو گیا کہ وہ مجھے سمجھ گئی ہے۔ پھر جب اس یقین اورشراب کے ملے جلے نشے میں یہ مجھ سے یہ اعتراف سرزدہوا کہ میں پوری زندگی تنہا رہا ہوں تو وہ چھبیس سالہ عورت جو میری بیوی بننے والی تھی اپنا چہرہ موڑ کر کسی دور دراز افق کو گھورنے لگی، بالکل ایسا ہی سرد، یاسیت بھرا سراپا جو ابھی میرے سامنے تھا۔
’تم ہسپتال گئی تھی؟‘
اس نے مڑتے ہوئے’ ہاں‘ میں ہلکا سا سر ہلایا ۔ کیا وہ اپنی بیمار صورت چھپانا چاہتی تھی یا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی؟
’کیا ہوا، خدا کے لیے مجھ سے بات تو کرو۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟‘
’یہی کہ سب ٹھیک ہے۔‘ یہ جملہ زبان کی بجائے اس کی سانسوں سےخارج ہوتا محسوس ہوا۔ لہجہ خوفناک حد تک سپاٹ تھا۔
پہلی ملاقات میں اس کی شخصیت کی سب سے پُرکشش چیز اس کی آواز تھی۔یہ ایک احمقانہ موازنہ تھا لیکن اس کی آواز نے مجھے کسی صیقل ہوئی، چمک دار چائے کی تپائی کی یاد دلا دی ، ایک ایسا فرنیچر کا فن پارہ جو آپ اہم ترین مہمانوں کی آمد پر ہی سامنے لاتے ہیں، جس پر بہترین پیالیوں میں اعلی ترین چائے ہی پیش کی جا سکتی ہے۔ اس رات بظاہر میرے اعتراف پر رتی برابر الجھن محسوس نہ کرتے ہوئے، میری بیوی کا جواب بہت اٹل اور لہجہ ہمیشہ کی طرح مطمئن تھا۔ ’لیکن میں اپنی ساری زندگی کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں گزارنا چاہتی،‘ اس نے کہا۔
اس کے بعد میں نے پودوں کا ذکر چھیڑ دیا۔ اپنے سپنوں کا گھر جس کی پوری بالکونی سبز زرکاغذی اور پودینے کے بڑے بڑے گملوں سے بھری ہو گی۔ گرمیوں میں پودینے کے پودوں پر برف کے ذرات جیسے ننھے پھول کھل رہے ہوں گے ۔ رسوئی میں لوبیے کی کونپلیں پھوٹتی ہوں گی۔ اس پر وہ ذرا کھلکھلا کر ہنسی اور مجھے شک آمیز نظروں سے ایسے گھورا جیسے پودوں کے متعلق یہ گفتگو اس تاثر سے بالکل مختلف ہو جو اس نے میرے بارے میں قائم کر رکھا تھا۔اس کمزور اور معصوم ہنستی ڈھلان سے چمٹے رہنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے اپنے وہی الفاظ دوبارہ دہرائے: ’میں اپنی تمام زندگی تنہا رہا ہوں۔‘
شادی کے بعد میں نے بالکونی میں گملے تو رکھ دیے لیکن ہم دونوں میں سے کسی کا مقدر کچھ خاص سبز نہیں تھا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی لیکن سدابہار پودے بھی جنہیں میرے خیال سے باقاعدہ سیرابی کے علاوہ کسی اہتمام کی ضرورت نہیں تھی ، ایک بھی فصل دیے بغیر مرجھا کر دم توڑ گئے۔
کسی کا کہنا تھا کہ ہمارا اوپری منزل کا فلیٹ زمین کی توانائی سے بہت زیادہ دو رہے، ایک اور صاحب کہنے لگے کہ پودے خراب ہوا اور گندے پانی کے باعث مر رہے ہیں۔ ہم پر یہ الزام بھی لگا کہ ہم زندہ چیزوں کی پرورش کے لیے قلبِ سلیم نہیں رکھتے جو کہ ایک بالکل غلط بات تھی۔ جس طرح پوری دلجمعی سے میری بیوی نے اپنے آپ کو ان پودوں کے لیے وقف کر دیا تھا وہ تمام توقعات سے بڑھ کر تھا۔ اگر کوئی سلاد یا پودینے کاپودا مرجھا جاتا تو اس پر نصف دن پژمردگی طاری رہتی، اور اگر کوئی زندگی سے مضبوطی سے چمٹا نظر آتا تو وہ ادھر ادھر گھومتے ہوئے گنگناتی نظر آتی۔
نہ جانے کیا وجہ تھی لیکن بالکونی میں پڑے مستطیل گملوں میں خشک مٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ سب مردہ پودے کہاں چلے گئے؟ اور وہ بارانی شب و روز کہاں گئے جب میں گملوں کو کھڑکیوں کی سِل پر رکھ آتا تھا تاکہ پودے ٹھنڈی بارش میں تروتازہ ہو جائیں، وہ سب جوان دن کہاں کھو گئے؟
میری بیو ی نے میری طرف مڑتے ہوئے کہا، ’چلو ہم دونوں کہیں دور نکل چلیں۔‘ پودوں کے برعکس جن میں بارش کے دوران ایک نئی روح دوڑ جاتی تھی، میری بیوی پر مزید گہری یاسیت طاری ہو رہی تھی۔ ’اس گھٹن میں رہنا ناممکن ہے،‘ اس نے اپنا لاغر ہاتھ سلاد کے پتوں کی جانب بڑھاتے ہوئے بارش کی پھوار کو بالکونی کی جانب پھینکنے کی کوشش کی۔ ’یہ بارش غلیظ ہے،‘ اس نے کہا،’رینٹھ اور تھوک سے سیاہ۔‘اس کی نگاہیں میری جانب ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے رضامندی چاہتی ہوں۔ ‘یہ زندگی تو نہیں،‘ وہ پھنکاری، ’بس ہمارا گمان ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ ‘ اس کی آواز میں اشتعال کے آثار تھے، جیسے کوئی شرابی اونچی آواز میں بڑبڑائے کہ یہ سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ’کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہاں کچھ اُگ نہیں سکتا؟ یہ گھٹن زدہ شور شرابا۔۔۔یہاں کون قید رہ سکتا ہے!‘
میری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔
’کون سی گھٹن ہے؟‘ میں اپنی نئی نویلی ڈری سہمی مسرتوں پر ہوتے یہ تابڑ توڑ حملے مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اس کے لاغر بدن سے پرانی دبی ہوئی تکلیفوں کا خون نچوڑتے وہ الفاظ اب مزید قابلِ قبول تھے۔’بولو بھی۔‘ میں نے بارش کا چلو بھر پانی اس کے شانوں پر ٹپکاتے ہوئے پوچھا۔ ’کیا گھٹن زدہ ہے؟ کیا بہرا کیے دے رہا ہے؟‘
میری بیوی کے حلق سے ایک ہلکی سی کراہ نکلی، شدید صدمے کے عالم میں اس کے ہاتھ اپنے چہرے کو نوچنے کی کوشش کر رہے تھے۔بالکونی کی کھڑکی سے میرے چہرے پر بارش کی سرد پھوار پڑ رہی تھی۔ کھڑی میں پڑا گملا بالکونی کے فرش پر گرنے سے پہلے میری بیوی کا پاؤں کچل گیا۔ ٹوٹی ہوئی ٹھیکریاں اور مٹی کے ننھے تودے میری بیوی کے کپڑوں ، اس کے ننگے پاؤں سے چمٹے تھے۔ جھک کر دونوں ہاتھوں سے اپنا زخمی پیر تھامتے ہوئے اس نے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے کاٹ ڈالا۔
ہونٹ کو دانتوں میں دبانا اس کی پرانی عادت تھی، ہماری شادی سے بھی پہلے وہ غصے کے عالم میں یا میری آواز اونچی ہونے پر ہمیشہ یہی کرتی۔ ہونٹ کے ساتھ مصروف ہونا ارتکازِ فکر میں مددگار ثابت ہوتا اور پھر کچھ دیر بعد وہ میری بات یا ہمارے درمیان کسی بھی مسئلے کے متعلق سکون سے منطقی استدلال پیش کرنے لگتی۔ لیکن اس دن بالکونی میں اس کا کٹا ہوا ہونٹ ہی اس کا واحد ردعمل تھا۔ اس دن کے بعد ہم نے کبھی بحث نہیں کی۔
’ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟‘ میں نے اپنے سینے میں تنہائی اور تھکن کی ایک شدید لہر دوڑتی محسوس کی۔ جب میں نے اپنی جیکٹ اتاری تو میری بیوی نے تھامنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔
’اس کا کہنا تھا کہ اسے تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا،‘ اس کا منہ بدستور دوسری طرف تھا۔
۵
آہستہ آہستہ میری بیوی کی بچی کھچی گویائی بھی جاتی رہی۔ جب تک بات نہ کی جاتی وہ کچھ نہ کہتی اور اس صورت میں بھی اس کا جواب ہاں یانہیں میں بس دھیرے سے سر کی حرکت ہوتی۔اگر میں اپنی آواز بڑھا کر مطالبہ کرتا کہ وہ جواب دے تو آنکھوں میں ایک موہوم سے بے توجہی بھر کر دور خلاؤں کو تکنے لگتی۔اس کے چہرے کی مسلسل بڑھتی زردی اب لیمپ کی مدھم روشنی میں بھی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔
چونکہ ڈاکٹر کہہ چکا تھا کہ اسے کسی بیماری کے آثار نہیں ملے لہٰذا میری بیوی کے معدے یا آنتوں کے ساتھ کسی مسئلے کے بجائے یہ صرف کسی ذہنی پریشانی کا مسئلہ تھا۔ لیکن اسے دنیامیں کس چیز کی تمنا کھائے جا رہی تھی؟
پچھلے تین سال میری زندگی کے سب سے پرسکون سال تھے۔ کام بہت زیادہ سخت نہ تھا۔ خوش قسمتی تھی کہ مالک مکان کرایہ بڑھانے پر اصرار نہ کرتا تھا۔ میں نئے گھر کی تمام قسطیں پوری کر چکا تھا۔ بیوی ایسی کہ نہایت حسین و جمیل نہ ہونے کے باوجود اپنے اندر ایک اچھی شریکِ حیات کے سب وصف رکھتی تھی ۔میرا اطمینان کسی بھرے ہوئے حوض میں نیم گرم ہلکے پھلکے ہچکولے کھاتے پانی کی طرح تھا جومیرے تھکن سے چور جسم کے لیے سکون بخش تھا۔
تو پھر میری بیوی کو کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ اگر واقعی کوئی خواہش اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی تو سمجھ سے باہر تھا کہ اس کی شدت اس حد تک ذہنی انتشار کا باعث کیسے ہو سکتی تھی۔ خود سے یہ سوال پوچھتے ہی کہ اس عورت کو مجھے اس حد تک تنہا کر دینے کا کیا حق تھا ، مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میرا پورا وجود ایک لاانتہا نفرت کے سیلاب میں بہتا ہوا ، ریت کی کسی قدیم تہہ کی طرح اکیلا ہوتا جا رہا ہے۔
اگلے اتوار یعنی کاروبار کے سلسلے میں ایک ہفتے کے لیے بیرونِ ملک دورے سے ایک روز قبل میں نے اپنی بیوی کو بالکونی میں کپڑے سکھاتے دیکھا۔ خراشیں اب اس کے بازوؤں کو اس حد تک بھر چکی تھیں کہ جِلد کے بچے کھچے سفید حصے اب خود نیلاہٹ کے بیچ سفید خراشوں کے دھبوں کی طرح محسوس ہوتے تھے۔ یہ نظارہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ جونہی وہ کپڑوں کی خالی ٹوکری کمرے میں لائی ، میں نے اس کا راستہ روکتے ہوئے سارے کپڑے اتارنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے کچھ پس و پیش سے کام لیا لیکن میں نے اس کی ٹی شرٹ اتار دی ، سیاہ ہلکی گہری نیلاہٹ میں رنگا ایک کاندھا میرے سامنے تھا۔
میں گھبرا کر پیچھے کی جانب لڑکھڑایا اور اس کے بدن کو گھورنے لگا۔ بغلی بال جو کبھی ایک دبیز گچھے کی صورت ہوتے تھے اب نصف سے زیادہ گر چکے تھے، نرم بھورے پستانوں کا رنگ اڑ چکا تھا۔
’ایسے نہیں چلے گا۔ میں تمہاری ماں کو فون کرتا ہوں۔‘
’نہیں رکو ، میں خود کرتی ہوں،‘ میری بیوی فوراً چلائی۔ لفظ اس کے منہ سے یوں برآمد ہو رہے تھے جیسے وہ اپنی زبان چبا رہی ہو۔
’ہسپتال جاؤ، سمجھ گئی؟ کسی ماہرِ امراضِ جلد سے ملو۔ نہیں بلکہ جنرل ہسپتال جاؤ۔ ‘ وہ گنگ کھڑی سر ہلا رہی تھی۔ ’تم جانتی ہو کہ میرے پاس تمہارے ساتھ جانے کے لیے وقت نہیں۔ تم خود اپنے جسم کو جانتی ہو، اپنا خیال تو انسان کو خود رکھنا ہوتا ہے نا؟‘ اس نے ایک بار پھر سر ہلایا۔ ’میر ی بات سنو۔ اپنی ماں کو فوراً فون کرو۔‘ میری بیوی وہاں کھڑی ، بس ہونٹ بھینچے سر ہلا رہی تھی۔ کیا یوں سر ہلانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ میری بات سن رہی ہے؟ گمان یہی تھا کہ میرے الفاظ ایک کان سے داخل اور دوسرے سے خارج ہو رہے تھے، میں فرش پر گھٹیا بسکٹوں کے چُورے کی طرح گرتے ہوئے ان کے مسلے جانے کی آواز سن سکتا تھا۔
۶
لفٹ کے دروازے کھڑاک سے کھل گئے۔ اپنا بے ڈھب سوٹ کیس اٹھائے اندھیری راہداری میں چلتے ہوئے میں آخر کار دروازے تک پہنچا اور گھنٹی بجائی۔کوئی جواب نہیں آیاْ۔
میں نے اپنا کان دروازے کے برفیلے فولاد سے لگاتے ہوئے کچھ سننے کی کوشش کی۔ پھر دوبارہ گھنٹی بجائی، دو ، تین ، چار بار کہ آیا وہ کام کر بھی رہی تھی۔ گھنٹی ٹھیک تھی، فلیٹ کے اندر اس کے بجنے کی آواز سنی جا سکتی تھی، گو دروازہ بند ہونے کی وجہ سے آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوتی تھی۔ سوٹ کیس دروازے کے ساتھ لگا کر میں اپنی گھڑی دیکھنے لگا۔ شام کے آٹھ بج رہے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میری بیوی کی نیند گہری تھی ، لیکن یہ تو کچھ زیادہ ہی تھا۔
بہت تھکا ہوا تھا۔ کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ کاش چابی آرام سے مل جائے اور زیادہ تلاش کرنے کی پریشانی میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔
شاید میری بیوی نے اپنی ماں کو فون کر دیا ہو اور میرے کہنے کے مطابق ہسپتال چلی گئی ہو یا پھر میری غیر موجودگی میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں کچھ دن گاؤں میں ٹھہرنے۔ لیکن نہیں۔۔۔جونہی میں دروازے سے اندر داخل ہوا تو وہی جانے پہچانے سلیپر، ورزشی اور دوسرے زیبائشی جوتوں کا ڈھیر میرے سامنے تھا۔
میں نے غیر شعوری طور پر فلیٹ کی عمومی سردی اپنے اندر اتارتے ہوئے جوتے اتار کر سلیپر پہن لیے۔ ابھی چند ہی قدم بڑھا تھا کہ ایک شدید بدبو کا احساس ہوا۔ فریج کھولا تو اندر حلوہ کدو اور کھیرے کا گلا سڑا پکوان ایک بدبودار مادے میں تبدیل ہوا پڑا تھا۔
سلگتی برقی دیگچی میں کوئی آدھا پیالہ چاول بچے ہوں گے جنہیں واضح طور پر اتنی دیر ہو چکی تھی کہ وہ سوکھ کر اندرونی حصے میں چپک چکے تھے۔ڈھکن اٹھاتے ہی کئی دن کے باسی چاولوں کی بو گرم بھاپ کے ساتھ میرے نتھنوں سے ٹکرائی۔ آب گیر میں گندے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا، واشنگ مشین کے اوپر موجود پلاسٹک کی ٹوکری سے گلی سڑی نمی کی بدبو اٹھ رہی تھی جہاں سرمئی صابن والے پانی میں گندے کپڑے موجود تھے۔
میری بیوی نہ تو بیڈروم میں تھی ، نہ ہی غسل خانے یا اس فالتو کمرے میں جسے ہم مختلف کاموں کےلیے استعمال کرتے تھے۔بیٹھک میں صبح کا اخبار اسی طرح پھیلا تھا جیسا میں پچھلے ہفتے چھوڑ گیا تھا، آدھ لیٹر دودھ کے ڈبوں کا ایک کنستر، جمے ہوئے دودھ کے قطروں والا ایک شیشے کا کپ، میری بیوی کی ایک الٹی سفید جراب اور ایک سرخ چرمی پرس اِدھر اُدھر بکھرے پڑے تھے۔
باہر شاہراہ پر تیزی رفتاری سے سفر کرتی کاروں کے انجنوں کا شور فلیٹ میں موجود خالی پن کے ٹھوس حجم کو کسی تیز دھار آلے سے کاٹ رہا تھا۔
چونکہ تھکن سے چور او ربھوکا تھا، تمام برتن ہی آب گیر میں موجود تھے اور میرے لیے ایک بھی صاف چمچ نہیں تھا کہ کچھ چاول ہی نکال لیتا، مجھے شدید اکیلے پن کا احساس ہوا۔ شاید تنہائی اس لیے محسوس کر رہا تھا کہ اتنے طویل سفر کے بعد ایک خالی گھر میں آن پہنچا تھا، وہ تمام چھوٹے موٹے قصے سنانا چاہتا تھا جو طویل ہوائی پروازوں پر پیش آتے ہیں، ان تمام مناظر کے بارے میں گپ شپ لگانا چاہتا تھا جو کسی اجنبی ملک کی ریل گاڑیوں کی کھڑکیوں سے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی تو ہوتا جو یہ پوچھتا کہ ‘کیا تم تھکے ہوئے ہو؟‘ اور میں اُس مردم بیزار سوفسطائی کے سامنے یہ جواب دے کر اپنی برداشت کے جوہر دکھا سکتا کہ ’میں ٹھیک ہوں‘۔ یہ سب کچھ سوچ کر مجھے غصہ آ گیا۔ اس احساس کی وجہ سے کہ میرے بدن کی بے وقعتی مجھے کائنات میں ضم ہونے سے روک رہی تھی، اس سردی کی وجہ سے جو اچانک میرے ڈھیلے ڈھالے لباس میں سرایت کر رہی تھی اور اس خیال کی وجہ سے کہ میں نے ساری زندگی خود کو کامیابی سے بہلانے میں گزار دی، مجھے غصہ آ گیا۔ بالکل تنہا ، کسی چاہنے والے کے بغیر میری ہستی شاید پہلے ہی فراموش کی جا چکی تھی۔
عین اسی لمحے ایک مدھم سی آواز سنائی دی۔
میں آواز کی جانب مڑا۔ یہ یقیناً میری بیوی ہی کی آواز تھی۔ بالکونی سے ایک بہت ہلکی اور ناقابلِ فہم سرگوشی کی سی آواز آ رہی تھی۔
تنہائی کا وہ شدید احساس اچانک اطمینان میں بدل گیا۔ جونہی میں اپنے پیر تھپ تھپ زمین پر مارتا بالکونی میں پہنچا مجھے اپنی زبان کے سرے پر جھلاہٹ کی ایک لہر سی محسوس ہوئی ۔ ’اگر تم اس وقت سے یہیں موجود تھیں تو مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟‘ میں نے برآمدے کا دروازہ زور سے کھولتے ہوئے کہا۔ ’ یہ گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس گند میں تم زندہ سلامت ہی کس طرح ہو؟‘
اپنی بیوی کے برہنہ وجود پر نظر پڑتے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا!
وہ بالکونی کی کھڑکی کے ساتھ چلتی سلاخوں کی جانب منہ کیے جھکی ہوئی تھی، دونوں بازو ہوا میں یوں بلند تھے جیسے خوشی سے لہرا رہی ہو۔ تما م بدن گہرا سبز تھا۔ سیاہ ہوتا چہرہ اب کسی سدابہار پتے کی طرح چمک رہا تھا۔ سوکھے ہوئے مولی کے پتوں جیسے بال اب جنگلی جڑی بوٹیوں کے تنوں کی طرح منور تھے۔
سبز چہرے میں دو چمکدار آنکھیں ذرا زرد محسوس ہوتی تھیں۔ پیچھے ہٹا تو وہ میری جانب اس طرح مڑی جیسے کھڑا ہونا چاہتی ہو۔ لیکن اس کی بجائے اس کی ٹانگوں میں اوپر نیچے بس ایک ارتعاش سا پیدا ہوا۔ وہ کھڑے ہونے یا چلنے کے قابل نہ لگتی تھی۔
اس کی لچکدار کمر تھرتھرا رہی تھی۔ گہرے نیلے ہونٹوں کی درمیان ایک لاغر سی سوکھی ہوئی زبان کسی آبی پودے کی طرح لہرا رہی تھی۔ دانتوں کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔
ان زرد، شکن دار ہونٹوں کے بیچ سے ایک ہلکی سی آہ نکلی جو کراہنے کی آواز سے ذرا سی ہی زیادہ تھی ۔
’۔۔۔پااااانی۔‘
میں بیسن کی طرف بھاگا اور فوراً پورا نلکا کھول دیا،پلاسٹک کا پیالہ لبالب بھر گیا۔ بالکونی کی طرف اس طرح واپس بھاگا کہ تیز رفتار قدموں کے ساتھ پانی چھلک چھلک کر بیٹھک کے فرش پر گر رہا تھا۔ جونہی میں نے اپنی بیوی کی چھاتی پر چھڑکاؤ کیا تو کسی بہت بڑے پودے کے پتے کی طرح اس کا پورا جسم کپکپاتے ہوئے زندہ ہو نے لگا۔ واپس گیا اور دوبارہ برتن بھر کر اس کے سر پر انڈیل دیا۔ بال یوں اچھل کر کھڑے ہونے لگے جیسے کسی نادیدہ بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ میں اپنے بپتسمہ کے زیرِ اثر اس کے چمکدار کھلتے ہوئے بدن کو تکتا رہا۔ سر چکرا رہا تھا۔
آج سے پہلے میری بیوی کبھی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔
۷
ماں۔
میں اب مزید خط لکھنے کے قابل نہیں رہی۔ نہ ہی تمہارا چھوڑا ہوا وہ سویٹر پہننے کے قابل ہوں۔ وہ نارنجی اونی سویٹر جو تم پچھلی سردیوں میں غلطی سے یہاں بھول گئی تھی۔
اُس کے کاروباری دورے پر نکلنے سے اگلے روز میں نے وہ پہنا تھا۔ تم جانتی ہی ہو کہ مجھے کتنی سردی لگتی ہے۔
وہ دُھلا ہوا نہیں تھا اس لیے اس میں ان دُھلے برتنوں کی بُو اور تمہارے جسم کی مہک رچی بسی تھی۔ کوئی اور دن ہوتا تو شاید میں اسے دھو لیتی لیکن اس دن بہت سردی تھی اور میں اسی مہک میں سانس لینا چاہتی تھی، لہٰذا اسے پہنے پہنے ہی سو گئی۔ اگلی صبح ابھی کُہر کی جکڑ قائم تھی اور شاید یہ میری پیاس اور سردی کا احساس تھا کہ بیڈروم کی کھڑکی سے سورج کی روشنی اندر آتے ہی میرے منہ سے ایک دبی دبی چیخ نکل گئی: ’ماں‘۔اس گرم روشنی میں خود کو چھپا لینے کی تمنا تھی کہ میں بالکونی میں نکل گئی اور تمام کپڑے اتار دئیے۔ میری برہنہ جلد میں پیوست ہوتی سورج کی کرنیں تمہاری مہک سے کتنی ملتی جلتی تھیں! وہیں جھکے ہوئے میں ماں ماں پکارتی رہی۔ کوئی بھی اور لفظ نہیں۔
نہ جانے کتنا سمے گزر گیا۔ دن، ہفتے، مہینے؟ یہ دیکھتے ہوئے کہ ہوا اب کچھ خاص گرم محسوس نہیں ہوتی مجھے بس حدت میں تھوڑا سا چڑھاؤ اور پھر ایک اطمینان بخش اتار ہی یاد ہے۔
اب کسی بھی لمحے چونگ نینگ ندی کے اس پار موجود فلیٹوں کی کھڑکیاں نارنجی روشنیوں سے جگمگائیں گی۔
کیا وہاں رہنے والے لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ کاریں جو اپنی روشنیاں بہاتی شاہراہ پر تیزرفتاری سے دوڑتی چلی جا رہی ہیں؟ میں اب کیسی لگتی ہوں؟
*
اس نے بہت مہربانی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے ایک بڑے سے گملے میں لگا دیا۔ ساری اتوار وہ بالکونی کے کنارے پر بیٹھا سبز سُنڈیاں پکڑتا رہتا ہے۔
وہ جو ہمیشہ تھکا تھکا رہتا تھا اب ہر صبح پچھواڑے والی پہاڑی چڑھ کر معدنی پانی کی ایک بالٹی لاتا ہے تاکہ میری ٹانگوں کو پانی دے سکے (اسے یاد ہے کہ مجھے نلکے کا پانی پسند نہیں)۔ کچھ دیر پہلے اس نے میرا گملا خالی کیا اور اس میں موجود پرانی مٹی کو کھاد اور مٹی کے تازہ گندھے ہوئے آمیزے سے بدل دیا۔ جب پچھلی رات کی بارش شہری ہوا کی ریت کو چاٹ جاتی ہے تو وہ کھڑکیاں دروازے چوپٹ کھول دیتا ہے تاکہ نتھری ہوئی ہوا اندر آ سکے۔
*
ماں یہ سب کچھ بہت عجیب ہے۔ دیکھے، سُنے،سونگھے اور چکھے بغیر بھی سب کچھ بہت تروتازہ، پہلے سے زیادہ زندہ محسوس ہوتا ہے۔ میں تارکول پر گھسٹنے والے کار کے ٹائر کی کھردری رگڑ محسوس کرتی ہوں ، وہ داخلی دوازہ کھول کر میری طرف بڑھتا ہےتو اس کے قدموں کی چاپ میں موجود ہلکا سا ارتعاش ، زرخیز خوابوں کو نمی بخشتی بارش سے بھری ہوا، صبح صادق کی سرمئی نیم روشن منور فضا۔
نزدیک ہوں یا دور ، میں کلیوں کا پھوٹنا اور پتیوں کا کھلنا محسوس کر سکتی ہوں، زرگونوں سے لارووں کا نکلنا، کتوں اور بلیوں کا بچے پیدا کرنا، ساتھ والی عمارت کے بوڑھے آدمی کی نبض کا اتار چڑھاؤ، اوپر رسوئی میں ابلتا ہوا سلاد، نچلے فلیٹ میں گرامو فون کے پیچھے پڑے گلدان میں باہر سے توڑے گئے گل داؤودی کا گلدستہ۔ رات ہو یا دن، ستارے ایک ٹھہری ہوئی قوس معلوم ہوتے ہیں۔ سورج جب بھی طلوع ہوتا ہے تو شاہراہ کےکنارے پر لگے انجیرِ توت اپنے خمیدہ جسم مشرق کی سمت جھکا لیتے ہیں۔ میرا اپنا بدن بھی بالکل یہی کرتا ہے۔
کیا تم سمجھ سکتی ہو؟ میں جانتی ہوں کہ بہت جلد یہ یادوں کا سلسلہ بھی معدوم ہو جائے گا، لیکن میں ٹھیک ہوں۔ میں بہت عرصے سے یہی خواب دیکھ رہی تھی، صرف اور صرف ہوا، سورج کی روشنی اور پانی پر زندہ رہنے کا خواب۔
*
یاد ہے جب میں بچی تھی: دوڑتی ہوئی رسوئی میں آتی اور اپنا سر تمہارے دامن میں رکھ دیتی ، وہ لذیذ مہک، تلوں کے تیل، تلے ہوئے بیجوں کی وہ اشتہا انگیز خوشبو۔ تمہیں یاد ہو گا کہ میں ہمیشہ مٹی میں ہی کھیلتی رہتی تھی۔ گیلی مٹی سے لتھڑے میرے ہاتھ تمہارے دامن کو آلودہ کر دیتے تھے۔
میری عمر اس وقت کیا ہو گی؟ بہار کا وہ دن جب ہلکی پھوار کے باعث دھند سی چھائی تھی، ابا نے مجھے اٹھا کر ٹریکٹر پر بٹھایا تھا اور ہم سب ساحل کی سیر کو چلے گئے تھے۔ بارش میں سب بڑوں کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کی آواز، بچوں کی پیشانیوں پر چپکے ہوئے گیلے بال، یہاں وہاں اچھلتے کودتے ہنستے کھیلتے چہرے، سب دھندلا رہا ہے۔
سمندر کے کنارے وہ غریب سا گاؤں تمہاری کُل کائنات تھا۔ تم وہیں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی۔ وہیں بچے جنے، کام کیا اور بوڑھی ہو گئی۔
ایک دن وہیں ہمارے آبائی قبرستان میں ابا کے پہلو میں پہنچ جاؤ گی۔
تمہارے جیسے انجام کا ڈر تھا ماں جس نے مجھے گھر سے اتنا دور ہونے پر مجبور کیا۔ سترہ سال کی عمر میں گھر کو خیرباد کہتے ہوئے، بوسان، دائیگو، گینگ نیونگ کے وہ تمام شہری اضلاع جہاں میں بے مقصد ایک ماہ سے بھی زیادہ گھومتی پھرتی رہی میری یاداشت کا حصہ ہیں۔ ایک جاپانی ریستوران میں اپنی عمر کے بارے میں جھوٹ بولنا، تن تنہا اپنا بوجھ اٹھانا، شام کو جنینی حالت میں مڑ تڑ کر اس چھوٹے سے کتب خانے میں پڑے رہنا۔۔۔مجھے وہ جگہ بہت پسند تھی۔ شہری علاقوں کی وہ چکا چوند کر دینے والی روشنیاں، وہاں کے باسیوں کی وہ دمکتی اٹھان۔
یاد نہیں کب مجھے ادراک ہوا کہ میرا انجام انہی اجنبی گلیوں میں آوارہ گردی کرتے ضعیف و لاچار ہوجانا ہے۔ گھر میں بھی ناخوش تھی اور گھر سے دور بھی اتنی ہی ناخوش، تو پھر تم ہی کہو میں کہاں جاتی؟
میں کبھی خوش نہیں ہو سکی۔ کیا میرے عقب میں ازل سے کوئی زخمی روح موجود ہے، میرا گلا دباتی، میرے جسم کو جکڑتی کوئی بدروح؟ میں نے ہمیشہ بھاگ جانا چاہا ، ایک شدید بنیادی سی جبلت، ایک کرب جو رونے پر مجبور کرے، ایک چٹکی جو چیخ کو دعوت دے۔ کوئی بھی مجھے بس کے پچھلے حصے میں گھٹنے اوپر کیے دیکھے تو یہی محسوس ہو کہ یہ لڑکی مکھی تک نہیں مار سکتی، لیکن یہ تمام وقت میں اپنے اندر ایک زوردار مکے سے کھڑکی کو چٹخ دینے کی شدید خواہش سے برسرِ پیکار رہی۔ اپنی ہتھیلی سے بہتے خون کو دیکھنے کی حرص، میں اسے اس طرح چاٹ لیتی جیسے کوئی بلی دودھ چٹ کر جاتی ہے۔ میں کس چیز سے بچ کر بھاگنا چاہتی تھی؟ میرے اندر کرب کی وہ کون سی آگ تھی جو مجھے دنیا کے دوسرے کنارے جانے پر اکساتی تھی؟ پھر وہ کیا تھا جو مجھے روکے ہوئے تھا، وہ دبدھا جو مجھے معذور کیے دے رہی تھی؟ اس جست کو ناممکن بنانے والی یہ کیسی بیڑیاں تھیں جو گردشِ خون کو روک رہی تھیں؟
*
اسٹیتھو اسکوپ پر اپنی انگلی سے بار بار ضرب لگاتا عمر رسیدہ ڈاکٹر بڑبڑا رہا تھا کہ میرے سینے میں کسی قبر کی سی خاموشی تھی۔ بس دور ہوا کے جھکڑوں جیسی کچھ آوازیں تھیں۔ اس نے اسٹیتھو اسکوپ واپس میز پر رکھ دیا اور الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین کی طرف مڑ گیا۔ میں ساکت لیٹی رہی جب ا س نے ایک لیس دار مادہ میرے پیٹ پر لگایا اور پھر بڑے طریقے سے ایک پتلی سی چھڑی جیسا آلہ سینے کے مرکز سے پیٹ کے نچلے حصے تک پھیرا۔ اس آلے کے ذریعے میرے جسم کی سیاہ و سفیداندرونی تصویر ایک اسکرین پر منتقل ہو رہی تھی۔
’سب نارمل ہے،‘ وہ اپنی زبان چٹخاتے ہوئے بڑبڑایا۔ ’اب ہم تمہاری آنتوں کا معائنہ کر رہے ہیں۔۔۔یہاں بھی سب ٹھیک ہے۔ ‘
ہر چیز ’نارمل‘ قرار دے دی گئی۔
’معدہ، جگر، بچہ دانی، گردے، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ ‘
اسے کیوں نظر نہیں آتا تھا کہ یہ تمام اعضا آہستہ آہستہ سوکھ رہے تھے، غائب ہونے والے تھے؟ میں نے کچھ کاغذی رومالوں کی مدد سے خود کو صاف کیا اور اٹھنے ہی والی تھی جب اس نے میں مجھے دوبارہ لیٹ جانے کو کہا۔ پیٹ کو مختلف جگہوں سے دبایا، ایسا کچھ خاص درد تو نہیں تھا۔ اس کے عینک والے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے میں نے اس کے بے توجہی سے کیے گئے سوال ’ درد محسوس ہورہا ہے؟‘ کے جواب میں نفی میں سر ہلا دیا۔
’یہاں ٹھیک ہے؟‘
’یہاں درد نہیں ہوتا؟‘
’درد نہیں ہے۔‘
ایک انجکشن لگایا گیا اور گھر واپسی کے دوران میں نے قے کر دی۔
زیرِ زمین ریلوے اسٹیشن کی ٹائلوں والی دیوار کے ساتھ کمر لگائے بیٹھی رہی۔ گنتی گن رہی تھی کہ درد کب دور ہوتا ہے۔ظاہر ہے ڈاکٹر نے یہی تجویز کیا تھا کہ میں پرسکون رہنے کی کوشش کروں، اطمینان بخش خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ دوں۔ اس کا کہنا تھا کہ ساری بات تو دماغ کی ہے، لہجہ اُس وقت کسی بدھ بھکشو جیسا تھا۔ پرسکون خیالات، اطمینان بخش خیالات، ایک ، دو ، تین ، چار، بے حد سکون، قے نہ کرنے کی کوشش میں گنتی گننا۔۔۔درد سے میرے آنسو نکل آئے، معدے میں موجود تیزاب کو حلق سے باہر انڈیلنے کی کوشش میں جسم بل کھا رہا تھا ، دوبارہ، ایک بار پھر، یہاں تک کہ کچھ بھی نہ بچا اور میں زمین پر گر پڑی۔ انتظار کرتی رہی کہ ہلتی ہوئی زمین رک جائے، خدا کی پھٹکار، اب رک بھی جاؤ۔
یہ کتنی پرانی بات ہے؟
*
ماں میں یہی خواب بار بار دیکھتی ہوں۔ کسی سفیدے کی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہوں۔ بالکونی کی چھت کو چیرتے ہوئے، بالائی منزل کی چھت سے بھی اوپر، اس سے اگلی منزل سے بھی اوپر، پندرہویں منزل، سولہویں منزل، سہارا دینے والے کنکریٹ اور فولادی سلاخوں کو کاٹتے ہوئے ، یہاں تک کہ میں سب سے بالائی منزل کو توڑتی ہوئی فضا میں نکل گئی ہوں۔ میری بالاترین اونچائیوں سے سفید لارووں جیسی کلیاں پھوٹ رہی ہیں۔ سانس کی نالی صاف شفاف پانی چوستی ہے، اتنا تناؤ جیسے پھٹنے کے قریب ہو، سینہ آسمان کی جانب اچھلتا ہےاور میں شاخوں کی طرح پھوٹتے ہر عضو کو پھیلانے کے لیے پوری قوت خرچ کر رہی ہوں۔ اس طرح اس فلیٹ سے فرار ممکن ہوا ہے۔ ہر رات، ہر رات یہی خواب ماں!
*
دن سرد تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج بھی اس دنیا میں بہت سے پتے زمین پر گرے ہوں گے، کئی سانپوں نے کینچلیاں بدلی ہوں گی، کئی کیڑے مکوڑے اپنی ننھی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں گے، کئی مینڈکوں نے وقت سے ذرا پہلے ہی سرما خوابی کا آغاز کر دیا ہو گا۔
میں تمہارے سویٹر کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ تمہاری مہک اب دھندلا رہی ہے۔ میں اسے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے یہ اوڑھا دے لیکن میری آواز اب ضائع ہو چکی ہے۔ کیا کر سکتی ہوں؟ وہ مجھے یوں گھلتے دیکھ کر روتا ہے، غصے بھی ہوتا ہے۔ تم جانتی ہی ہو، میں ہی اس کا کُل کنبہ تھی۔ میں اپنے اوپر بہائے جانے والے معدنی پانی میں اس کے گرم آنسو دریافت کر سکتی ہوں۔ ہوا کے خلیوں کی بے ترتیبی سے احساس ہوتا ہے کہ اس کی بند مٹھی خلا میں کسی نادیدہ ہدف سے جا ٹکرائی ہے۔
*
مجھے ڈر لگتا ہے، ماں۔ میرے اعضا نے گرنا ہی ہے۔ یہ گملا کسی شکنجے کی طرح ہے، دیواریں بہت سخت ہیں۔ میری جڑوں کی سروں پر درد ہوتا ہے۔ ماں میں سردیاں آنے سے پہلے ہی مر جاؤں گی۔
اور شاید ہی پھر کبھی دوبارہ اس دنیا میں کِھل سکوں۔
۸
اس رات جب میں اپنے کاروباری دورے سے لوٹا تو تین پیالے انڈیلنے کے بعد میری بیوی نے ایک زرد تیزابی قے کی۔ میں نے اس کے ہونٹوں کو کھلتے اور پھر تیزی سے واپس بھنچتے دیکھا، میری آنکھوں کے بالکل سامنے، گوشت پر گوشت چڑھ گیا۔ میری کانپتی انگلیاں ان زرد پتیوں جیسے ہونٹوں کو ٹٹول رہی تھیں کہ میں نے بالآخر ایک کمزور سی آواز سنی، اتنی مدھم کہ الفاظ ماورائے سماعت تھے۔ یہ آخری موقع تھا کہ میں نے اپنی بیوی کی آواز سنی۔ اس کے بعد کبھی ہلکی سی آہ تک سنائی نہ دی۔
پھر اس کی رانوں کے اندرونی حصے سے جڑوں کا ایک سفید دبیز فوارہ سا پھوٹ پڑا۔ سینے سے گہرے سرخ پھول کِھل گئے۔ پستانوں سے جڑواں زرِ ریشہ اگ آئے جو جڑوں سے زرد و دبیز اور سِروں سے سفید تھے۔جن دنوں اس کے اٹھے ہوئے بازو ؤںمیں ذرا سا دباؤ ڈالنے کی سکت باقی تھی ، وہ انہیں میری گردن میں حمائل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی اب تک نیم منور آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میں کمیلیا کی پتیوں والے بغل گیر ہاتھوں کی جانب جھک گیا۔ ’تم کیسی ہو؟‘ میں نے پوچھا۔ پکے ہوئے انگوروں جیسی آنکھوں کی چمکدار سطح ذرا جھلملائی، مسکراہٹ کی شبیہہ۔
خزاں کو کچھ وقت گزرا تو میں نے اپنی بیوی کے جسم میں بتدریج ایک واضح نارنجی روشنی طاری ہوتے دیکھی۔ کھڑی کھولتا تو اس کے کھلے ہوئے بازو ہوا کے بہاؤ کے ساتھ لہراتے۔
خزاں کا آخر تھا جب اس کے پتے دو دو تین تین کی جوڑیوں میں گرنے لگے۔ اس کا بدن نارنجی سے چمکیلا بھورا ہو گیا۔
مجھے یاد آیا جب میں نے آخری بار اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ۔
جسمانی رطوبتوں کی تلخ ناگوار تیزی کی بجائے اس کے جسم کے زیریں حصے سے ایک ہلکی سی خوشگوار مہک اٹھ رہی تھی۔ اس وقت میں نے یہی سوچا تھا کہ شاید اس نے صابن تبدیل کیا ہے یا شاید کچھ فارغ وقت مل گیا ہو گا اور اس نے نیچے کچھ عطر کے قطرے وغیرہ ٹپکائے ہیں۔ یہ سب کتنی پرانی بات ہے؟
اب میری بیوی کی وضع قطع میں شاید ہی دوپایوں والی کوئی بات رہی ہے جو وہ کبھی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیا ں جو چمکدار گول انگوروں میں تبدیل ہو چکی تھیں ، اب بتدریج بھورے تنوں میں دفن ہو رہی ہیں ۔ وہ اب دیکھ نہیں سکتی۔ نہ ہی اپنے تنوں کے سرے ہلا سکتی ہے۔ لیکن بالکونی میں جاتے ہوئے مجھے ایک دھندلا سا احساس ہوتا ہے جو ماورائے نطق ہے، جیسے اس کے بدن سے ایک نازک سی برقی رو نکل کر میرے جسم میں سرایت کر رہی ہو۔ جب وہ تمام پتے گر گئے جو کبھی اس کے دست و گیسو تھے ، وہ درز کھل گئی جہاں کبھی اس کے ہونٹ آپس میں ملتے تھے اور مٹھی بھر پھل برآمد ہوئے تو وہ احساس کسی نازک سے دھاگے کے ٹوٹنے کی طرح ختم ہو گیا۔
ننھے پھل اناروں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر بصورتِ ہجوم باہر آ گئے۔ انہیں ہاتھوں میں اکٹھا کیے میں بالکونی اور بیٹھک کی دہلیز پر بیٹھ گیا۔ یہ پھل جنہیں میں پہلی بار دیکھ رہا تھا زرد ی مائل سبز تھے۔سورج مکھی کے بیجوں کی طرح سخت جنہیں بھنے ہوئے مکئی کے دانوں کے ساتھ شراب نوشی کا لطف دوبالا کرنے کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔
میں نے ایک اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ ملائم بیرونی چھلکا تو بالکل بے ذائقہ اور کسی قسم کی خوشبو کے بغیر تھا۔ میں نے اسے چبا ڈالا۔ روئے زمین پر میری واحد محبوبہ کا پھل ۔ اولین احساس تیزابی بلکہ تقریباً ترش تھا، زبان کی جڑ سے چپک کر رہ جانے والے عرق میں ایک کرواہٹ کا سا بچ رہنےوالا ذائقہ تھا۔
اگلے دن میں ایک درجن گول گملے خرید لایا اور انہیں زرخیز مٹی سے بھر کر ان پھلوں کو بو دیا۔ گملوں کو ایک قطار میں اپنی مرجھائی ہوئی بیوی کے ساتھ رکھا اور کھڑکی کھول دی۔ آہنی جنگلے پر جھک کر کھڑا ہوا، ایک سگریٹ سلگایا اور تازہ گھاس کی خوشبو کا مزہ لینے لگا جو اچانک میری بیوی کے زیریں حصوں سے اگ آئی تھی۔ آخرِ خزاں کی سرد ہوا سگریٹ کے دھویں کو لہرا رہی تھی، میرے لمبے بال بکھر رہے تھے۔
بہار کی آمد پر کیا میری بیوی دوبارہ کِھل اٹھے گی؟ کیا اس کے پھول سرخ ہوں گے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، کون جانے کیا ہوتا ہے۔
***
پسِ تحریر: جنوبی کوریا کی خاتون ناول نگار ہان کینگ کی ۱۹۹۷ ءکی اس کہانی کو کئی جہتوں سے ان کے ۲۰۰۷ء کے مشہور ناول The Vegetarian کا نقیب کہا جا سکتا ہے۔ دونوں کہانیوں میں ایک شادی شدہ جوڑا اپنی بالکل سپاٹ زندگیوں میں اس وقت ایک ہلچل محسوس کرتا ہے جب عورت ایک عجیب و غریب جسمانی و نفسیاتی قلبِ ماہیت سے گزرتی ہے۔ لیکن جہاں ناول واضح طور پر کسی بھی مافوق الفطرت منظر کشی سے کنارہ کرتا ہے اور ناول کے مرکزی کردار کے درخت میں تبدیل ہونے کی خواہش کو اس کے اردگرد موجود تمام افراد پاگل پن کے طور پر دیکھتے ہیں، اس افسانے کی بے نام ہیروئین درحقیقت واقعی ایک پودے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہان کینگ کی اس کہانی اور اس سے جنم لیتے ناول کی کئی تعبیرات پیش کی گئی ہیں اور اسے جنوبی کوریائی سماج پر ایک تنقید کی بھی کہا گیا ہے۔ لیکن کایا کلپ کی یہ جہت اپنی تمثیلی جہت میں کوریائی سماج کی نسبت روایتِ کافکا سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ کوریائی ادب پر یونانی دیومالا کے بھی کوئی خاص اثرات نہیں۔ لہٰذا کوریائی نقادوں کے نزدیک ہان کینگ نے ادب میں ایک ایسی نئی روایت کو متعارف کروایا ہے جو مشرقی ایشیا کے ادب میں جدید سرمایہ دارانہ صنعتی دور سے جنم لیتے ایک ماحولیاتی ابہام کو اپنا موضوع بناتی ہے ۔ یہ ابہام آمیز طلسماتی نثر بلاشبہ کسی بھی مترجم کے لیے ایک دلچسپ چیلنج سے کم نہیں۔