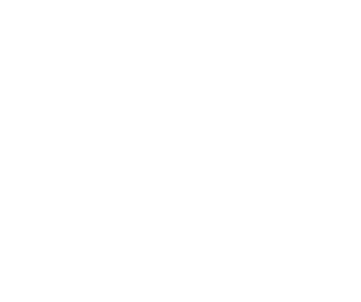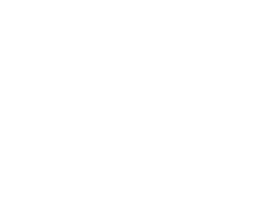یونیورسٹی پر سامراجی غلبہ۔ تحریر: حارث ظہور گوندل (ترتیب: ذوالقرنین سرور)
حارث بیان کرتے ہیں کہ کیسے یونیورسٹیوں کے تمام شعبہ جات وقت کی قید میں جکڑے ہوئے ہیں اور دلائل کے ساتھ یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ طالب علموں کو علم کی حقیقی روشنی سے فائدہ ملنے کے بجائے نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن مسلسل کوشش ان قید کی زنجیروں کو ضرور توڑ دے گی۔ (کتاب گھر، جس کا اس مضمون میں تذکرہ کیا گیا ہے، کو جاننے کے لیے دیکھیے: دی کورسپونڈنٹ، سما، نیو اور ڈان)
نگوگی واتھیا نگو کہتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کے ادبی شعبہ جات کافی عرصے سے ’وقت‘ کی قید میں ہیں اور آج تک ان میں ’نو آبادیاتی اثر‘ واضح طور پر عیاں ہے۔ میرے تجربے کے مطابق صرف ادبی شعبہ جات ہی نہیں، بلکہ باقی تمام شعبہ جات بھی نو آبادیاتی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ چاہے آپ تاریخ پڑھ لیں، چاہے سیاسیات، یا کوئی اور مضمون، آپ کو گلوبل ساؤتھ یا ”تیسری دنیا“ کے ادیب اور مفکر بہت کم ہی پڑھنے کو ملیں گے۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو کر ہمارے اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس پیدا ہو چکا ہوتا ہے کہ شاید تعلیم اور تہذیب کا حقیقی دارالخلافہ تو یورپ ہی ہے۔ اُسی خطے میں ادیب، مفکر، دانشور اور سائنسدان پیدا ہوئے اور یہاں کے لوگ تو بس کند ذہن اور کاہل ہی ہیں جنہیں ایسی تعلیم میسر کروا کر ایک ”پڑھا لکھا“ اور سوچنے والا انسان بنایا جا سکتا ہے۔ ہم رسمی طور پر آزاد تو ہو گئے مگر ہمارے ذہنوں پر نو آبادیاتی غلبہ آج بھی قائم ہے کیونکہ ہم وہ ہی پڑھ لکھ رہے ہیں جو برطانوی و یورپی سامراج کی دین ہے۔ نہ ہی ہم نے اپنے ریاستی نظام کی تشکیل نو کا کوئی تصور کیا اور نہ ہی تعلیمی نظام کے بارے میں کچھ سوچا۔ اس قسم کی تعلیم کے فوائد کا تو علم نہیں لیکن نقصانات کافی زیادہ ہیں۔ اور شاید سب سے بڑا نقصان اپنی سیاسی و تاریخی حقیقتوں سے نا آشنائی ہے۔ آج ہمیں ایسی تعلیم کی ضرورت ہے جو ہمیں اپنی تاریخ اور یہاں کے لوگوں کی سیاسی جد و جہد سے جوڑ سکے، جو ہمیں تیسری دُنیا کی سانجھ کا درس دے۔ اور یہ کام یونیورسٹی میں حاصل کردہ تعلیم سے تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ آج کی نیولبرل یونیورسٹی محض پیسے کمانے کے چکروں میں ہے۔ جیسا کہ فریڈ موشن اور سٹیفانو ہار اپنی کتاب ”انڈر کا منر“ میں لکھتے ہیں: ”آج یونیورسٹی سے واحد ممکنہ رشتہ مجرم کا ہے“۔ خیر، میں اپنی بات کچھ مثالیں دے کر واضح کرنا چاہوں گا۔
سال ۲۰۱۶ء کی بات ہے، حالانکہ میں ادب کا طالب علم تھا، لیکن یونیورسٹی کے لبرل آرٹس تعلیمی نظام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے تاریخ کے کچھ کورس پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ پہلی جنگ عظیم سے لے کر سرد جنگ کے اختتام تک بین الاقوامی تعلقات پر پڑھائے جانے والے کورس میں ہمیں ہنری کسنجر کا ایک خط پڑھایا گیا جو اس نے چائنہ کا دورہ کرنے کے بعد صدر رچرڈ نکسن کو لکھا تھا۔ اور ہمیں بتایا گیا کہ کیسے کسنجر نے اپنی ذہانت اور بین الاقوامی تعلقات کو سمجھنے کی ایک غیر معمولی صلاحیت استعمال کر کے نکسن کا دورہ چین ممکن بنایا۔ ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ کسنجر کتنا شاطر اور کیسا ”ڈپلو میٹک جینیسں“ تھا۔ اسی طرح برزنسکی کی تعریفوں کے پل باندھے گئے۔ ارے واہ، کسنجر تو نو بیل پیس پرائز کا بھی حامل ہے۔ پر ہمیں کمبوڈیا پر ہونے والی بمباری میں کسنجر کا کردار کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ اگر ہم کسنجر کا ایک فضول سا خط پڑھ سکتے ہیں تو کمبوڈ یا پر ہوئی بمباری پر بھی تو کسی نے کچھ لکھا ہو گا۔ ویتنام جنگ کے دوران کسی قسم کی جینیسں ڈپلومیسی استعمال کر کے لاشوں کے انبار لگائے گئے؟ اس طرح کی حقیقتوں پر پردہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اب جب میں اُس کورس کا سوچتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسنجر کا سایہ اس کمرۂ جماعت میں کہیں دندناتا پھر رہا تھا۔ ایک بھاری سایہ، ابلتی ہوئی آنکھیں لیے، ہمارے پروفیسر کے کندھوں پر ہاتھ دھرے۔ وہ ہمیں دیکھ، بلکہ گھور رہا تھا۔ کسنجر کی حقیقت جاننے کے لیے اینتھنی بورڈین کے چند جملے ہی کافی ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ آپ اگر کمبوڈیا کا ایک چکر لگا لیں تو آپ کا من کرے گا کہ آپ کسنجر کو اپنے ہاتھوں سے مکے مار مار کر اس کا منہ توڑ دیں۔ اور آپ پھر کبھی بھی اخبار میں اس قاتل حرامزادے کا کوئی انٹر ویو سکون سے نہیں پڑھ پائیں گے۔ لیکن ہمیں کمبوڈیا کے انسانوں سے کیا لگے۔ ہم کسنجر کے خط کا مزا لیں گے۔ ہمارا غرض اس کی ڈپلو میٹک صلاحتوں تک محدود ہے۔ ہم اس کی کتابیں سی۔ ایس -ایس کے سلیبس میں پڑھائیں گے۔
ادب کی بات کی جائے تو اس کی پڑھائی شمالی امریکہ اور برطانیہ کے کچھ سفید فام مردوں تک محدود کر دی گئی ہے۔ افریقہ، لاطینی امریکہ، یا تیسری دنیا کے کسی اور ملک کے ادیبوں کی پڑھائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ حالانکہ ہماری سیاسی و سماجی حقیقتیں اور تاریخی جد و جہد ان سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہے۔ برطانوی نو آبادی بربریت اور امریکی سامراج کے مظالم تیسری دنیا کے لوگوں میں سانجھ کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ اور اس سانجھ کی بھی ایک تاریخ ہے جس سے ہمیں دانستہ طور پر دور رکھا گیا ہے۔ چاہے وہ ایفرو ایشین سالیڈیرٹی کے تحت لکھا، پڑھا اور ترجمہ کیا جانے والا انقلابی ادب ہو یا پیٹریس لمومبا کے بہیمانہ قتل کے خلاف لاہور کی سڑکوں پر کیا جانے والا احتجاج ہو۔ ہماری قومی یادداشت سے ان واقعات کو تقریباً مٹا دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا ادب اور ایسی تاریخ پڑھائی جاتی ہے جس کو ہم پوری طرح محسوس ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ہماری یا ہم جیسے لوگوں کی کوئی ترجمانی نہیں۔ ترجمانی تو دور کی بات ہے، ہمیں ایسا ادب اور تاریخ پڑھائی جاتی ہے جس میں ہمارے قاتلوں کو تعظیم و تکریم دی جاتی ہے۔
جب یونیورسٹی میں ادب کے کورس پڑھے تو چارلس ڈکنز کے کام سے متعارف کروایا گیا۔ اور اس کا کام پڑھ کے اچھا بھی لگا۔ وہ برطانوی سماج میں طبقاتی تفریق سے جنم لینے والی غربت اور اس کے اثرات پر بڑے زبردست ناول لکھ رہا تھا۔ لیکن برطانیہ سے باہر رہنے والوں کے لیے شاید اُسے کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ ۱۸۶۶ء یا غالباً ۱۸۶۷ء میں، جب ”سلیوری“ جیسی لعنت کو منسوخ ہوئے تقریبا ایک سال گزر چکا تھا، تو جمیکا میں احتجاجی مظاہرہ کرنے پر برطانوی سامراج نے سینکڑوں کی تعداد میں سیاہ فام باشند وں کا قتل عام کیا۔ یہ برطانوی سامراج کی بربریت کی انتہا تھی۔ چارلس ڈکنز نے اس اقدام کی بھر پور حمایت کی اور کہا کہ ”نیٹو“ کو سبق سکھانا ضروری تھا تا کہ وہ اپنی اوقات میں رہے۔ شاید ڈکنز کے لیے ”انسان“ محض برطانیہ میں ہی رہتے تھے۔ شاید اس کے دل میں رحم صرف سفید فام لوگوں کے لیے ہی تھا۔ جو ادیب جمیکا میں قتل و غارت کی حمایت کر سکتا ہے، اس کے لیے جلیانوالہ باغ میں لاشوں کا انبار بھی کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتا ہو گا۔ وہ الگ بات ہے تب تک وہ خود ایک لاش بن چکا تھا۔
کہتے ہیں ادب بغیر کسی تفریق کے پڑھنا چاہیے۔ ادیب کے کام کو اس کی ذاتی زندگی سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔ مجھے آج تک یہ بکواس سمجھ نہیں آئی۔ ادب کو ادیب سے الگ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ آخر ادیب کا کام اس کی سوچوں کا مجموعہ ہی تو ہے۔ مجھ سے تو ایسی تفریق بالکل نہیں کی جاتی۔ میں شاید زندگی میں اب ڈکنز کا کوئی ناول سکون سے نہیں پڑھ پاؤں گا۔ اور جب یونیورسٹی میں اُسے پڑھا تھا، اگر اس وقت مجھ پر یہ حقیقت عیاں ہوتی، تو یقین مانیں میں شاید کلاس کی کھڑکی سے کود جاتا (ایسی کیفیت ویسے مجھ پر کئی دفعہ طاری ہوئی لیکن شرم اور ڈر کی وجہ سے کچھ کر نہ پایا۔) میرے لیے ڈکنز محض ایک ادیب کی حیثیت نہیں رکھتا، میرے لیے وہ سامراج اور سامراج کے کیے جانے والے مظالم کا حمایتی ہے، اور میں ایسے لوگوں کے ادب پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میرا خیال ہے اگر ہم ایسے ادیبوں کو نہ بھی پڑھائیں تو بھی کام چل سکتا ہے۔ اور اگر ڈکنز ہم پر لازم ہو چکا ہے تو ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ اس کا سامراجی بر بریت کے بارے میں کیا خیال تھا!
یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو کر ایمے سیزیر، فرانٹر فینون، والٹر راڈنی، املسر کابرال، گلوریا انزلد عا، چیری مورا گا اور بھگت سنگھ کے کام کا مطالعہ کیا تو کاگنیٹو ڈسونینس ”(cognitive dissonance)“ کا شکار ہو گیا۔ اور جہاں تک فکشن کی بات ہے، جمیکا کنکیڈ، وولے سوئنکا، ٹونی ماریسن، روبر تو بولانیو، جیمز بالڈون، شنوا اشیبی اور جے ایم کوٹزے کو پڑھا تو ادب پر ایمان پھر سے بحال ہو گیا۔ اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر ایسا ادب ہم اپنے یونیورسٹی کے طلبا کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ ہم کیوں اُن پر گلا سڑا اور بے ذائقہ ادب تھوپنے پر بضد ہیں۔ اگر میں مذکورہ بالا ادیبوں کے کام سے واقف نہ ہوتا تو آج یہ مضمون لکھنے کی بجائے میں کوئی اور کام کر رہا ہوتا اور ادب کی دنیا کو کب سے خیر آباد کہہ چکا ہوتا۔ جب ہمیں ایسے ادیب پڑھائے جائیں گے جو ہم پر ہوئے تاریخی مظالم پر دانت نکالتے ہوں تو ہم بیگانگی کے علاوہ اور محسوس بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی یونیورسٹیوں کو نوآبادیاتی اور سامراجی ادب و تاریخ سے آزاد کرنا ہوگا۔ کسنجر کوئی ڈپلومیٹک جینیس نہیں بلکہ ایک جنگی مجرم ہے۔ اور ڈکنز کے لیے انسان محض برطانیہ کے گورے ہی تھے۔ ہمیں اپنے آپ کو ان حقیقتوں سے روشناس کروانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تیسری دنیا کے لوگوں سے سانجھ برقرار رکھنے کے لیے گلوبل ساؤتھ کے ادیبوں اور مفکروں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہو سکتا تو ہمیں ”کتاب گھر“ جیسی عوامی لائبریریوں کا تصور کرنا ہوگا، جہاں ہم اپنے نوجوانوں کو انقلابی ادب سے متعارف کروا سکیں اور یونیورسٹی کی پڑھائی پر مکمل انحصار کو ختم کر سکیں۔
” کتاب گھر“ جیسی لائبریری ہر شہر کی ضرورت ہے، جہاں لوگ اکھٹے ہوں اور مل بیٹھ کر مطالعہ کر سکیں۔ جہاں پروین شاکر، سارہ شگفتہ، خالدہ حسین سے لے کر پنجابی میگزین ”پنچم“ تک کی پڑھائی ہو سکے۔ جہاں صابر علی صابر جیسے شعرا کے مشاعرے ہوں۔ جہاں جب نوجوان اکٹھے ہوں تو دندناتے ہوئے اجنبی اور بھیانک سائے ان کا تعاقب نہ کر پائیں۔ جہاں تیسری دنیا کی سانجھ کی بات ہو۔ جہاں ایک بہتر دنیا کا تصور ممکن ہو۔ جہاں علاقائی ادب کے ساتھ ساتھ گلوبل ساؤتھ کے ادبیوں کا کام بھی آسانی سے میسر ہو۔ ہمیں پڑھنے اور محسوس کرنے کے لیے یونیورسٹی کی تعلیم پر انحصار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں نئی راہوں کا تصور کرنا ہو گا۔ اپنے میگزین، پمفلٹ اور مینی فیسٹو چھاپنے ہوں گے۔ ہمیں اپنے مسائل پر خود لکھنا ہو گا، چاہے جیسا بھی لکھیں، اور ریاستی سرپرستی سے آزاد رہ کر ”کتاب گھر“ جیسی عوامی سپیس کی زیادہ سے زیادہ حمایت کرنی ہو گی۔
ایسا کرنا آسان تو نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ رجعتی طاقتوں نے ہمیشہ ایسے اقدامات کی خلاف ورزی کی ہے کیونکہ ریاست نہیں چاہتی کہ ہمارے نوجوان اپنے آپ اور اپنے لوگوں کے لیے سوچ سکیں۔ ریاست نہیں چاہتی کہ ہم کچھ ایسا پڑھ لیں جو ہمیں سیاسی عمل کے لیے مجبور کر دے۔ وہ چاہتی ہے آپ اُس کے تابع رہیں، اے۔ پولیٹیکل روبوٹ بن کر استحصال برداشت کیے جائیں۔ ریاست نہیں چاہتی کہ ”کتاب گھر“ جیسا کوئی اور گھر ہو۔ وہ ہمیں لکیر کا فقیر بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور یونیورسٹی کے زوال کی وجہ بھی یہی ہے۔ لیکن بہت ہو چکا، اب ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں اور پانے کو بہت کچھ ہے۔

ماخذ: پڑھا لکھا پاکستان