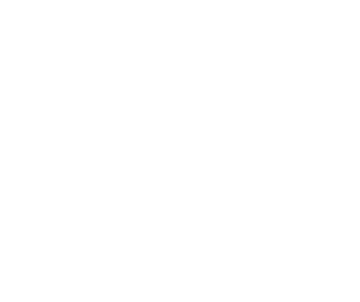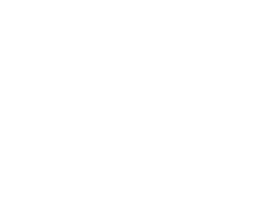مِصری کی ڈلی اور مصفا چینی: ترجمہ اور اس کی گتھیاں: محمد عمر میمن (ترجمہ: اسد فاطمی)
میں جب اوائل دسمبر ٢٠١٠ء میں کراچی آیا تھا، بینالاقوامی اردو کانفرنس اپنے دوسرے دن میں تھی۔ اگلی صبح میں نے اردو افسانہ پر دن کے پہلے اجلاس میں شرکت کی۔ مخاطبین نے آ کر دس منٹ کی تقریر کی، کچھ نے دس منٹ کے دھواں دھار بھاشن دیے۔ میرا بھولپن کہ میں کوئی لکھے پڑھے مدلل مقالات کی امید لے کر آیا تھا۔ میں نے اُٹھ آنے کا فیصلہ کیا۔ آڈیٹوریم سے باہر کسی نے مجھے بلا کر بتایا کہ ٹی وی چینل ون اپنے پروگرام ’ دی بک کلب ‘ کے لیے مجھ سے مصاحبہ کرنا چاہتا ہے۔ بھئی ہاں، کیوں نہیں؟ ہر کسی کو ظریفانہ فراغ کا کوئی لمحہ درکار ہوتا ہے، خاص طور پر دانائی کی ایسی پیٹ بھر خوراک کے بعد جو کہ مجھے اس سیشن میں شرکت کے دوران میسر رہی۔ٹی وی والوں نے آرٹ کونسل کی عمارت کے پچھواڑے میں کھلی فضا میں تقریب کے لیے اسٹیج کے طور پر استعمال ہونے والے ایک چبوترے پر اپنے کیمرے، عکاسیے، کیبلیں اور چلچلاتی دھوپ تلے کیا کچھ نصب نہیں کر رکھا تھا۔ مسعود اشعر اور اردو کے ہمہ اوست بڑے میاں، حضور والا انتظار حسین، پہلے سے ہی اپنی آرام دہ نشستوں پر تشریف فرما ہو کر نگوڑی مکھیوں کو ہاتھوں کے پنکھ مار کے اڑا رہے تھے۔
قریب قریب گھنٹہ بھر طویل مصاحبے میں ہمارے سامنے متعدد سوالات رکھے گئے، میرے خیال سے، جن کے دوہرانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ کیا فکشن کی برتری نے، خاص طور پر، مغرب میں ناول میں، اردو کے ادبی حلقے میں کوئی قابل موازنہ بحث چھیڑی ہے؟ مسعود اشعر: ’’ بہت زیادہ نہیں!‘‘ انہوں نے اس بابت دو نکات پیش کیے: (١) عالمی ادب تک ہماری رسائی انگریزی تراجم کے ذریعے ہوتی ہے، اور (٢) انگریزی تراجم بھی بسا اوقات نادرست ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دعوے کی حمایت میں ٹالسٹائی کے وار اینڈ پیس اور پراؤست کے À la recherche du temps perdu (گمشدہ وقت کی تلاش میں) کے سات تراجم کا تذکرہ کیا۔تاہم انہوں نے موضوع اور اسلوب دونوں میں اردو پر خارجی اثر کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے اردو کی افسانوی پیداوار پر اثر، کی معین شرط یا تعریف بتانا گوارا نہیں کی۔
مجھے ایسا لگا کہ یہ جواب ترجمے سے وابستہ پیچیدہ مسائل کو گرفت میں نہیں لا سکا، بر سبیل تذکرہ: ہمارا پچھمی پڑوسی، ایران، سو فیصد خواندگی کو پہنچ رہا ہے۔ وہ باقاعدگی سے مغربی سائنسی، ادبی اور فلسیانہ کاموں کے فارسی تراجم شائع کرتے ہیں۔ حال ہی میں میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے واقعتاً علاوہ از دیگر، لاطینی امریکی اور ہنگارین ناولوں کا ایک ذخیرہ ترجمہ کر رکھا ہے۔اس کے بالعکس، پاکستان میں خواندگی کی فیصدی شرح افسوسناک حد تک نیچے ہے اور اس میں اردو کا حصہ اور بھی کم ہے۔ اردو والوں میں فکشن پڑھنے والے ایک فیصد یا اس سے بھی کم ہوں گے۔ اب کلاسیکی، شاہی خلعت والے اہل قلم، دانشمند حکماء، مصور اور موسیقار ماضی کا قصہ ہیں، ایک اردو لکھاری محض اپنی تحاریر کے بل پہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمارے بیشتر لکھاری، بشمول اشعر اور انتظار صاحب، اپنی روزی تخلیقی نگارش کے علاوہ پیشوں سے کماتے ہیں۔ اور کچھ لکھاری اپنے کاموں کی اشاعت کا خرچ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔١٨ کروڑ سے زائد کی آبادی میں زیادہ تر ادبی کتابوں کی مطبوعہ گردش ٥٠٠ نسخوں سے زیادہ نہیں ہو پاتی۔ تقسیم کے وقت یہ ١٠٠٠ یا ١١٠٠ تک ہوتی تھی۔ (بجا طور پر، سبھی جانتے ہیں کہ اصل مطبوعہ گردش ٥٠٠ نسخوں سے زائد ہے۔ ناشرین بڑے ہوشیار لوگ ہیں! لیکن ایک ٥٠٠٠ یا ١٠،٠٠٠ کی ترسیل بھی چند مہینوں سے زیادہ میز پر کھانا فراہم نہیں کر سکتی۔) اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے، ادب میں پرجوش دلچسپی اور جانفشانی کے فقدان کی بانسری بجانا کس قدر معقول ہے: طبعزاد تحریر، ترجمہ اور مباحثہ؟کیا ہمیں شاید پہلے خواندگی کو بڑھانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟
اب زیادہ قائم بالذات مسئلے کی طرف آتے ہیں، یہ کہنا کہ کسی مغربی لکھاری کے متعدد تراجم اس لیے سامنے آتے رہے ہیں کہ گزشتہ تراجم کو ’’غیر صحیح‘‘ سمجھا گیا تھا، معاملے کو بالکل سادہ بنانے کے لیے ہے۔ اختلافات سطح تک محدود ہیں کیونکہ سادہ سی بات ہے کہ ہر معاشرہ اور نسل بالباطن خود اپنے لیے ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہر نسل کے اندر مختلف لکھاری اپنی شخصیتوں اور بصیرتوں کو کسی فن پارے میں لے آتے ہیں، جو صرف ایک ترجمہ دستیاب ہونے کی صورت میں کھو سی جاتیں۔ فنون لفظی میں صحیح یا غیر صحیح نامی کوئی شے نہیں ہوتی۔ تخلیقی طور پر استعمال کیا گیا ہر لفظ خود اپنی ذات میں بہت سے ٹھاٹ باٹھوں والی چیز ہوتی ہے۔ مترجم دیکھتے ہیں کہ اس میں خود ان کے اپنے تجربے سے کیا کچھ میل کھاتا ہے اور وہ اس کا اپنے زمانے کی زبان میں اظہار کر دیتے ہیں۔ بہرکیف، ڈکنز، جؤائس، اور جولیان برنیس بالکل ایک جیسی انگریزی نہیں لکھ رہے۔ ١٩ویں صدی میں کیا گیا ڈکنز کا ترجمہ ٢٠ویں یا ٢١ویں صدی کے ترجمے سے نمایاں طور پر مختلف ہو گا۔ (خدا لگتی کہیے، اہل مغرب الزام سے ماورا نہیں ہیں۔ جورڈن الگرابلی کا ’ میلان کنڈیرا سے گفتگو ‘ (سالماگُنڈی ٧٣، سرما ١٩٨٧) کا ’ ترجمہ ‘ کے بارے حصہ ہی پڑھ لیں، تاکہ آپ اس کے ناول دی جوک کے انگریزی ترجمے پر کنڈیرا کے شکوے کے عجز، اور اسکی گہری مایوسی کو بہتر سمجھ سکیں)۔ پھر یہ مسئلہ ہے کہ کوئی لکھتا ہی کیوں ہے۔ اچھے فکشن کی جڑ میں دیکھی سنی دنیا اور لکھاری کی متصورہ یا متخیلہ دنیا کے درمیان بے ربطی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک بیتابی ہوتی ہے، جو اسے اپنی متخیلہ دنیا کو فکشن میں تعمیر کرنے پر مائل کرتی ہے۔انتظار صاحب نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ کوئی کہانی لکھنے سے پہلے وہ ایک بے نام سی بے کلی، ایک مبہم سا دھڑکا محسوس کرنے لگتے ہیں جو ان کو خوابوں میں بھی مسحور رکھتا ہے۔ پھر وہ ایک کہانی لکھتے ہیں جو ان کے لیے قابل ادراک ہو۔ دوسرے لفظوں میں، ایک کہانی اس سے پہلے کہ پیدا ہو، وہ ایک تحت الشعوری بے چینی سے گزر کر آتی ہے۔
اپنی مرضی کی ایک دنیا بُننے کی تمنا ایک لکھاری کو اپنے سماج سے الگ تھلگ بناتی ہے۔ وہ ایک بے وطنی کی سی کیفیت میں رہتا ہے۔اسے اپنے ہی لوگوں اور ماحول کے بیچ ایک اجنبی کہا جا سکتا ہے، ایک مردود، ایک منحرف، ایک باغی، جو بہاؤ کی مخالف سمت میں تیرتا ہے۔ چونکہ وہ حقیقت سے فقط مہین سی مشابہتیں رکھنے والی ایک تخیلاتی دنیا ہوتی ہے، اس کا بنیادی وسیلہ ایک ایسی زبان ہوتی ہے جو بنیادی طور پر معلوم کی صراحت کے لیے شکل میں لائی گئی ہوتی ہے (کیونکہ ان اشیاء کے لیے کوئی شایان لفظ نہیں ہوتے، بلکہ مناظر سے ہوتے ہیں جو مبہم انداز سے دماغ میں موجود ہوتے ہیں) اور وہ کچھ بیان کرتے ہیں جو ملموس تجربے میں سما سکتا ہے، نہ کہ وہ جو حسیت اور ادراک کے اس کنارے پر جھلملاتا ہے، اور جو اپنے معرض اظہار میں آنے کے آئندہ لمحے کا منتظر ہوتا ہے۔عین یہی وہ مقام ہے جہاں لکھاری کا مرکزی مسئلہ جاگزین ہے:کلمۂ مقصود کی تلاش۔لّوسا نے تذکرہ کیا ہے کہ کروئسے میں فلابیر کے مکان کے قریب نیمو کے پیڑوں کا ایک ایوان تھا جو allée des gueulades یعنی ’’ چلّانے کا گلیارا‘‘ کہلاتا تھا۔فلابیر وہاں جاتا تھا اور جو کچھ اس نے لکھ رکھا ہوتا، اسے بآواز بلند پڑھتا۔ اس کے کان اسے بتاتے کہ آیا جو اس نے لکھا ہے وہ سننے میں بھلا ہے یا اسے صحیح لفظ کی تلاش جاری رکھنی پڑے گی۔ لکھاری کی اپنے پرمغز مناظر کی عکاسی کی بیتابانہ مساعی، اپنے تمام دھندلے انعطافات کے ساتھ، ایک ایسی زبان میں جو اکثر اوقات اسے اس کے تخلیقی استعمال پر، اسے توڑنے موڑنے، دھجیاں اڑانے، اور اگر ضرورت پڑے، قواعد انشا کو تلووں تلے کچلنے پر اکسانے میں کام آتی ہو۔
ایک مترجم کا کام اور بھی زیادہ مشقت طلب ہے، مہیب لسانی اشکالات سے معمور، خاص طور پر اگر وہ ایک کثیر الثقافتی متن کا ترجمہ کر رہا ہو۔ (بجائے دیگر، میرے اپنے تراجم میں مجھے کبھی کبھار ایسے جملوں سے واسطہ پڑتا ہے جو مصنف نے عمداً مبہم چھوڑ دیے ہیں۔ کوئی پہلے یہ جان لیے بغیر ترجمہ کیسے کر سکتا ہے کہ ابہام چھوڑنے یا چھپا لینے کا کیا مطلب ہے؟) میں اس بحث سے متعلق ہونے کی بدولت کچھ اکا دکا اور سوالات کو بھی یہاں بیچ میں لاؤں گا جو کہ اس مصاحبے میں آگے چل کے مجھ سے پوچھے گئے۔ کیا ترجمہ پڑھنے میں ہموار نہیں ہونا چاہیے؟ مصاحبہ کار نے انتظار صاحب کو نقل کرتے ہوئے، اضافہ کیا،’’ اسے منہ میں مِصری کی ڈلی کی طرح منہ میں کھنکنا نہیں چاہیے۔‘‘ جبکہ اشعر صاحب نے انتظار صاحب کو عطیہ حسین کے Sunlight on a Broken Columnکے ترجمے پر داد دی، جو پڑھنے میں ایک طبعزاد اردو ناول جیسا لگتا ہے۔میرے خیال سے اعزازی غنائیت ڈالنے سے بہت کچھ کھو گیا تھا۔
مغربی زبانوں سے کیے گئے سبھی تراجم ہمیشہ طبعزاد اردو ناولوں کی طرح نہیں پڑھے یا پڑھائے جا سکتے، جیسا کہ کافی کے کپ میں مصفا چینی، جو پلوں میں پگھل جاتی ہے، اور شدید اثرات کے ساتھ سرعت سے گردشِ خون میں رواں ہو جاتی ہے۔ ایسے ناولوں کو ترجمہ کرنا کافی آسان تر ہوتا ہے جو مترجم کے اپنے ثقافتی محیط سے پھوٹتے ہوں۔ ان کی زبان سے قطع نظر، ان کے رمز و ایما اور فضا بڑی حد تک قابل شناخت رہیں گے، بشرطیکہ کوئی زوردار سا شخصی تخلیقی عنصر مداخلت نہ کر ڈالے۔ دونوں کی لکھاریانہ صلاحیتوں اور شخصیتوں کے لحاظ کی رعایت اپنی جگہ، اگر عطیہ حسین ایک اردو لکھاری ہوتیں تو وہ انتظار صاحب کے ترجمے سے کچھ مختلف نہ لکھتیں۔ سادہ بیانی کی غرض سے، دنیا کو صرف دو ثقافتی حیطوں میں کاٹ کر بانٹ دیتے ہیں: مغربی اور غیر مغربی۔ یورپی زبانوں اور تراجم میں ایسے مشترک رمز و ایما، دیومالاؤں، داستانوں اور کتھاؤں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، جو اس مفہوم میں فرض کیجیے، چیک اور فرانسیسی میں، نسبتاً آسان ہیں۔ ان کی خونریز جنگوں اور معاندانہ تعلق سے بلا لحاظ، جو ان کی تاریخ میں مشترک ہیں۔ وہ سبھی چھری کانٹا استعمال کرتے ہیں، اور ہاں، استنجے کا پارچہ بھی۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ سیلائن (Céline) کا’آخرِ شب کا سفر‘یا’قسطوں میں موت‘کا ترجمہ کرنا چاہتے ہوں، جن میں اس نے بھانت بھانت کے پھکڑوں کا دلیرانہ برتاؤ کیا ہے جو معاصر فرانسیسی کے اسلوب نگارش اور عمومی مزاج سے ہٹ کر ہے۔ انتظار صاحب نے جؤائس کے تمام تر اعتراف فن اور اس کو ہمسری کے لیے ایک نمونہ بنانے کے باوصف، کبھی یولیسس (Ulysses) کا ترجمہ کرنے یا، اللہ بھلا کرے، اس کی ہمسری کرنے کا میلان محسوس نہیں کیا۔
معاصر اردو اشاعت رموز اوقاف کے ایک چکرا دینے والے غلط برتاؤ سے پُر ہے۔ اکثر ہمیں اوقاف کی ایک پوری تان (۔۔۔۔۔۔) نظرآتی ہے، لیکن اس کی شانِ نزول قاری کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ شاید لکھاری سمجھتا ہے کہ اس کا کل مقصد قاری پر وفور طاری کرنا ہے، تو تین پر کیونکر رکا جائے، جتنے زیادہ ہوں اتنا بہتر ہے، اور یہ عدد چار، پانچ، چھ اور آگے گنتے جائیے، اور تازگی کی ایک علامتِ وقفہ کی نذر کریں۔ حذفی اشارے کا استعمال، بالفاظ دیگر، من مانا اور بے سوچا سمجھا معلوم ہوتا ہے، جو بیانیے کے مجموعی ارادےمیں کوئی مفید غرض نہیں بجا لا رہا ہوتا۔ معاصر مغربی فکشن میں، رموز اوقاف کی اپنے مسلّم قواعد انشائی مقصد سے ہٹ کر اپنی اغراض ہوتی ہیں۔یہ بے شکن انداز میں اس بافتے میں بُنا جاتا ہے، جو فی الواقع خیال کا ایک جزو لاینفک ہوتا ہے۔ میں آپ کو کنڈیرا کا آمنا سامنا(Encounter) پڑھنے کا کہوں گا، پورا ناول نہیں بلکہ ناولوں کے بارے حصہ ، یا پھر انور بن مالک کا افسانہ ’ ڈنڈ ‘۔ جاتک طرز کے مستقیم بیانیے اور وہ جو پلاٹ پر انحصار کرتے ہیں شاید ان بیانیوں کی نسبت کم مسائل کھڑے کرتے ہیں جہاں مکانی گردشیں اور وقتی قربتیں بآواز بلند پڑھنے سے کچھ زیادہ ہی آپ کے ذہن پر گراں ہوتے اور کان کو چھیلتے جاتے ہیں۔مختصر جملے بجا طور پر انگریزی میں کوئی نادر شے نہیں ہیں؛ اگر ایک لکھاری ایک طویل جملہ لکھنے کی راہ اختیار کرتا بھی ہے، تو وہ کسی بیانیے کے کسی متعین مقصد کے تحت کرتا ہے (جیسے کہ خاویر ماریاس یا ہوزے سراماگو کے ناولوں میں)۔ طویل جملوں کی مختصر جملوں کے ایک سلسلے میں تقطیع کر دینا اردو کے کام و دہن کے لیے زیادہ مرغوب رہتا ہے، لیکن اس کی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے۔ بطور شغل، ذیل کو ترجمہ کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ آیا آپ کو ہوا میں اڑنے (یا مصفا چینی کے منہ میں گھلے جانے کا) کا سا احساس ہوتا ہے، یا ایک ہنڈولے میں بل کھاتے جھولے لینے (مصری کی ڈلی) کے جیسا:
’’ یہ بدچلنی کی ایک مہذب، خلوت پسندانہ سی شکل لگتی تھی۔ اور اسی وجہ سے، وہ تمام (اپنی استادانہ ناپسندیدگی کا مزہ چکھنے، اسے زبان سے چھونے اور ایک مٹھائی کی طرح چاٹنےپر) تمام تر سنجیدگی سے راضی تھے۔ ‘‘
It appeared to be a civil, solitary form of corruption. And for this very reason, they all agreed (savouring their teacherly disapproval, touching it with their tongues, sucking it like a sweet) all the more serious
اور یہ کسی یورپی لکھاری نے بھی نہیں لکھا، بلکہ ہماری پڑوسن اروندھتی رائے کا ’ گاڈ آف سمال تھنگز ‘ ہے۔
باون سال پہلے، محمد حسن عسکری نے ادب میں اسمائے صفت کے استعمال کے حوالے سے ایک مضمون میں اردو سے مخصوص کچھ مسائل کی نشاندہی کی تھی۔ مجھے ان کے داؤ کے جملے میں سے تیسری مثال نقل کرنے دیجیے۔ آپ سے تین میں سے دو ترجموں کے سبق حل کروائے جا چکے ہیں، ’’ سو آپ لکھتے ہیں’ کف در دہاں، چیختی چنگھاڑتی میز ‘‘‘ ۔ یہ جملہ، بلاشبہ، ایک بڑا واضح منظر ہے، لیکن اردو والے کہیں گے: ’ان صاحب کا دماغ چل گیا ہے! بھلا کسی نے میز کو بھی منہ سے کف بہاتے دیکھا ہے؟‘ جانے دیجیے، فکشن میں میز چیخ اور چنگھاڑ سکتی ہے۔
ایک اور مسئلہ: اردو کے جیالے – بلحاظ کہ کون کہہ رہا ہے – اردو کو دنیا کی دوسری یا تیسری بڑی زبان کے درجے پر فائز کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ایک سپاٹ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اداروں نے انگریزی کےبطور خاص حساس ادبی ذخیرۂ الفاظ کے لیے ایک انگریزی اردو لغت مرتب کرنے کے لیے شاذ ہی کچھ کیا ہے۔ میں نے ایلان پاپے کی چوکھٹے سے باہر (آؤٹ آف دی فریم) کے٣٠صفحات کا ترجمہ کرنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے، حالانکہ وہ کوئی فکشن کا کام بھی نہیں ہے بلکہ فلسطین اسرائیل تصادم کے بارے میں ہے۔ میں اکثر اردو نحویات کے بارے میں بھی حیران ہوتا ہوں، یک لفظی اسمائے ظرف کا فقدان، اور روانی کا یہ تقاضا۔ اگر آپ معاملے کو کچھ اور نزدیک سے دیکھیں، تو یہ نظر انداز کرنا مشکل ہو گا کہ اردو بالباطن خطابت کی زبان ہے، قرأت کی نہیں، جس میں آنکھ سے زیادہ کان استعمال ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے یہ کافی محسوس ہوتا ہے کہ اردو بدستور زبانی تکلم کے لیے ہی موزوں ترین ہے۔ لیکن ہم آگے بڑھ آئے ہیں – کیا ایسا نہیں ہے؟ – اور مزید سے مزید مطبوعہ ورق کے محتاج ہوئے ہیں۔ کوئی شخص اپنا ہی ذرا سا طویل جملہ من و عن دوسرے جملے یا دو جملوں میں پھر سے نہیں دوہرا سکتا۔ وہ اسے مختصر اور سادہ رکھنے پر مجبور ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی ورق سے پڑھ رہا ہے، قطع نظر اس سے کہ کتنی بار جملۂ معترضہ، حذفی نشان، یا خطوط شرطیہ (—) اچانک مخل ہو کر نثری آہنگ کو توڑ ڈالیں، اسے بس چاہیے کہ آنکھ اوپر اٹھائے اور ٹوٹے دھاگے کو گانٹھ دے۔ اسے ایسا کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ آنکھ ایک بڑے حیطے کو گھیرتی ہے اور کم از کم چار سے پانچ سطریں بیک وقت اس کی حدود کے اندر ہوتی ہیں، اور اس کی سطحی نظر میں اس سے زیادہ کچھ آتا ہے۔ اصوات غائب ہو جاتی ہیں، مکتوب لفظ اپنی جگہ جما رہتا ہے۔
فکشن، اس کی مغرب میں تفہیم کے اعتبار سے، اردو میں ایک مستعار لی گئی ہیئت ہے۔ ہماری ماقبل جدید، ماقبل نوآبادیاتی بیانیہ نثری ہیئت داستان تھی، مغربی افسانے اور ناول سے مختلف ایک افسانوی امکان۔تاہم اسے ہمیشہ داستان گو زبانی بیان کرتے ہیں۔
اب جبکہ ہم سینہ بہ سینہ سے، پوری طرح مطبوعہ، خواندگی کے عہد میں آ چکے ہیں، اس کے لیے درکار ساز و آلات کی ایک پوری سپتک کے باوصف،جس میں آنکھ خیال کی ترسیل کا بنیادی وسیلہ ہوتی ہے، مجھے یقین ہے کہ کبھی نہ کبھی ہم معاصر نثر کے کھڑکھڑاتے سُروں اور بسا اوقات شکستہ آہنگوں کے عادی ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے مسعود اشعر، انتظار حسین، اور مصاحبہ کار حضرات، در حقیقت ہر کوئی جو ایک ترجمے کی کامیابی کو اس کی قدرے ہموار اور رواں معلوم ہونے کی خاصیت کا حامل پاتا ہے، اسے میری اوپر کہی گئی باتوں کو خاطر میں لانا ہو گا۔ اور ظاہر ہے، میں اچھے تراجم کی بات کر رہا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ ضروری نہیں روانی ہی ’’اچھے پن‘‘ کا کل معیار ہو۔ میں نے ’’ قدرے ‘‘ کہا کیونکہ ’’روانی ‘‘ اور ’’ پڑھنے میں ایک طبعزاد اردو ناول جیسا لگنے ‘‘ کے علاوہ کوئی کسوٹی پیش نہیں کی گئی تھی۔
مجھ سے مغرب میں اردو افسانوی تراجم کی پذیرائی کے بارے میں پوچھا گیا۔ میرے ذہن پر ’’ موضوع‘‘ اور دیگر سوالات قابض تھے: کیا ہمارا فکشن جدید زندگی کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے، کیا یہ مغربی پیداوار کی سطح پر پہنچتا ہے؟ انتظار صاحب کو اس بات پر شبہات ہیں کہ اگر اس کی کوئی مساعی کی گئی ہیں تو وہ وابستہ تقاضوں کو نبھاتی ہیں، یہ مساعی ایک تخلیقی سطح پر بھی کچھ خاطر خواہ پوری نہیں اترتیں۔ انہیں یہ بھی لگا کہ ہمارے بڑوں کے یہ دعوے مضحکہ خیز ہیں کہ ہمارا فکشن مغرب کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کے قابل ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے چیخوف اور جؤائس کے پائے کا کوئی ایک آدھ کام پیدا کر بھی لیا، جو کہ او ہنری سے کاندھے ملاتا ہو، تو کیا تیر مار لیا۔
یہ سوال کچھ غیر متعلقہ سا لگتا ہے۔ مجھے لگا کہ فکشن کا مقصد انسان کے داخلی تقاضوں کو نبھانے میں پنہاں ہے، کسی ایسے خارجی ماجرے کے حوالے کی مدد سے جو اس کے اپنے بارے میں کسی سچائی سے پردہ اٹھانے کا بہانہ بن سکے۔ تو فکشن نے خارجی زندگی کے تقاضوں، جدید یا دیگر، کی برآری کی ذمہ داری پر کب سے زین کس لی ہے؟ اور ’’ موضوع ‘‘ – فکشن میں اس کا مقام اور بھی زیادہ ہے – کیا یہ ایک بری تعریف کی حامل پھسلواں ڈھلان نہیں ہے؟ جب ہمارے نقاد اور لکھاری اسے برتتے ہیں تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کوئی خارجی شے ہے جو کسی کام کو معنی دیتی ہے۔ بٹوارے کے دوران گروہی فسادات کو اکثر ان پرآشوب وقتوں کے ادب کا ایک موضوع بتایا جاتا ہے۔حالانکہ، اگر کوئی چیز اس کو معنی دیتی ہے، تو وہ ہے ایک افسانوی کردار کا کسی وجودی کیفیت میں کسی خارجی ارادے کے سامنے برتاؤ۔ مدتوں پہلے عسکری صاحب نے ١٩٤٧کے گروہی فسادات کے تناظر میں ’’ موضوع ‘‘ کے بارے میں عمومی غلط فہمیوں کو رفع کرنے کی کوشش کی تھی۔ منٹو کے سیاہ حاشیے کے دیباچے میں لکھا کہ لکھاری اور قاری دونوں اپنے نیک جذبات کی تصدیق نو چاہتے ہیں۔ ’’ دراصل ادب کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کون ظلم کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ ادب تو دیکھتا ہے کہ ظلم کرتے ہوئے اور ظلم سہتے ہوئے انسانوں کا داخلی اور خارجی رویہ کیا ہوتا ہے۔ جہاں تک ادب کا تعلق ہے،ظلم کا خارجی عمل اور اس کے خارجی لوازمات بے معنی چیزیں ہیں۔ ‘‘ اور: ’’ یہ افسانے فسادات کے متعلق نہیں ہیں، بلکہ انسانوں کے بارے میں ہیں۔ ‘‘
فلسطین کے مسئلے پر ایلی ویزل کے تبصرے کو جانے دیں، لیکن کیا اس کے ’نائٹ ‘ کو ہالوکاسٹ کے بارے میں ایک ناویلا کہا جا سکتا ہے؟ بلکہ کیا یہ ایک ننھے یہودی لڑکے کے بارے میں نہیں ہے، جو خدا کا برگزیدہ بندہ ہے، جو کہ، فرانکوئے مورائس کے لفظوں میں، ’’ صرف خدا کے لیے زندہ رہا اور صرف زبور کی پیروی کرتا رہا، یہودی عارفانہ سلسلے میں داخلے کا خواہشمند رہا، ابدیت کے لیے خود کو وقف کیے ہوئے ‘‘ – ایک لڑکا جس نے اپنی روح کی گہرائیوں میں خدا کی موت کو آنکھوں سے دیکھنے کی ذلت اٹھائی اور پھر اس کے آگے نہیں جھکا؟ اسی طرح، منٹو کے ترکے کے متعلق، جس کی رجحان پرست سماجی دانشور اور مؤرخین پوری طرح غیر معتبر اور غیر نقادانہ زمرے بندی یوں کرتے ہیں کہ یہ کہانیاں (الف) بٹوارے کے بارے میں ہیں اور (ب) طوائفوں کے بارے ہیں جو کہ ایک ایسے احاطے میں گمراہ کن بلوہ کرنے کے مترادف ہے جس کے وارثوں نے اپنی ڈھالیں پھینک دی ہوں، اور اپنی ذمہ داریوں کو شرمناک طور سے ترک کر چکے ہوں۔
انتظار صاحب اپنی اس ناامیدی میں حق بجانب ہیں کہ اردو فکشن کے مغربی فکشن سے موازنے کی تمنا طفلانہ ہے۔ میرے نزدیک یہ تمنا ایک عجیب اضطراب اور ایک بنیادی کم اعتمادی کا اظہار ہے۔ جیسے کہ ایسا موازنہ قائم کرنے سے، کسی عالمی سطح کے لکھاریوں کے کلب کی رکنیت، خواہ اعزازی ہی سہی، ہمیں عطا ہو جائے گی۔ پوچھے جانے کے لائق سوال یہ ہے: اگر اردو فکشن کا ہم سے کوئی عہدو پیمان تھا، وہ کس قدر ایفا ہوا ہے۔
بشکریہ: ڈان آرکائیو