اڑن کھٹولا (تحریر: محمد حامد زمان)
”کیا آپ پاکستان سے ہیں؟“ میں نے قریب آ کر پوچھا۔
مقامی لباس میں ملبوس افراد کے سمندر میں ایک ہی شخص تھا کہ جو اپنی سفید شلوار قمیض کی وجہ سے پردیس میں بھی بدیسی دکھائی دیا۔ مئی کے دن تھے، کڑکتی دھوپ اور دوپہر کا وقت۔ جمعے کی نماز ابھی حال ہی میں ختم ہوئی تھی۔ سب لوگ مسجد سے نکل کر ایک طرف جا رہے تھے اور میں اس دھارے کی دوسری طرف۔ اس دھارے میں شامل کچھ افراد نے مجھ سے دامن بچایا اور مجھے جگہ دی، اور کچھ نے اپنے کاندھے مزید چوڑے کر لئے اور راستہ نہ دینے کا عزم مزید پختہ کیا۔ ایک دو نے گھورا، ایک آدھ نے کچھ کلمات سے بھی نوازا جن کا مطلب ہر زبان میں یکساں ہوا کرتا ہے۔ دیارِ غیر میں اجنبیت کا اگر کوئی احساس تھا تو وہ جاتا رہا۔ جمعے کی نماز سے نکلنے والے نمازی بھلے شمال میں ہوں یا جنوب میں، ان کا خمیر یکساں ہوتا ہے۔
نیل کے ساحل سے لے کر تابخاکِ کاشغر۔
یہ وہ دن تھے کہ ابھی دنیا میں کرونا کی وبا برقرار تھی۔ میں نے احتیاطاً ماسک پہنا ہوا تھا، مگر میری ناک پھر بھی بہہ رہی تھی، گو کہ حال ہی میں کیا گیا میرا ٹیسٹ بدستور منفی تھا۔ ماسک کی گھٹن، گرمی اور بہتی ناک کے ملے جلے ردِ عمل سے میری آواز اور مزاج دونوں میں ایک تغیر تھا۔ اس بات کو وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت میری ناک کیوں بہہ رہی تھی۔ کیا اس کی وجہ سفر کی تھکن اور نیند کی کمی تھی؟ یا اس کی وجہ ماحول میں شدید گرد اور غبار تھا، یا پھر میں ٹیسٹ خریدتے ہوئے نقالوں سے ہوشیار نہیں رہا تھا؟
ان حالات میں کسی اجنبی کا یکایک آپ کے سامنے آ جانا اور ایک غیر ضروری سوال کرنا یقیناً ایک چونکا دینے والا عمل ہوا ہوگا۔
سفید شلوار قمیض میں ملبوس باریش شخص کے پاس کئی راہیں تھیں۔ مثلاً یہ کہ وہ مجھے گھورتا، ماسک کی چلمن کے اس پار میری بہتی ناک کی طرف ایک نظر ڈالتا، اور کنارے سے نکل جاتا۔ یا پھر یہ کہ وہ اپنا فون نکالتا اور اس کو گھورتے گھورتے غائب ہو جاتا۔ یا سرے سے میری بات کا جواب ہی نہ دیتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ خالص مقامی لہجے میں ”معاف کرو با با“ یا اس سے ملتا جلتا کوئی جملہ کہتا اور اپنی راہ لیتا۔ مگر موصوف نے ایسا کچھ نہ کیا۔
”جی ہاں!“۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس صاحب نے جواب دیا۔
جواب سن کر شاید میں خود بھی کچھ حیران سا ہو گیا۔ میرا اپنا خیال تھا کہ بھائی ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ ایک لمحے کے لئے میں خود بھول گیا کہ مجھے پوچھنا کیا تھا۔
”کیا مسجد الحسین اس طرف ہے؟“ میں نے سوال کیا۔
”جی۔ اسی جانب ہے۔ مگر آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟“
اس اجنبی پر اب یہ بات واضح تھی کہ اول تو میں یہاں سے ہوں نہیں اور کسی شے کا متلاشی ہوں، اور دوئم یہ کہ مجھے خود بھی معلوم نہیں کہ مجھے کس چیز کی تلاش ہے۔ میری زندگی کا سب سے اہم اور بنیادی سوال گویا ان صاحب نے لمحے بھر ہی میں جانچ لیا تھا۔
اس اجنبی کا خلوص تھا، دوپہر کی گرمی یا پھر قاہرہ کا سحر، میرے رکھ رکھاوٴ، بناوٹ اور تکلف کے باندھے ہوئے بند ٹوٹ گئے۔ چند ہی لمحوں میں میں نے نہ جانے کیا کیا بتا ڈالا۔ میں آج صبح ہی اس شہر آیا تھا، ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ سب سے قدیم مسجد ابنِ طولون ہے، اپنے ہوٹل سے ٹیکسی لے کر وہاں گیا، ٹیکسی والے نے ٹھگ لیا مگر میں بحث نہ کر سکا۔ مسجد ابن طولون میں جمعہ کی نماز پڑھی، اپنی مغفرت کی بھی دعا کی اور ٹیکسی والےکے لئے ہدایت کی بھی۔ مسجد میں زیادہ لوگ نہ تھے بس ایک ڈیڑھ صف تھی۔ خطبہ کچھ سمجھ آیا اور کچھ نہیں۔ واپسی پر مسجد کے آس پاس کوئی ٹیکسی میسر نہ آئی تو کڑی دھوپ میں پیدل چلنے کی ٹھانی، کچھ اپنے فون پر راستہ دیکھا، اور کچھ کاتبِ تقدیر پر بھروسہ کیا، اور قدم ادھر لے آئے۔
معمول کے مطابق میں اپنے آپ اور اپنی کہانی میں اتنا گم ہو گیا کہ نہ تو موصوف کا نام پوچھا اور نہ ہی ان سے مصافحہ کیا۔ میری ناک مسلسل بہہ رہی تھی اور اس بہتی گنگا میں اب کھانسی کی طغیانی بھی شامل تھی۔
ایک مرتبہ پھر اس اجنبی کے پاس کئی راہیں تھیں۔ ایک سیدھا راستہ یہ تھا کہ موصوف کہتے کہ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اس جانب الحسین مسجد ہے، وہ رہی جامع الازھر اور برابر میں الازھر کی مسجد۔ میں قاہرہ میں آپ کے باقی ماندہ ایام کی عافیت کے لئے دعاگو رہوں گا۔ ایک راہ یہ بھی تھی کہ یہ صاحب کہتے کہ ابنِ طولون کی مسجد تو آپ نے دیکھ لی، اور کیا دیکھئے گا؟ میں آپ کے لئے ٹیکسی کا بندوبست کئے دیتا ہوں، اور اس سے بات کر لوں گا کہ غریب سیاح کو لوٹنا ایک غیر اخلاقی فعل ہے۔ مگر ان صاحب نے، جو کہ عمر میں مجھ سے کم تھے، ان میں سے کسی بھی راستے کا انتخاب نہ کیا۔
ہاتھ آگے بڑھا کر پہلے مصافحہ کیا۔
مجھے بھی شرم آئی، اور میں نے بھی اسمِ گرامی دریافت کیا۔
”قدیم قاہرہ میں کیا کچھ دیکھا ہے آپ نے۔“
”کچھ خاص نہیں۔“
”پھر آیئے میرے ساتھ۔“
میں نے تکلفاً بھی نہیں کہا کہ ارے نہیں چھوڑئیے، میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ میری سیاحی صلاحیتوں کا احساس مجھے بھی تھا اور پچھلے چند ہی لمحات میں ان صاحب کو بھی ہو چلا تھا۔
میں اپنے رفیق کے ہمراہ ہوگیا۔ لوگوں کی بھیڑ اب نسبتاً کم ہو چلی تھی۔ ایک سرنگ سے گزر کر ہم سڑک کی دوسری جانب آ گئے۔ الازھر کی مسجد ہمارے سامنے تھی، مگر مسجد سامنے ہوتے ہوئے بھی بہت دور دکھائی دی۔ دربان مسجد کے دروازوں کو مقفل کر رہے تھے۔ میرے میزبان نے بتایا کہ کرونا کے باعث مساجد صرف نماز کے اوقات کھلتی ہیں اور نماز کے فوراً بعد ہی بند ہو جاتی ہیں۔
یہ کہ کر وہ بائیں جانب کی ایک گلی میں مڑ گئے۔ کچھ آگے گئے تو ایک نکڑ پر رک گئے۔ یہاں پر وین در وین، جنہیں ہم پاکستان میں ہائی ایس بھی کہتے ہیں، قطار در قطار کھڑی تھیں۔ ایک میں ہم بھی سوار ہو گئے۔ کچھ دیر تک کنڈکٹر آوازیں ہانکتا رہا، پھر کچھ مردوں اور کچھ خواتین کو ٹھونسا، دروازے کو ایک مخصوص انداز میں زور سے بند کیا اور ڈرائیور سے چلنے کو کہا۔ ٹھونسی ہوئی اس ویگن میں پیر و جواں، مرد و خواتین سبھی سوار تھے۔ کرونا کی وجہ سے مساجد کے دروازوں پر مضبوط قفل ایک دنیا کا پتہ دے رہے تھے، مگر یہ گنجان آباد وین کہ جس میں میری سانس کی ڈوری پر پے در پے دیگر مسافروں کے پسینے کے تعفن سے حملے ہو رہے تھے، شاید کسی اور دنیا سے منسلک تھی۔ یہاں کاروبارِ زندگی کسی وبا کے دباؤ کے اثر سے ماورا تھا۔
نمازی کا جہاں اور ہے، سواری کا جہاں اور۔
جس سرعت سے میرے میزبان نے وین میں مجھے گھسایا، اور جس کمال سے انہوں نے کنڈکٹر سے گفتگو فرمائی، اس سے ظاہر تھا کہ موصوف مقامی رنگ میں رچ بس گئے ہیں۔ اس وقت کوئی دانشمندانہ بات تو ذہن میں نہ آئی، مگر میں کہاں رکتا تھا، جھٹ سے بولا:
”آپ کی عربی بہت اچھی ہے۔“
اب سوچتا ہوں تو اپنے میزبان کی مہربانی پر رشک کرتا ہوں۔ اگر کوئی اور ان کی جگہ ہوتا، مثلاً کہ میں خود، تو خاموشی سے وین کے دوسرے دروازے سے نکل جاتا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتا۔ مگر یہ صاحب مجھ سے بہت بہتر تھے۔ ٹکا سا جواب دینے کے بجائے صرف مسکرا دیئے۔
وین نے دوسری وینوں کی بھیڑ سے نکلنے کے لئے علامہ کی نہ سنی، اور اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا، اپنا راستہ خود تلاش کیا اور اپنی دنیا آپ پیدا کی۔ کھڑکی کھلی، تعفن کا زور کچھ ٹوٹا اور میں نے سانس لینا دوبارہ شروع کیا۔ میں نے اپنے ساتھی سے مزید کچھ سوالات کئے، اس امید پر کہ شاید وقت کے ساتھ پاسبانِ عقل جو کہ کچھ عرصے سے رخصت ہے، اب شاید لوٹ آئے۔ ساتھی نے بتایا کہ وہ الازھر میں ایم فل کے طالبِ علم ہیں اور کچھ برسوں سے قاہرہ میں ہیں۔
”الازھر کیسے آنا ہوا؟“ ایک مرتبہ پھر میرے سوالات کی نوعیت اور ہیئت دونوں ہی شعور اور دانشمندی سے عاری تھیں۔
لیکن شاید اس قسم کے سوالات پہلے بھی مجھ جیسے ان سے پوچھ چکے تھے، یا پھر ان کو سائل کا بھرم رکھنے کی خدا داد صلاحیتوں سے رب العزت نے نوازا تھا۔
میرے میزبان نے بتایا کہ وہ پنجاب کے رہنے والے ہیں، مدارس اور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں۔ الازھر کیسے آنا ہوا، تو اس کا جواب سیدھا سادھا ہے، الازھر کی جانب سے ہر برس وظائف پر دنیا بھر سے طلبہ و طالبات کو اس صدیوں پرانی درسگاہ پر علم حاصل کرنے کے لئے بلایا جاتا ہے۔ کچھ امتحانات ہوتے ہیں اور اگر آپ ان میں کامیابی حاصل کر لیں تو درسگاہ آپ کو مع وظیفہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اور ہاں جہاں تک آپ کا عربی کے متعلق سوال ہے، اس پر عبور کے لئے پہلا سال وقف کیا جاتا ہے۔
انہی باتوں کے دوران میرے ساتھی نے جیب سے چند نوٹ نکال کر کنڈکٹر کو دئے اور ہماری منزل کی اطلاع دی۔ اس قدر سرعت سے یہ کچھ ہوا کہ مجھے تکلفاً یہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملا کہ رکئیے! مجھے دینے دیجئے۔ اتنے میں ہماری منزل آ پہنچی۔ ساتھی اور میں سیدہ نفیسہ مسجد کے سامنے کھڑے تھے۔ سیدہ نفیسہؒ امام حسنؓ کے خانوادے سے تھیں اور گو کہ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی، ان کی عمر کا ایک طویل حصہ قاہرہ میں بسر ہوا۔ مورخین کے مطابق سیدہ نفیسہؒ اپنے وقت کے معروف محدثین میں شمار ہوتی تھیں اور ان کے بہت سے شاگردوں میں امام شافعیؒ بھی شامل ہیں۔ مسجد کا بیرونی حصہ کھلا ہوا تھا مگر اندرونی حصہ مقفل تھا۔ یہاں پر صرف ایک دربان موجود تھا۔ مجھے اندر جانے کا اشتیاق تو تھا مگر میں نہ تو زبان اور مقامی لہجے سے کچھ خاص واقف تھا اور نہ ہی قوانین کی خلاف ورزی کا شائق۔ مگر میرے ساتھی نے شاید الازھر میں عربی اور شریعت کے ساتھ ساتھ چہرے پر لکھی خواہشات پڑھنے پر بھی عبور حاصل کر لیا تھا۔ چوکیدار سے کچھ کہا، اور اس نے جھٹ سے اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا اور کھٹاک سے ایک دروازہ کھول دیا۔ اس مسجد میں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ مسجد کچھ بہت بڑی تو نہیں مگر میں جیسے ہی اندر داخل ہوا مجھے یوں لگا کہ تاریخ کے ایک وسیع سمندر میں غوطہ زن ہوں۔ ذہن میں بہت سے سوالات ابھرے۔ بارہ صدیوں پہلے یہاں پر کیا کچھ تھا اور کیا کچھ نہیں۔ اس مسجد میں آنے والے لوگ کون تھے؟ امام شافعیؒ کس راستے سے چل کر ادھر آتے ہوں گے؟ ان کے سوالات کی نوعیت کیا تھی؟ بحث کس کس موضوع پر ہوتی ہوگی؟ سوالوں کو ادھورا چھوڑا اور باہر نکل آیا۔ دربان کے ہاتھ میں دو نوٹ بطور ہدیہ تھمائے اور باہر نکل آئے۔
اب ہم اپنی اگلی منزل کی جانب رواں تھے۔
ہماری اگلی منزل کے لئے کسی وین اور کسی ٹیکسی کی ضرورت نہ تھی۔ یہاں سے تقریباً پندرہ بیس منٹ کی پیدل مسافت پر قاہرہ کی ایک معروف مسجد، سیدہ زینبؓ مسجد واقع تھی۔ سیدہ زینبؓ مسجد، حضرت امام حسینؓ کی ہمشیرہ سیدہ زینبؓ کے مزار سے منسلک ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق سانحہ کربلا کے بعد سیدہ زینبؓ قاہرہ تشریف لائیں اور یہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ کچھ اور مورخین اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے مطابق سیدہ زینبؓ کا انتقال دمشق میں ہوا اور ان کے نام سے منسوب مسجد شام میں واقع ہے۔ مورخین کے دلائل سے قطع نظر اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ متعدد مکاتبِ فکر سے منسلک عبادت گزاروں کے نزدیک قاہرہ کی یہ مسجد ایک نہایت قابلِ احترام و عقیدت مقام ہے۔ یہاں پر صوفی اور درویش صفت معتقدین کی بھیڑ ایک معمولی بات ہے۔ ہم لوگ صدر دروازے پر پہنچے تو دروازوں کو مقفل پایا، مگر سیدہ نفیسہؒ مسجد کے مقابلے میں یہاں لوگوں کی بھیڑ تھی، ایک بڑی تعداد میں لوگ اگلی اذان کے منتظر تھے، کہ موذن کی آواز کے ساتھ دروازے وا ہوں اور انہیں اپنی عقیدت کے اظہار کا موقع ملے۔ قاہرہ کی یہ مساجد پرانے شہر کے اس حصے میں ہیں جہاں سڑکیں، دوکانیں، بسوں کے اڈے، ٹھیلے والے اور مساکین سبھی ایک دوسرے میں شیر و شکر ہیں۔ بار بی کیو کی دوکان بھی سامنے ہے، اور وہیں موچی بھی بیٹھا ہے، ٹھیلے والے کی آواز بھی ہے اور گاڑی کا ہارن بھی، اذان بھی ہے اور طفلانِ محلہ کی کھلکھلاہٹ بھی، بستی کے پرانے مکین بھی ہیں اور میرے جیسے بوکھلائے اجنبی بھی۔
سیدہ زینبؓ مسجد کے اندر جانے کی تو کوئی سہولت نہ تھی، باہر سے ہی زیارت کی۔ اب میرے ہمراہ ساتھی نے ایک رکشہ روکا اور مصری لہجے میں ڈرائیور سے کچھ کہا۔ ڈرائیور نے سر ہلایا اور یوں ہم ایک رکشے میں براجمان ہو گئے۔ ابھی میں یہ فیصلہ کر ہی رہا تھا کہ پوچھوں کہ نہ پوچھوں کہ اب ہم کدھر کو چلے کہ معلوم ہوا کہ ہماری اگلی منزل امام شافعیؒ کا مزار ہے۔ وہ یہاں سے کچھ دور تھا اور میرے ساتھی کو اس بات کا علم تھا کہ شاید اس گرمی کے دباوٴ میں، میری بہتی ناک اور میں کہیں اچانک ڈھیر نہ ہو جائیں اس لئے رکشے پر انحصار زیادہ مناسب ہے۔
رکشے کے شور کے پیشِ نظر، اور میرے ماسک کے پردے کے باعث، باآوازِ بلند کچھ اور باتیں ہوئیں تو معلوم ہوا کہ میرے ہمسفر کی تحقیق کا موضوع شریعت میں منگیتر کے حقوق پر ہے۔ یعنی علمی دلائل اور فقہا کی بحث کی روشنی میں منگنی کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے اور شریعت کی روشنی میں حقوق کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے۔ گو میری اپنی تدریس و تحقیق ان امور سے متعلق نہیں، مگر نہ جانے کیوں حقوق کی بات چاہے فلسفے میں ہو یا قانون میں، عمرانیات میں ہو یا شرعی معاملا ت میں، میرے لئے ایک خاص کشش رکھتی ہے۔ میرے اندر اس بات کا تجسس ہمیشہ رہتا ہے کہ بدلتے معاشرے میں حقوق، بالخصوص ان لوگوں کے حقوق جن کو عرصہ دراز سے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے، کیسے اور کون متعین کرے گا، اور اس امر میں میری اپنی کیا ذمہ داری ہے؟ یکے بعد دیگرے میں نے اپنے ساتھی سے نہ جانے کتنے سوال کر ڈالے، ہر سوال سے کتنے ہی اور سوال جنم لیتے چلے گئے۔ بات حقوق اور ذمہ داریوں سے بڑھ کر علمی مباحثوں اور مسودوں تک آ پہنچی۔ رکشہ ایک ٹوٹی ہوئی سڑک پر جھٹکے کھاتا اپنی منزل پر آ پہنچا۔ اس بار میں تیار تھا، جھٹ سے کچھ نوٹ نکالے اور ڈرائیور کو دینے لگا، مگر میرے ساتھی کی تیاری مجھ سے بڑھ کر تھی۔ ایک ہاتھ سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے روکا، اور دوسرے سے رکشے ڈرائیور کو اس کا معاوضہ دیا اور رخصت کیا۔
شہر کا یہ حصہ قدرے خاموش تھا۔ نہ گاڑیوں کا رش اور نہ ہی بازار کی گہما گہمی۔ یہاں پر قدیم زمانے سے بہت سے مراقد اور قبور ہیں۔ قاہرہ کا یہ قدیم اور وسیع قبرستان القرافہ کے نام سے جانا جا تا ہے۔ اسی سڑک پر چلتے جائیں تو آخر میں امام شافعیؒ کا مزار اور اس سے منسلک مسجد ہے۔ ہچکولے کھاتا رکشہ ہمیں ہماری منزل پر لے آیا۔ یہاں پر ایک بڑی سے تختی آویزاں تھی۔ تختی پر جلی حروف میں مزار کی حالیہ مرمت کا ذکر تھا۔ میں نے تحریر پڑھنا شروع کی، جب آخری سطر پر پہنچا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ مرمت، اور حالیہ تزئین و آرائش کا پیشتر کام امریکہ کی مالی امداد سے ممکن ہوا۔ امریکی ادارے، یو ایس ایڈ کی فراخ دلانہ امداد کی بدولت عالمِ اسلام کے معزز ترین علما میں سے ایک کی مسجد اور مزار کی مرمت ممکن ہو سکی۔
مگر کیوں؟ میرے ذہن میں بہت سے سوالات نے جنم لیا۔ امریکہ کا امام شافعیؒ سے کیا تعلق؟ کیا مرمت کا یہ کام مشرقِ وسطی کی وسائل سے مالا مال کوئی اور ریاست نہیں کرسکتی تھی؟ اور وہ لوگ جو کہ امریکہ سے بہت سی وجوہ کی بنا پر ناخوش ہیں، مگر امام شافعیؒ سے اک گہرا روحانی اور علمی تعلق رکھتے ہیں، ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حکومتِ مصر اور اہلیانِ قاہرہ کیا اپنی علمی میراث کی قدر کھو بیٹھے ہیں، یا پھر روزمرہ زندگی کے شکنجے اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ اپنی میراث کی حفاظت کے لئے نہ اسباب ہیں اور نہ وقت؟
کچھ احباب نے مجھے میرے سفر سے پہلے ہی یہ بات باور کروا دی تھی کہ مصر کے مالی حالات ایک عرصے سے انتہائی سنگین ہیں۔ روٹی کی قیمت بدستور بڑھ رہی ہے۔ عام آدمی کا گزارہ کٹھن سے کٹھن تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔
اس وقت مجھے اپنے سکول کے زمانے کے ایک استاد یاد آ گئے۔ کہا کرتے تھے کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ چاند کو دیکھتا ہے تو وہ ادب تخلیق کرتا ہے، شعر کہتا ہے، چاند پر جانے کا سوچتا ہے۔ اور جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کو پورا چاند بھی ایک گول روٹی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ گھر میں اگر کھانے کو کچھ نہ بچے تو صدیوں پرانے مزار کی مرمت کیونکر ہو۔ مگر مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں۔ قاہرہ میں فلک شگاف عمارتیں بھی تعمیر ہو رہی ہیں اور اہلِ زر کے محلات بھی۔ روٹی کی قیمت کا بھاری بار غریب کے کاندھوں پر تو ہے، مگر حکومت اور اہلِ اسباب و وسائل کی ترجیحات کچھ اور بھی ہیں۔ میں نے اور میرے ساتھی نے صرف غور سے تختی کو پڑھا اور خاموش رہے۔ اپنے زخموں کو کرید کر کیا حاصل ہوگا؟
کہا جاتا ہے کہ گرمیوں میں دن کا سب سے گرم لمحہ عین اس وقت نہیں ہوتا جب سورج سوا نیزے پر ہو، بلکہ سب سے گرم وقت سہ پہر کا ہوا کرتا ہے جب نہ صرف دھوپ کی تمازت برقرار ہوتی ہے بلکہ دن بھر کی دھوپ ماحول کی ہر شے کو انگارہ بنا چکی ہوتی ہے، اور ہر طرف یہ سلگتے انگارے فضا کی تپش میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ میرے میزبان ساتھی کو شاید اس بات کا علم تھا۔ یا شاید اگر علم نہیں بھی تھا تو میری حالت دیکھ کر اب ہو چلا تھا۔ اب جو ہم اپنی اگلی منزل کی طرف چلے تو راستے میں آنے والی پہلی ہی دکان سے ٹھنڈے پانی کی کئی بوتلیں اور ٓائس کریم خرید لی گئی۔ اس بار میں نے پھر جلدی سے پیسے دینے کی کوشش کی اور ایک بار پھر بھرپور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔
عصر کا وقت ہونے کو تھا، ہم ایک مرتبہ پھر الازھر کی تاریخی درسگاہ کے احاطے میں آ نکلے۔ ابھی عصر کی اذان میں کچھ لمحے باقی تھے، مگر مسجد کے چوکیداروں نے نہ جانے کیوں ترس کھا کر ہمارے لئے دروازے کھول دئے۔ مسجد کے صحن میں جو داخل ہوئے تو میرے میزبان نے بتایا کہ آج بھی مسجد کے مختلف حصوں میں پرانے وقتوں کی طرح باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہر روز ایک جدول مسجد کے باہر چسپاں کر دیا جاتا ہے، جس میں ایک مکمل زائچہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ کون سا استاد کس وقت کیا تعلیم دے گا، اور کون سی کتاب کے کس باب پر بات کرے گا۔ ہر مکتبِ فکر کے علماء کا اپنا وقت مقرر ہے، جو ایک باقاعدہ ترتیب سے پورا نصاب مکمل کرتے ہیں۔ جس شخص کا جی چاہے، وہ اس سلسلے میں شامل ہو جائے۔ قدیم زمانے کے اس تدریسی نظام کا سن کر یوں لگا کہ جیسے میں کسی اور دنیا میں آ نکلا ہوں، جہاں علم کے حصول کے لئے بنیادی ضرورت تجسس اور لگن کی ہوا کرتی تھی، معاش، ٹیوشن اور مقابلے کی ان تھک دوڑ کی نہیں۔ گو کرونا کی وبا سے وقتی طور پر یہ سلسلہ معطل ہے، مگر امید ہے کہ جلد ہی اپنی صدیوں پرانی ڈگر پر آ نکلے گا۔
مسجد کے اندر داخل ہوکر مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہی کیفیت جو کسی بھی قدیم درسگاہ میں داخل ہو کر ہوا کرتی ہے۔ یہ سوچ کر کہ انہی ستونوں کے سہارے نہ جانے کس صاحبِ علم و ہنر نے فکر کی کون کون سی نئی راہیں تخلیق کیں، کس کونے پر کس عالم نے پہلی بار ایک پیچیدہ مسئلے کو جانچا، پرکھا اور ہماری انفرادی اور اجتماعی سوچ کو یکسر تبدیل کر دیا۔ اذان شروع ہوئی تو میرے ساتھی نے صلاح دی کہ ٓایئے مسجد الحسینؓ چلتے ہیں، نماز وہاں ادا کریں گے۔ ہم لوگ باہر آ گئے، سڑک پار کی اور مسجد الحسینؓ چلے آئے۔ یہ مسجد غالباً پورے مصر میں عقیدت مندوں کے لئے سب سے مقدس مقام ہے۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت امام حسینؓ کا سرِ مبارک یہاں دفن ہے۔ ہم مسجد میں داخل ہوئے تو یہاں الازھر کے مقابلے میں کہیں زیادہ رش تھا۔ کچھ لوگ خاموشی سے دعا کر رہے تھے اور کچھ پر ان کے جذبات واضح طور پر غالب تھے۔ پھر نہ جانے کیسے مجھے اور میرے ساتھی کو پہلی صف میں جگہ مل گئی۔ عصر کی نماز ادا کی، اور یہ جانتے ہوئے کہ ابھی کچھ ہی دیر میں مسجد کو تالے لگا دیا جائیں گے، ہم لوگ باہر آ گئے۔ میرے ساتھی نے مجھ سے اجازت چاہی۔ وقت جو پچھلے دو گھنٹوں میں کھچ کر وسیع ہو چلا تھا، اچانک سکڑ گیا۔ میں مسجد الحسینؓ سے چند قدم دور اسی مقام پر آ گیا جہاں پر گویا ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں ایک شخص سے ملا اور اس کے ہمراہ تاریخ کی کتنی راہ داریوں سے گزر گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میرے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔


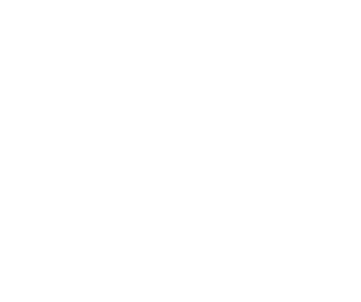
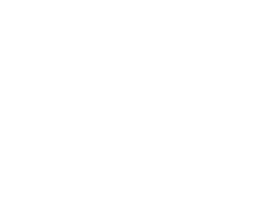



بہت خوب حامد زمان صاحب۔ آپ کی مرصع نثر میں اس تذکرے نے بہت لطف دیا۔ یوں ہی یاداشتوں سے نوازتے رہیے۔ اللہ کرے زورِ قلم اور زیادہ۔