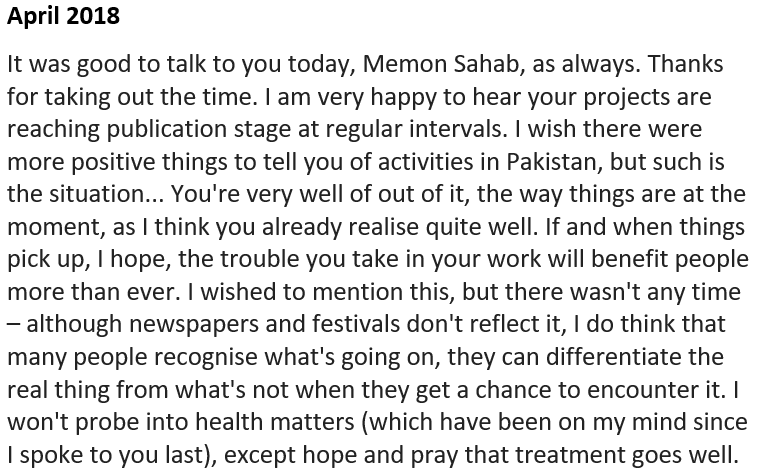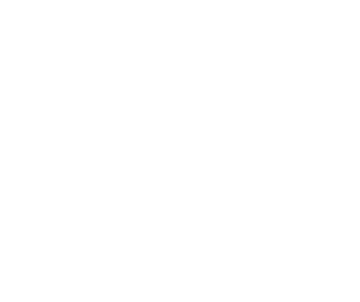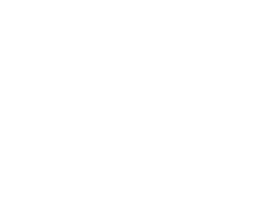محمد عمر میمن کی یاد میں: زہرا صابری (مرتب: عاصم رضا)
یہ کلمات زہرا صابری صاحبہ نے T2F، کراچی میں محمد عمر میمن کی یاد میں منعقدہ ایک تعزیتی نشست میں ارشاد فرمائے اور عاصم رضا صاحب نے انہیں قلمبند کیا۔ یہاں اس گفتگو کا اضافہ شدہ ورژن پیش کیا جا رہا ہے۔
زہرا صابری: میری میمن صاحب سے ملاقات۲۰۱۴ء میں ہوئی تھی۔ ۲۰۱۸ء میں ان کی وفات ہو گئی۔ ہماری دوستی چار سال تک رہی اور بہت تیزی سے گہری ہوتی گئی۔ میں اس کو دوستی کا نام اس لئے دے رہی ہوں کیونکہ میں نہ ان کی شاگرد تھی، نہ ہی ان کی کتابوں کی پبلشر تھی، نہ کبھی میں نے ان کے ساتھ کسی ادارے میں یا کسی پراجیکٹ پہ کام کیا تھا، لہذا ہمارے درمیان دوستی کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اور میں ان کو دوست ہی مانتی ہوں، mentor بھی نہیں مانتی۔ میری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ اردو ادب کے حوالے سے امریکہ میں مجھے سی ایم نعیم اور فرانسز پرٹچٹ کی صورت میں دو بہت ہی شفیق اور مہربان mentors ملے، اور یہ اشخاص میرے دل و دماغ میں استاد کے منصب پر فائز ہیں۔ جب تک میں عمر میمن صاحب سے ملی ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہو چکی تھی، اور میرا خیال ہے کہ ان کا مزاج mentorship کے مرحلے سے کافی دور جا چکا تھا۔ پڑھانے، سکھانے، اصلاح دینے کے سال گزر چکے تھے۔ اب وہ مکمل طور پر اپنے ذاتی شوق سے متعلق پڑھائی لکھائی اور ترجمے کے کاموں سے لطف حاصل کر رہے تھے۔ اور ہمارے درمیان جو رشتہ قائم ہوا وہ بنیادی طور پر گپ شپ کا رشتہ تھا۔ ادھر ادھر کے ہزار قسم کے موضوعات پر گھنٹوں گھنٹوں گفتگو کا رشتہ تھا۔ لہذا حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے تقریباً نصف صدی بڑے ہونگے، میں پھر بھی ان کو دوست کہنے کی جسارت کر رہی ہوں۔
محمد عمر میمن سے پہلی بار ملاقات کا معاملہ کچھ یوں ہوا کہ جنوبی ایشیا کی بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے امریکی ریاست وسکانسن کے شہر میڈسن میں، جہاں میمن صاحب رہتے تھے۔ شام کے وقت، میں کانفرنس والے ہوٹل میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کر رہی تھی اور کوئی ارادہ بھی نہیں تھا کہ نیچے آ کر کسی سے بات چیت کی جائے۔ ہمارے دوست مؤرخ و ماہر معاشیات اکبر زیدی صاحب کا ای میل آیا کہ عمر میمن صاحب یہاں ہوٹل میں موجود ہیں اور بات چیت کے موڈ میں ہیں۔ اگر مجھے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر بات کرنے میں دلچسپی ہو تو میں نیچے آ جاؤں۔ لہذا میں نیچے گئی اور ہم دو تین لوگوں کی میمن صاحب کے ساتھ باتیں شروع ہوئیں۔ ان کے ساتھ کھانے پر بھی بیٹھ گئے اور پھر شام سات بجے سے لے کر رات دیر تک گفتگو جاری رہی ہماری، یہاں تک کہ ہوٹل کی لابی خالی اور سنسان ہو چکی تھی۔ اتنی خوش گوار گفتگو رہی کہ پتہ ہی نہیں چلا ہمیں بھی اور انہیں بھی کہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا۔ اگلے دن وہ دوبارہ آ کے بہت گرم جوشی کے ساتھ ہوٹل کی لابی میں ملے۔ بڑے پرجوش (excited) تھے۔ زیدی صاحب سے کہتے تھے: مجھے لگا ہماری ملاقات ایک خواب میں ہوئی ہے۔ رات گپ شپ کے بعد وہ دیر سے اپنے گھر پہنچے تھے۔ صبح اٹھ کر انہوں نے ای میل میں ہمیں یہ شعر لکھ کر بھیجا:
اے ذوق کسی ہمدمِ دیرینہ کا ملنا
بہتر ہے ملاقاتِ مسیحا و خضر سے
تو بہت ہی سینٹمنٹل (sentimental) اور اموشنل (emotional) اور شفقت سے بھرپور وہ خط تھا۔ مزید یہ لکھا:
عمر میمن :
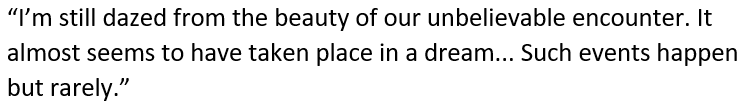
زہرا صابری: اس قدر شفقت ایسے لوگوں کے لئے جن کا شعبۂ تحقیق بھی ان سے نسبتاً جدا تھا اور جن سے وہ پہلی بار ملے تھے، اور چھوٹے بڑے کے تکلف سے آزاد ہو کر اس طرح جوش و خروش اور دوستانہ جذبات کا اظہار کرنا – ہم لوگ ان کے خلوص سے بہت متاثر ہوئے۔ (We were very touched)۔
ان کے مزاج میں کافی شفافیت (transparentness) تھی ۔ کوئی تصنع، بناوٹ، تکلف نہیں تھا۔ بہت صاف گو اور روراست (open) آدمی تھے اور دوسروں میں بھی شفافیت، صاف گوئی اور دیانت داری پسند کرتے تھے۔ ایک غیر پوشیدہ جوش (unconcealed excitement) اور ایک غیر پوشیدہ سرور کی کیفیت (unconcealed enjoyment) ان کے مزاج کی خصوصیت تھی۔ جب وہ کسی ایسے لفظ، خیال، یا تصور کے بارے میں بات کرتے جو ان کو دلچسپ لگتا تو آپ ان کی آواز میں ان کے لطف اور گرویدگی (fascination) کو محسوس کر سکتے تھے اور اس کا آپ پر بھی اثر ہوتا تھا۔ اس کو آپ انگریزی میں infectious excitement ( ہمہ گیر جوش و خروش) کہتے ہیں۔ ایک لحاظ سے وہ اس قسم کا جوش و خروش (excitement) تھا جو کسی کم عمر طالب علم میں نظر آتا ہے جو نئی نئی چیزیں پڑھ کر خوش ہوتا ہے۔ اور جس کا ذہن، خیالات اور curiosity (سیکھنے کا اشتیاق) ابھی تشکیل پا رہے ہوتے ہیں۔ ان میں علم حاصل کرنے کی لگن، نئی نئی چیزیں جاننے کا شوق، مصوری، موسیقی، خیالات، اور لفظوں کے حسن کا احساس، اور ایک احساسِ تحیر (sense of wonder) تھا جو ان کی گفتگو میں آخر تک جھلکتا تھا۔ آخر تک ایک intellectual passion اور youthfulness رہی ان کے انداز میں حالانکہ وہ زندگی میں بہت کچھ دیکھ چکے تھے، اپنے اکیڈمک کیریئر کے آخری سرے پر پہنچ چکے تھے اور کالج کی نوکری سے کب کے ریٹائر ہو چکے تھے۔ پھر بھی وہ بیزار نہیں لگتے تھے، excited اور پر جوش ہی لگتے تھے۔
میڈسن کی کانفرنس میں اس یادگار ملاقات کے بعد میری ان سے ایک بار ہی پھر ملاقات ہو پائی۔ وہ تھی اُسی سال سردی کی چھٹیوں میں کراچی میں۔ منصوبے بنتے رہے پاکستان یا امریکہ میں دوبارہ ملنے کے لیکن پھر کبھی ملاقات کی کوئی صورت نہیں بن پائی۔ لیکن ہم نے ایک دوسرے کو خط بہت لکھے ای میل کے ذریعے۔ تقریباً سو خط آئے گئے ہوں گے ان چار سالوں میں اور فون پہ بھی اکثر ان سے بات ہوتی تھی اور اسکائپ (Skype) پہ اکثر ویڈیو کال ہوتی تھی۔ بہت مزہ آتا تھا ان سے بات کر کے سینکڑوں موضوعات کے بارے میں۔ کہتے تھے: دیکھئے، میرا ذہن کیسے کودتا ہے ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف ۔ اور میرا خیال ہے شاید اسی لئے وہ کانفرنسوں میں مقالے پڑھنا بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے اور اپنی زندگی میں monograph بھی انہوں نے کم ہی لکھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ بس سوچا کریں اور آزاد رہیں، اور اپنے آپ کو ایک ہی موضوع میں کافی دیر قید کرنا انہیں شاید بوجھ سا لگتا تھا۔ بے تکلف اور غیر رسمی سی گفتگو کرنا ان کے مزاج کے زیادہ مطابق تھا۔ اور واقعی، ان سے بات کر کے احساس ہوتا تھا کہ ان کا ذہن واقعی پھدکتا ہے ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف، اور ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف۔ سننے والے کو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ان کی باتیں ہی اتنی دلچسپ ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی پاکستان اور دیگر ممالک میں اردو فیسٹولز اور کانفرنسوں کی صورت حال زیر بحث آتی تھی، کبھی علمی تحقیقات، کبھی اِن نکات پر بات ہوتی تھی کہ اردو میں کسی لفظ کی املاء کبھی ایسے کیوں ہوتی ہے اور کبھی ویسے کیوں۔ ایک کبھی نہ ختم ہونے والی گفتگو تھی، چاہے وہ اسپین میں مسلمانوں کی تاریخ پر ہو، چاہے جدید عربی ادب یا اردو ادب یا انگریزی ادب سے متعلق ہو۔ وہ خوش گفتار تھے، ان کی مسرت بخش اور عالمانہ گفتگو سننے والے کو بھی مزید سیکھنے، مطالعہ کرنے اور تحقیق کرنے کا جوش دلاتی تھی۔ ادبی اور علمی دنیا سے وابستہ افراد کی چھوٹی چھوٹی غیر ضروری باتیں اور اس دنیا میں اکثر نظر آنے والی حسد اور خود نمائی اور بناوٹ اور تصنع ان سے بات چیت کے لمحات میں بڑی ہی دور اور بڑی ہی اجنبی سی معلوم ہوتی تھیں۔ اور خوشی ہوتی تھی کہ اب ہماری توجہ ضروری چیزوں پر ہے جو ہیں علم و ادب و تصورات و خیالات اور ان پر بڑی ہی احتیاط اور ایمانداری کے ساتھ گفتگو۔ بس کوئی موضوع سامنے آتا اور ایک دلچسپ بحث چھڑ جاتی چاہے روبرو ہو یا فون پر ہو یا بذریعہ خط (یعنی ای میل) ہو۔ ان کی ای میلز سے کچھ اقتباسات پیش ہیں:
عمر میمن:
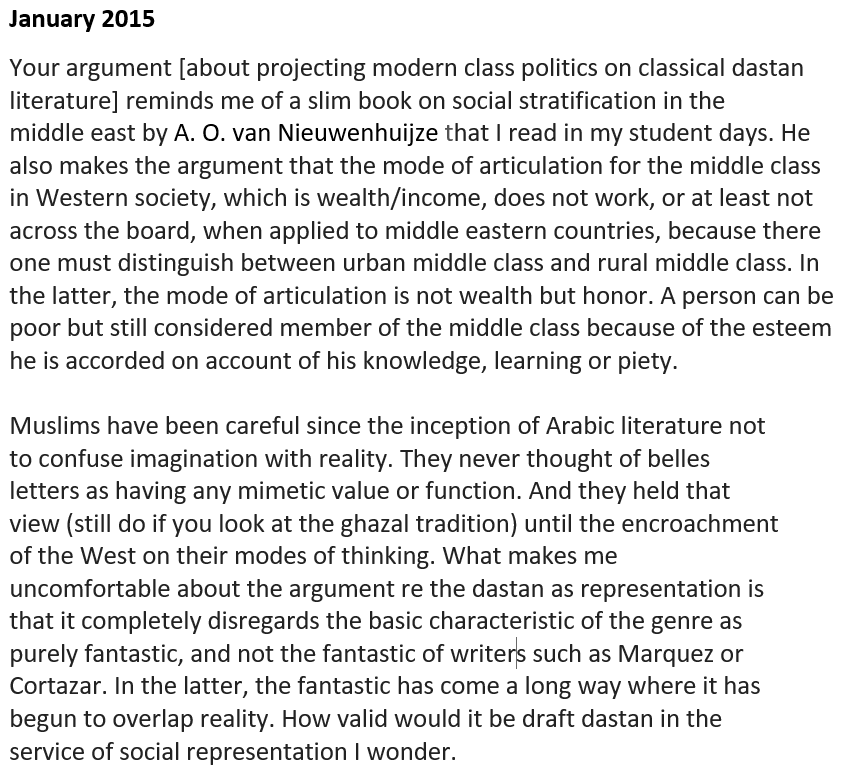
زہرا صابری:
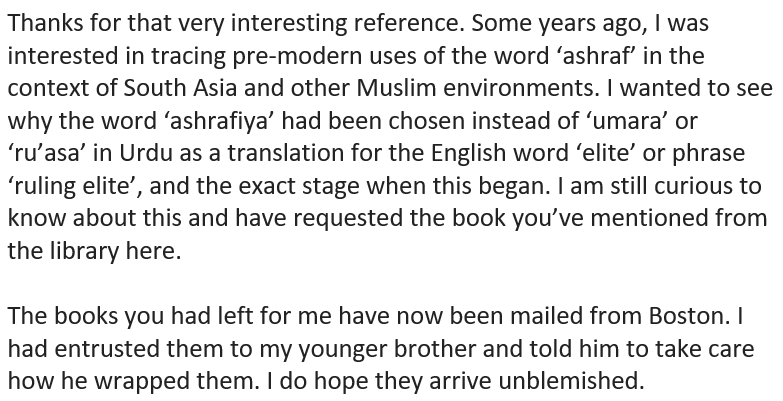
عمر میمن:
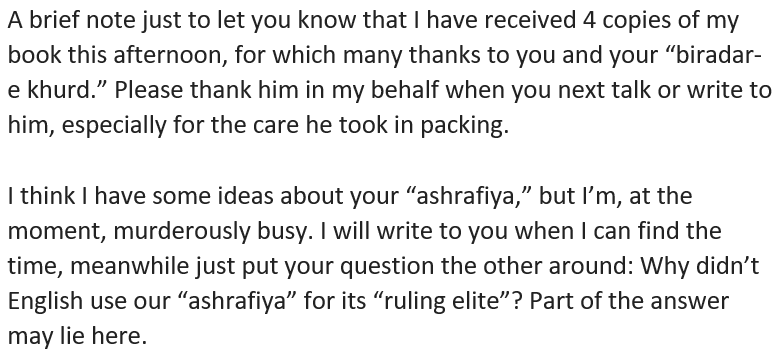
زہرا صابری:
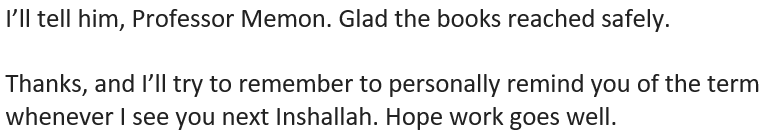
عمر میمن:
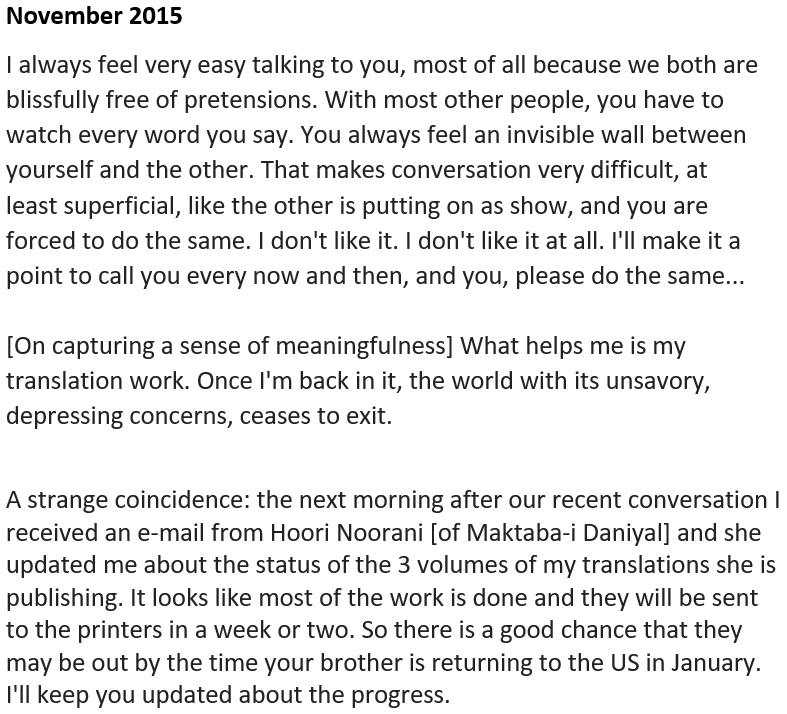
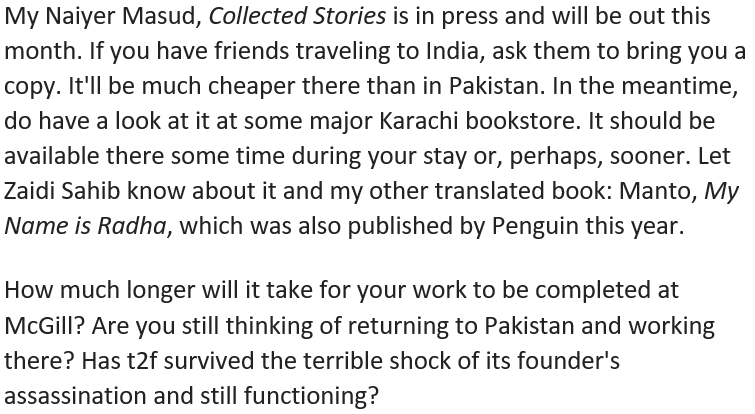
زہرا صابری:
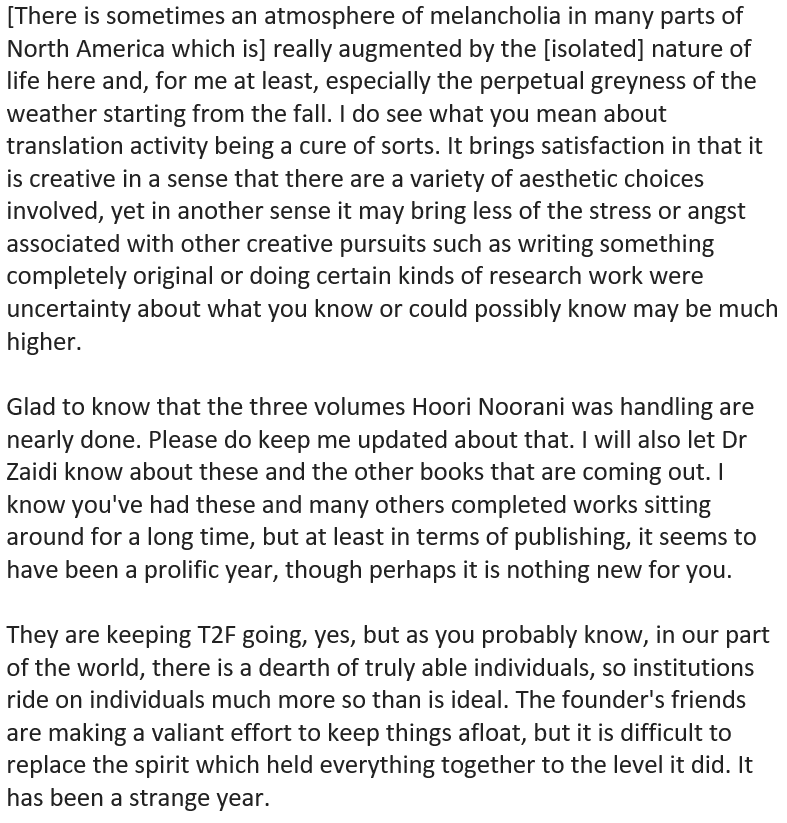
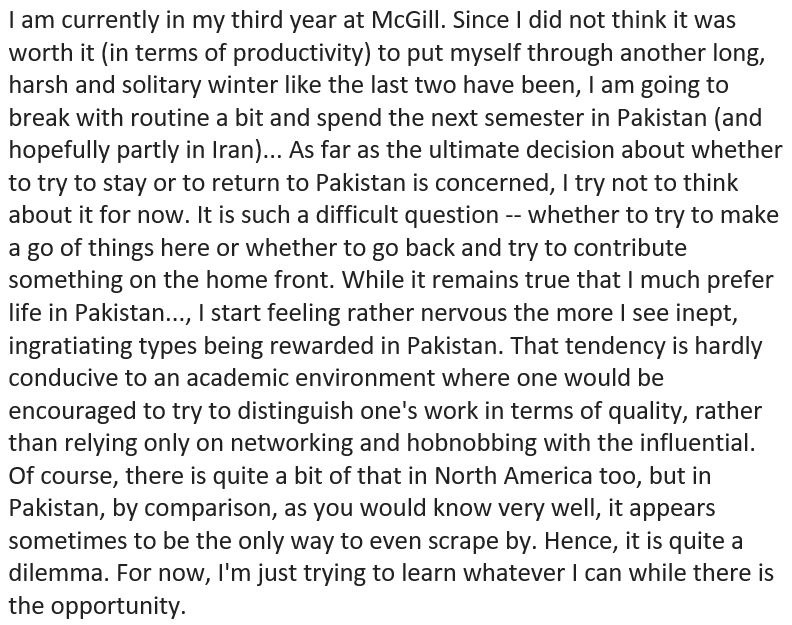
عمر میمن:
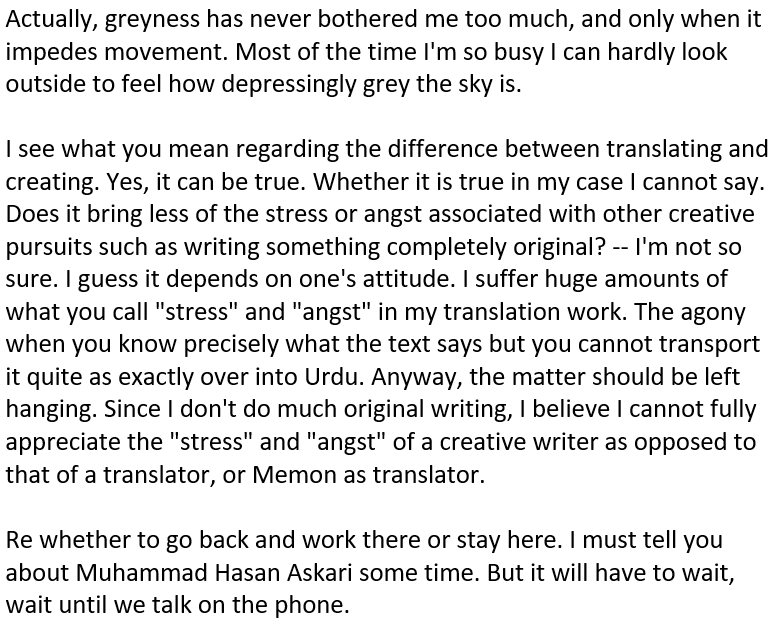
زہرا صابری:
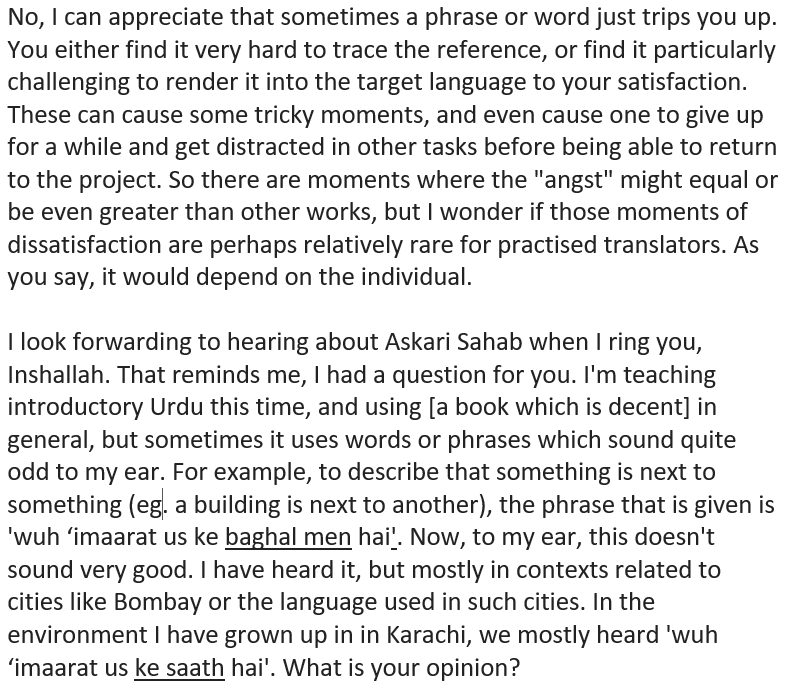
عمر میمن :
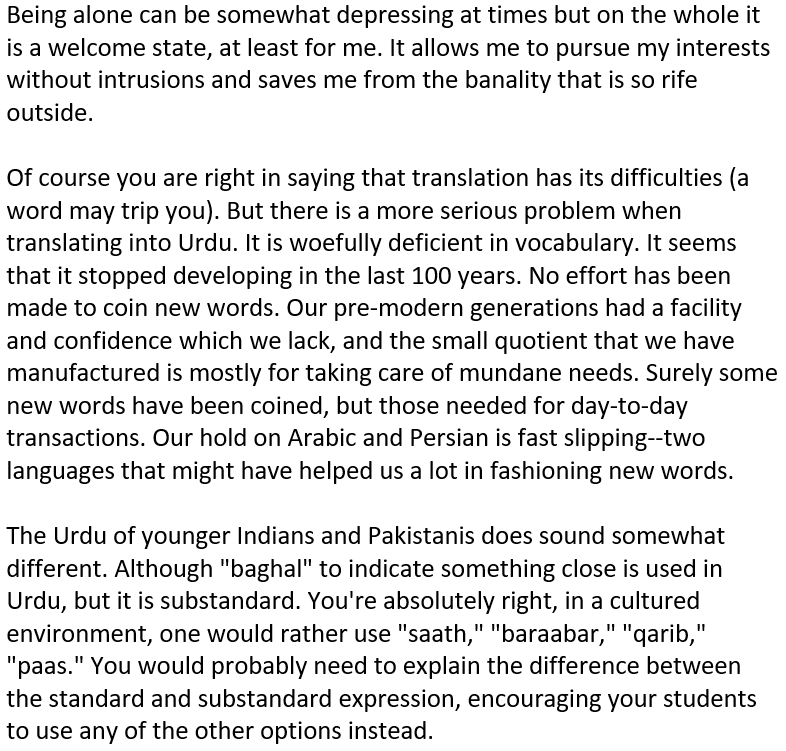
زہرا صابری:
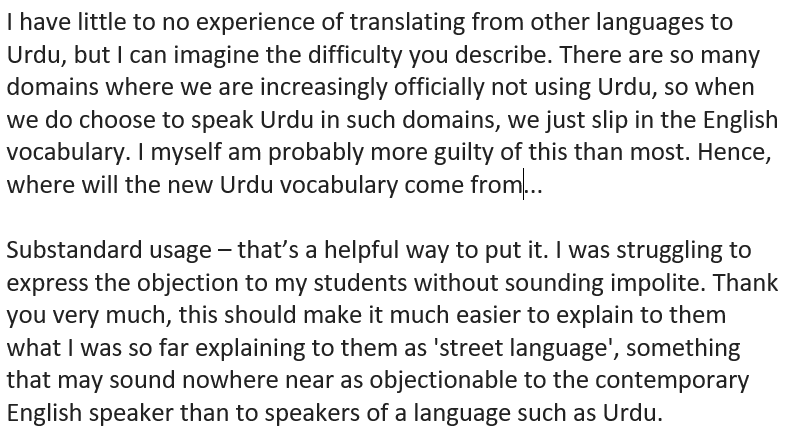
عمر میمن :
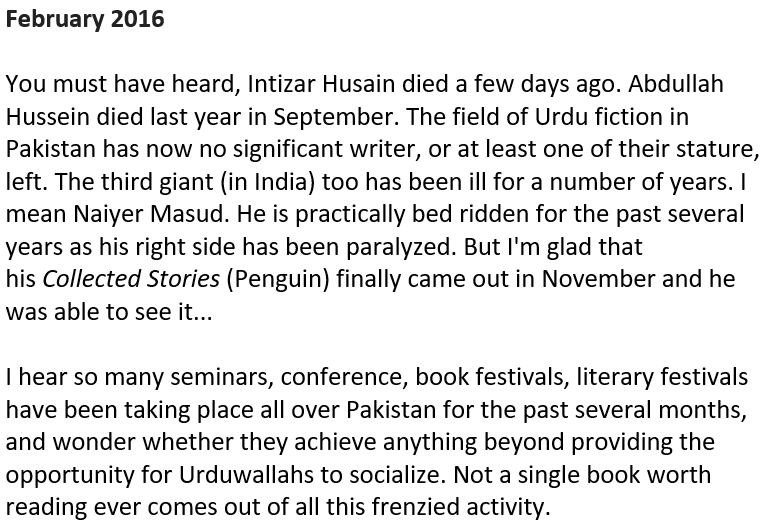
عمر میمن:
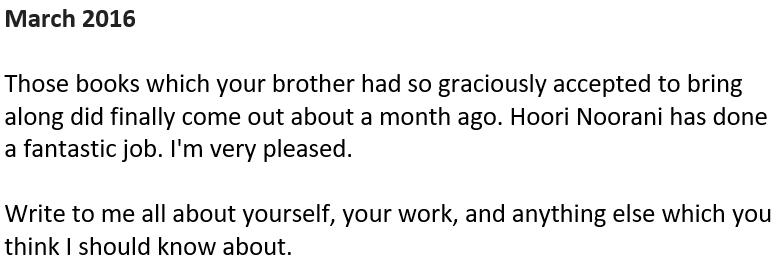
عمر میمن:
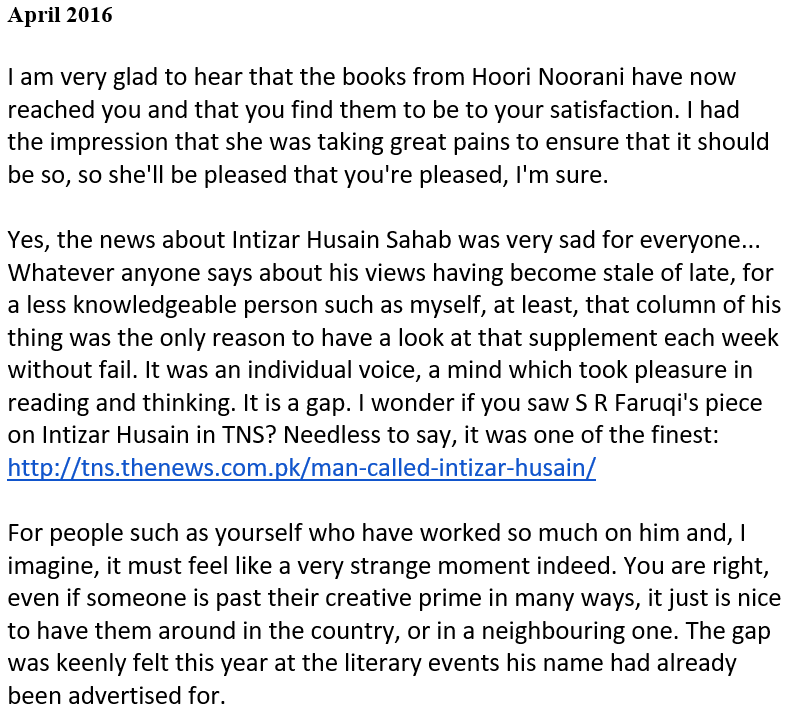
عمر میمن:
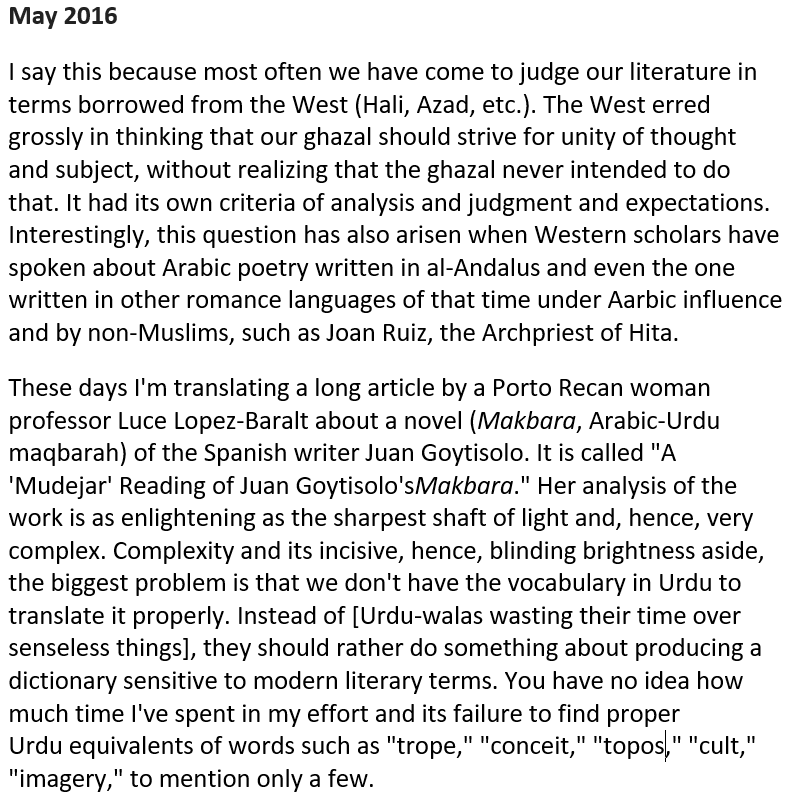
عمر میمن:
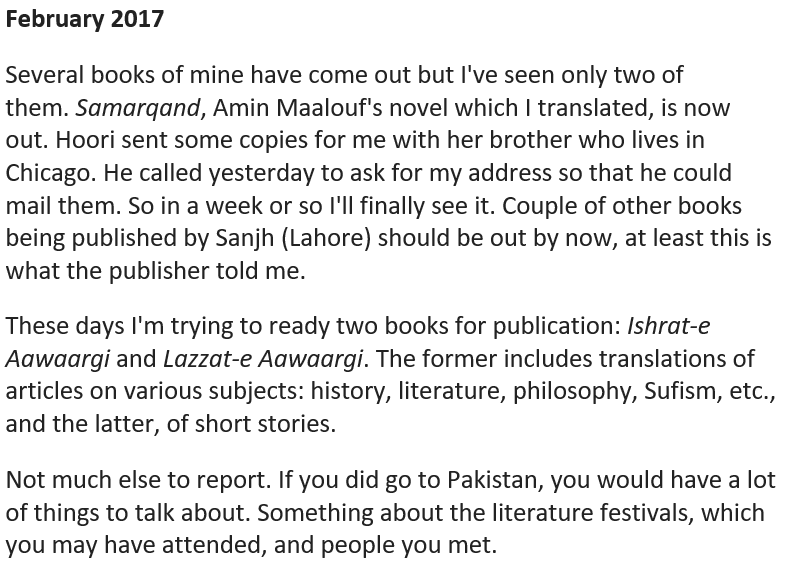
زہرا صابری:
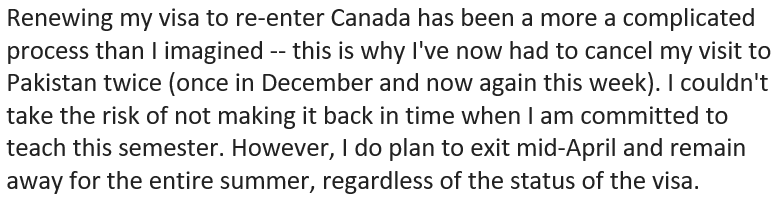
عمر میمن:
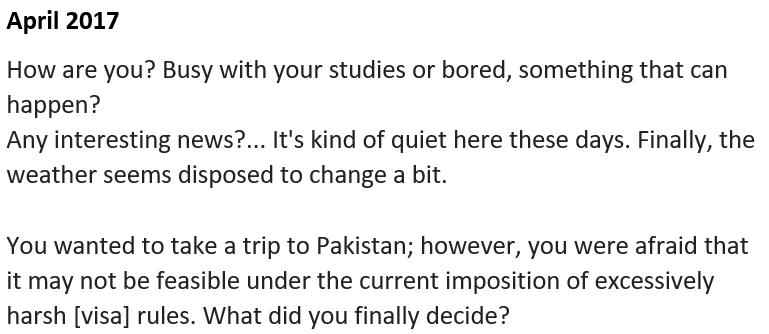
زہرا صابری:
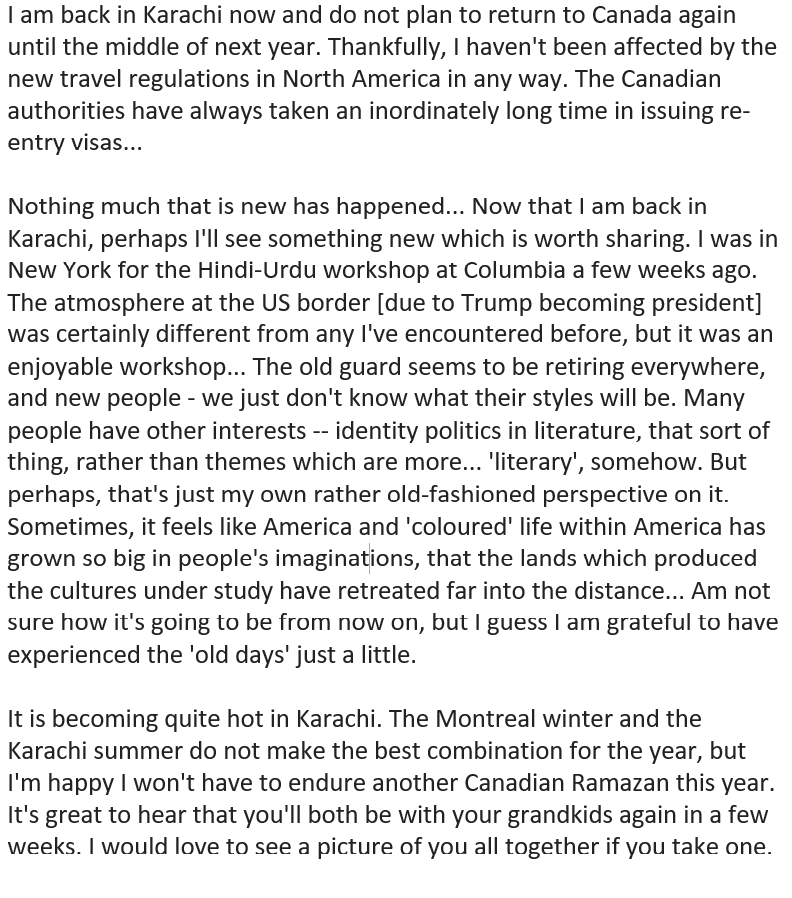
زہرا صابری:
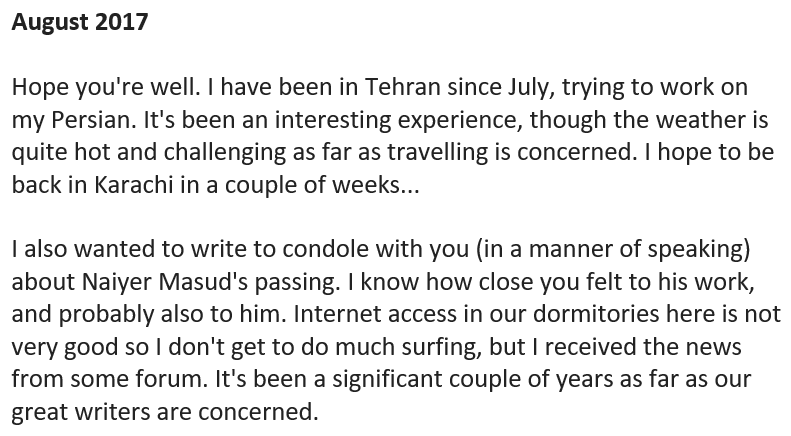
زہرا صابری: غرض یہ کہ بات چیت کے بے شمار موضوعات تھے۔ میرے لئے یہ ایک بہت خاص دوستی اس لئے بھی تھی کہ حالانکہ بہت سے دیسی لوگ امریکہ میں پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے شہر سے کوئی اس طرح کا شخص نہیں جس کی اسلامک اسٹڈیز میں بھی ٹریننگ ہو اور اردو میں بھی ہو۔ لہذا ایک اجنبیت سی محسوس ہوتی تھی وہاں پر زیادہ تر ایکیڈیمکس (academics) کے ساتھ تبادلۂ خیال کرتے ہوئے۔ لیکن میمن صاحب مجھے لگتا تھا کہ میرے شہر کے واحد آدمی ہیں جو شہر کے حالات سے بھی خوب واقف ہیں اور جن کی اُسی قسم کی ٹریننگ ہے جس طرح کی میں خواہش رکھتی ہوں اپنے لئے۔ ظاہر ہے ایسی خواہش کی تکمیل کہاں ممکن ہو سکتی تھی، لیکن خواہش تو آدمی رکھ سکتا ہے۔ وہ بھی امریکہ فلبرائیٹ کے وظیفہ کے ذریعہ تعلیم حاصل کرنے گئے تھے اور ہم بھی گئے تھے۔ پچھلے دنوں ۹/۱۱ کے بعد تو بہت ساری فلبرائیٹ (scholarships) تعلیمی وظائف ملے ہیں پاکستانی طالب علموں کو، اور ہمارے ساتھ کے بہت سارے لوگ ہیں جو اس وظیفہ کے ذریعہ امریکہ جا پائے اعلی تعلیم کی خاطر۔ میمن صاحب لیکن ۱۹۶۴ء میں گئے تھے اور اب جو ہم زیادہ تر لوگ امریکہ جا رہے ہیں وہ اپنے ساتھ پہلے سے اس درجے کی پڑھائی اور علمی صلاحیتیں یہاں سے نہیں لے کر جا رہے جو عمر میمن صاحب لے کر گئے تھے۔ جس علمی گھرانے سے ان کا تعلق تھا اور عربی، فارسی اور اردو کی جو تعلیم انہوں نے امریکہ جانے سے پہلے پاکستان میں حاصل کی تھی اور جو ان کے کام کے لئے وہاں پہنچ کر اثاثہ بنی تھی، وہ ہمارے موجودہ تعلیمی نظام میں ہمارے لئے شاید اب ممکن ہی نہیں رہی جس کے ذریعہ ہم اپنے علم میں ویسی وسعت اور اپنے کام میں ویسا نکھار پیدا کر سکیں۔ ایک انہوں نے مجھے خط لکھا تھا جس میں انہوں نے چلتے چلتے چند ایک باتیں کہی تھیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں علم کی عالمی دنیا میں کیسے کیسے اعلی درجے کے محققین سے درس حاصل کرنے کا اتفاق ہوا۔
عمر میمن :
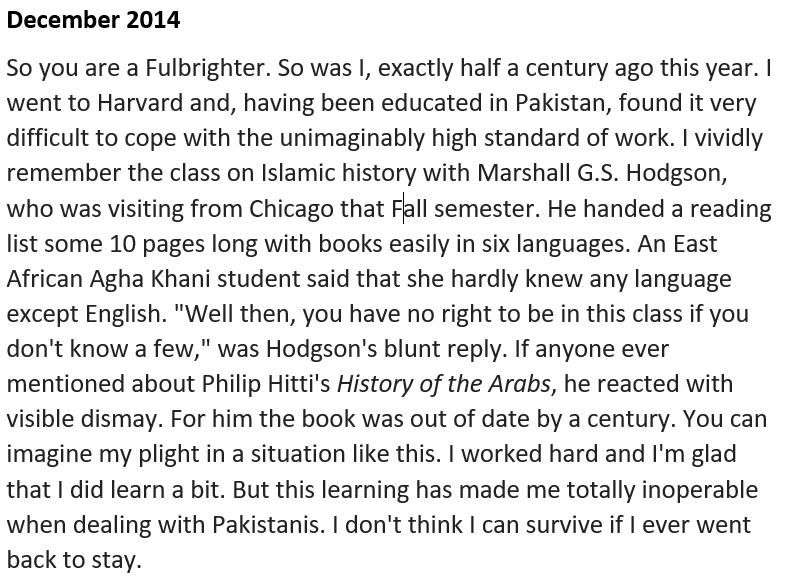
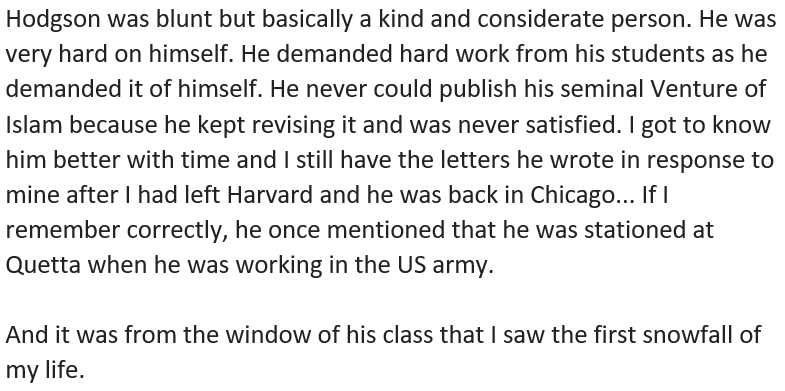
زہرا صابری: اسلامی تاریخ پر انگریزی میں شاید مارشل ہوڈجسن کی کتاب Venture of Islam کے بعد اتنی بڑی کتاب کوئی نہیں آئی ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کے لئے وہ بہت ہی اہم کتاب ہے۔ واضح ہوتا کہ کتنی مشکل کلاس ہوگی جس میں اتنی ساری زبانوں میں کتابیں پڑھنا ضروری تھیں۔ عمر میمن صاحب تو عربی، فارسی، اردو یہ تینوں زبانیں جانتے تھے۔ اور مجھے نہیں پتہ کہ یورپی زبانیں وہ کون کون سی جانتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ شاید نہیں، یورپی زبان انہوں نے کوئی شاید بہت زیادہ نہیں سیکھی تھی۔ خیر، اس قسم کے واقعات کبھی کبھار ان سے سننے کو ملتے تھے باتوں باتوں میں اور پتہ چلتا تھا کہ زمانۂ طالب علمی میں کس قسم کے دلچسپ علمی تجربوں سے گزرے ہیں اور کیا کیا اہم معلومات اکٹھی کیں ہیں۔ مجھے افسوس رہا کہ اتنے بڑے اسکالر تھے وہ جو کراچی سے اور پاکستان سے نکلے تھے، لوگوں کو کتنا کم یہاں ادبی فیسٹولز اور کانفرنسوں میں انہیں سننے کا اور ان کے علم سے استفادہ کرنے کا براہ راست موقع ملا۔ ایک لحاظ سے ان کے پاس جو علم تھا وہ یہاں ہمارے ماحول میں منتقل کرنا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ لوگوں تک تو ہم پہنچ بھی جائیں لیکن گھسی پٹی سوچ رکھنے والے منتظمین پر کیسے جتائیں کہ بہتر معیار کی تحقیات کی اہمیت ہونی چاہئے۔ اور باہر جا کر اتنا کچھ سیکھ کر کبھی مشکل بھی ہو جاتا ہے دوبارہ اس سطح پر آ کر سامعین سے بات کرنا جس ملک میں علمی اور تحقیقی ماحول بد سے بدتر ہوا چلا جا رہا ہو۔ جب میں پہلی دفعہ ان سے ملی تھی تو میں نے ذرا شکایت کے لہجے میں ان سے کہا تھا کہ اگر آپ کے معیار کے استاد میڈسن کے بجائے کراچی میں پڑھا رہے ہوتے تو اس شعبے میں کئی زیادہ محقق پیدا کر سکتے تھے کہ جتنے آپ امریکہ میں رہ کر کر پائے۔ اس بات سے ایک دم سے ان کے دل کو ٹھیس سے لگی اور کہنے لگے کہ ان کی خواہش تو تھی لیکن [کم از کم اُس وقت] وہ تعلیمی نظام پاکستان میں اس صورت میں نہیں موجود تھا جس میں وہ اپنی حاصل کردہ معلومات قاعدے سے منتقل کر سکیں۔
وہ جب کراچی آئے تھے تو ہم نے یہاں T2F میں ایک نشست رکھی ان کے لئے ۔ انہوں نے مجھے ایک مقالہ بھیجا تھا اور مجھے لگا کہ اس کے کئی نکات ایسے ہیں جن کو لوگوں تک پہنچانے میں کافی فائدہ ممکن ہے۔ لیکن وہ انگریزی کا مقالہ جہاں مجھے conceptually بہت ہی عمدہ اور اعلی پائے کا لگا، وہیں مجھے یہ خدشہ تھا کہ شاید یہاں لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہو۔ کیونکہ یہاں T2F جیسی محفلوں اور کئی ادبی حلقوں میں بھی باتیں ہوتی ہیں، وہ conceptually اس پائے کی نہیں ہوتیں۔ بلکہ کسی نے مجھے T2F اور کراچی کے ادبی میلوں کے بارے میں یہ تبصرہ پیش کیا تھا کہ یہاں اکثر لوگ جو آتے ہیں، ان کے ذہن میں پہلے سے جو خیالات ہیں، وہ محض ان پر تصدیق کی مہر لگوانے آتے ہیں۔ ان کو عادت نہیں ہوتی کہ کسی چیز کے بارے میں کسی نئی طرح سے سوچنے پر آمادہ کیا جائے ان کو۔ ان کو عادت نہیں ہوتی کہ عقیدۂ عمومی ( conventional wisdom) کے بر عکس کوئی بات کی جائے ان سے۔ اور میمن صاحب کی تو بہت سی باتیں اور آرا عقیدۂ عمومی (conventional wisdom) کے خلاف جاتی تھیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ انگریزی کے بجائے اردو میں گفتگو کیجئے کیونکہ لوگوں کو شاید سمجھ بھی زیادہ آ جائے اور ان کو اچھی اردو سننے کا موقع بھی مل پائے۔ بہت عمدہ گفتگو رہی، انہوں نے بہت ہی فکر انگیز خیالات پیش کئے۔ لیکن جب سوالات کا وقت آیا تو مجھے اس بات کا ذرا افسوس رہا کہ صاف واضح تھا کہ سامعین کو پوری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ واضح ہوا کہ زبان سے فرق پڑتا ہے لیکن اتنا بھی نہیں۔ لوگوں کو افکار اور بحث کے زیادہ پیچیدہ طرز کی باتیں سننے کی اب عادت ہی نہیں رہی۔ تیس چالیس سال پہلے شاید ہوتی لیکن اب نہیں رہی۔ گھسی پٹی اور عامیانہ سی باتیں ہضم کرنے کی زیادہ عادت ہے لوگوں کو۔ پھر بھی لوگ محظوظ ہوئے، ان کے لئے گفتگو کا یہ طرز نسبتاً نیا تھا، پوری طرح باتیں سمجھ نہ بھی آئیں لیکن کچھ نہ کچھ نیا ذہن نشیں ضرور ہوا۔
ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا وہاں T2F کے سیشن کے بعد، جو میمن صاحب کی شخصیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اچھا، آپ اردو پڑھاتے ہیں امریکہ میں؟ تو امریکہ میں کس قسم کے لوگ اردو پڑھتے ہیں؟ چینی باشندے، انگریز، یا کوئی اور لوگ؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہر قسم کے لوگ وہاں اردو پڑھنے آتے ہیں کلاسوں میں۔ اردو ایک اہم زبان ہے دنیا کی۔ تو وہ جو صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا، پتا ہے ایک امریکی آیا تھا پچھلے سال پاکستان اور وہ اردو میں بات کر رہا تھا۔ وہ اردو بول رہا تھا۔ تو میمن صاحب نے اُن صاحب سے کہا ’تو آپ بہت خوش ہو گئے ہوں گے؟‘ وہ آدمی (میمن صاحب کے لہجے کی وجہ سے) تھوڑا چونک سا گیا کہ ’جی‘؟ کہنے لگے کہ آپ اپنی ذہنیت پر غور کیجئے۔ میں بھی تو انگریزی بول لیتا ہوں۔ اس میں خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی انگریز اردو بول رہا ہے۔ ان کو اس زبان میں اور بھی زیادہ مہارت پیدا کرنی چاہئے۔ پھر ہنس کر بولے اس آدمی سے، ’آپ برا نہ منائیں۔ I’m not such a bad guy, you know ۔ میں صرف اس چیز کی نشان دہی کر رہا تھا کہ ہمیں ایسی غلامانہ سوچ نہیں رکھنی چاہئے کہ ہماری زبان کوئی سیکھے تو ہمیں تعجب ہو اور ہم اس بات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیں۔‘
ان کو پریشانی ہوتی تھی جب آکسفرڈ پاکستان جیسے پبلشرز ہماری زبانوں کے معاملے میں احتیاط نہیں برتتے تھے بلکہ جانے مانے مصنفین لا پرواہی سے دیسی زبانوں سے متعلق کتابیں چھاپتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے ایک خط میں لکھا:
عمر میمن :
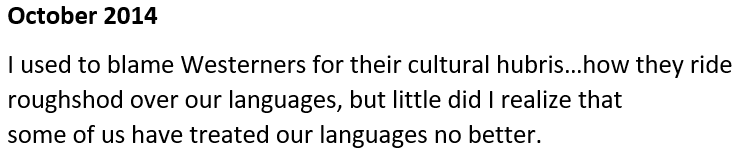
زہرا صابری: میرے اور ان کے خیالات بہت ملتے تھے پاکستان کے انگریزی میں فکشن لکھنے والوں کے بارے میں۔ انہیں بھی لگتا تھا کہ یہاں سے پچھلے دو تین دہائیوں میں جو انگریزی ادب لکھا گیا ہو اور باہر کے ملکوں میں بہت مشہور و مقبول ہو رہا ہے، ادبی لحاظ سے اس کا معیار کچھ اتنا بھی خاص نہیں ہے اور یہ کہ یہ ادب کافی over-promoted ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے مجھے ایک بار لکھا:
عمر میمن :
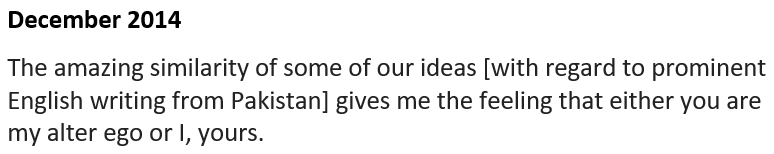
ظاہر ہے ایسی بات سے تو مجھ جیسے ادنی طالب علم کو خوشی اور اطمینان ہی محسوس ہونا تھا، چاہے یہ انہوں نے محض مروت اور حوصلہ افزائی کے جذبوں کے تحت کیوں نہ کہا ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ پاکستان میں جو مشہور اور معروف انگریزی ادب لکھا جا رہا ہے، اور جن کی بنا پر لکھنے والے اپنے گرد مقامی اور بین الاقوامی فیسٹیولز میں ہجوم اکٹھا کر رہے ہیں، ان سے تو بہتر کچھ بالکل ہی غیر معروف لکھنے والوں کی تصنیفات ہیں جو اردو اور دیگر زبانوں میں لکھی جا رہی ہیں۔ لیکن انگریزی کی ہمارے یہاں خصوصی حیثیت (privilege) ہی اس طرح کی ہے کہ اسے پاکستان کے کئی نمایاں فورمز پر زیادہ اہمیت ملتی تھی۔ انگریزی کے لکھنے والے ان سے آ آ کر ملا کرتے تھے، لیکن ان میں سے اکثر کی ذہنیت ان کو کافی عجیب لگتی تھی۔ وہ اس بات کو نوٹ کرتے تھے کہ یہ لوگ اکثر جتانا پسند کرتے ہیں کہ ان کا کسی گوری چمڑی والے سے کسی لحاظ سے کوئی خون کا رشتہ ہے، اور یہ لوگ باتوں باتوں میں ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہماری کوئی اطالوی نانی ہیں یا فرانسیسی چچی۔ ان کو یہ سب بالکل ہی غیر ضروری اور احمقانہ بات لگتی تھی، جس سے ایسے لوگوں کی غرب زدگی اور نسلی اعتبار سے احساس کمتری کا ثبوت ملتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو امریکہ میں اب میمن صاحب کے اپنے گھر کا ماحول یوں تھا کہ ان کی بیگم جاپانی ہیں اور ان کی ایک بہو اور پوتا اطالوی بولتے ہیں۔ لہذا ان کے گھر میں تو صرف وہی رہ گئے تھے جو اردو بولتے تھے اور باقی لوگ اطالوی، جاپانی اور انگریزی بولتے تھے۔ لیکن انہوں نے تو کبھی اس بات کا فخر سے ذکر نہیں کیا کہ ہمارا گھر ’بین الاقوامی‘ ہے اور ولایتی ثقافتوں سے نسلی تعلق رکھتا ہے۔ شاید اس وجہ سے کہ انہوں نے انگریزی علوم وغیرہ اپنے اندر بڑی گہرائی سے جذب کر لئے تھے۔ ان کے لئے یہ سب چیزیں نئی اور نایاب نہیں رہیں تھیں ہمارے یہاں ان دیسی لوگوں کے برعکس جو اوروں کو مرعوب کرنے کی خاطر یورپین ادیبوں اور فلسفہ دانوں کے ناموں کا اپنی گفتگو میں وقت بے وقت ذکر کرتے رہتے ہیں۔
ان کی شخصیت کے بارے میں تو کافی حد تک بات ہو چکی، اب آخر میں ان کے ادبی نظریوں کے بارے میں کچھ باتیں۔ ترقی پسند تحریک نے اردو ادب میں ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے آزادی سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی۔ تمام عقل مند لوگوں کی طرح میمن صاحب کو بھی ان کی کئی باتیں بالکل پسند نہیں تھیں۔ انہوں نے ایک مقالے میں لکھا:
عمر میمن:
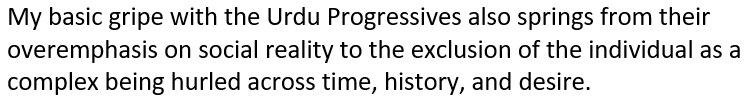
زہرا صابری: اس کے بر عکس ایک اور جگہ انہوں نے لکھا کہ اگر نیر مسعود جیسے فکشن نگاروں کو آپ نے پڑھنا ہے تو آپ ان کی تحریروں میں کوئی معنی نہیں تلاش کریں بلکہ اسالیبِ وجود اور صورتیں (modes of being) تلاش کریں۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت محبت کرتے تھے اردو سے۔ حالانکہ اسلامک سٹڈیز میں ان کی ٹریننگ تھی لیکن پھر وقت کے ساتھ انہوں نے اردو پر زیادہ کام کرنا شروع کردیا، شاید اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے گھریلو ماحول میں ایک طرح سے اردو سے لا تعلق ہو رہے تھے، چناچہ شاید ان کو لگتا ہوکہ اردو پر کام ان کے لئے گھر کے اندر ہی ایک مزید گھر کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ شروع میں ۱۹۴۰ء کے لگ بھگ جو اردو میں کام ہوا، وہ اس زمانے کے جدید فارسی اور عربی ادب سے بہت بہتر تھا، بہت آگے تھا ۔ لیکن تقریباً۱۹۵۰ء کے بعد کچھ معاملہ ایسا پیدا ہوا کہ اردو کے ادیب پیچھے رہ گئے۔ چونکہ وہ دنیا بھر کے فکشن نگاروں کی تحریریں پڑھتے تھے تو وہ عالمی پیرائے میں سب کا موازنہ کر پاتے تھے ۔ ایک جگہ لکھا:
عمر میمن:
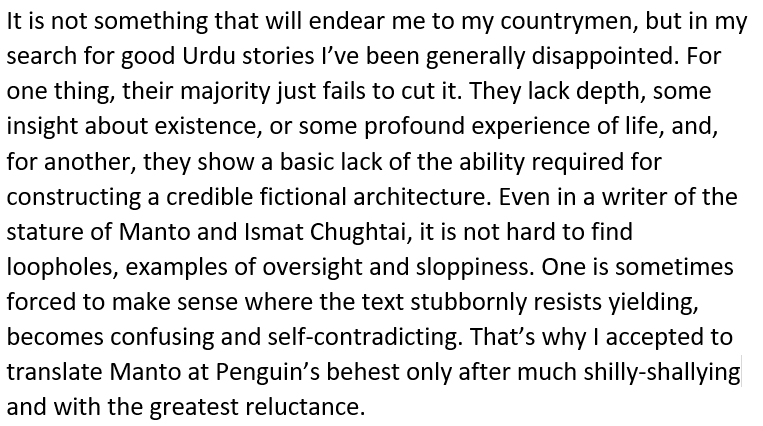
زہرا صابری : جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ انڈیا میں اردو دھیرے دھیرے تقریبا ختم ہو جائے گی۔ وہ اس بات کو کافی دو ٹوک انداز میں کہہ دیتے تھے۔ میرے نزدیک ان کے اسی دو ٹوک انداز کی ایک منفرد اہمیت بھی تھی امریکہ کے علمی حلقوں میں۔ وہاں کی جنوبی ایشیا کے تدریسی حلقے اکثر اوقات ظاہر ہے سیاست کے زیر اثر بھی آتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہاں رہ کر کچھ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو سننے میں خوب صورت تو لگتی ہیں لیکن زمینی حقائق سے بہت دور ہوتی ہیں اور عمل میں لائی ہی نہیں جا سکتیں۔ جیسا کہ وہاں کئی لوگوں کے نزدیک ہندی اور اردو دونوں ہی کج روی کی مثالیں ہیں، اصل زبان تو ’ہندوستانی‘ ہے جو ایک بہت خوب صورت تصور ہے اور گاندھی جی نے بھی تاکید کی ہے کہ ہندی اور اردو کے بجائے ایک بیچ کی زبان (ہندوستانی) کو فروغ دینا چاہئے۔ لیکن زبانیں امنگوں کے لحاظ سے کہاں چلتی ہیں؟ ان کی تو اپنی ہی منطق ہوتی ہے۔ میمن صاحب میں ثقافتی تعصب نہیں تھا لیکن وہ جو بات انہیں صحیح لگتی تھی، اسے کہنے سے کتراتے بھی نہیں تھے، چاہے پھر اگلا اس کا جو بھی مطلب نکالے۔ ان کا نظریہ تھا کہ ان سب مباحث میں الجھنے کے بجائے اِن زبانوں کی صحت کے لئے عملی طور پر کچھ کرنا چاہئے۔ ایک خط میں مجھے لکھا:
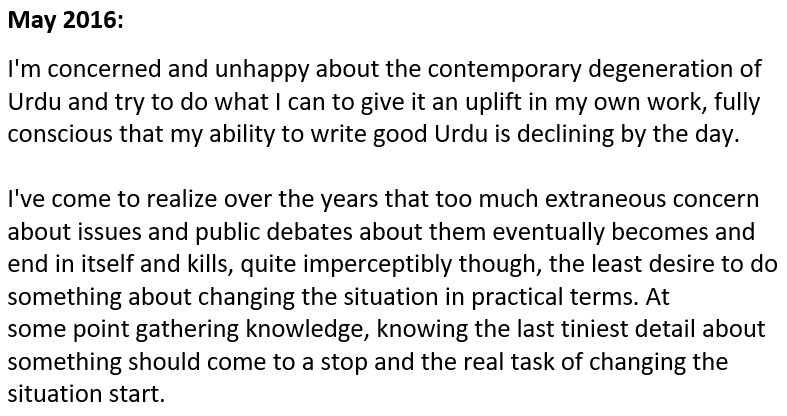
زہرا صابری: ایک جو وجہ تھی ان کے لئے تراجم کرنے کی، وہ نظریاتی اور سیاسی بھی تھی۔ عرب اسرائیلی جنگ کے دوران فلسطینیوں کے جو حالات امریکہ میں بیٹھ کر وہ دیکھ رہے تھے، اس کا ان پر کچھ خاص اثر تھا، ان کو کچھ خاص درد تھا۔ کیونکہ ان کا عربی کا براہ راست بھی بہت مطالعہ تھا، گھر میں ان کے والد علامہ عبد العزیز میمن کے عربی ادب کے اتنے عظیم عالم ہونے کی وجہ سے عربی کا ایک خاص ماحول تھا، ان کے والد بہت سے عرب ممالک بھی پھر چکے تھے اور وہاں ان کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ لہذا میمن صاحب کو اس خطہ کی سیاست اور اس کی ثقافت کے بارے میں کچھ اور زیادہ بھی خبر تھی جو عام طور پر دیسی لوگوں کو نہیں ہوتی ۔ بہت احساس رکھتے تھے اس خطے کی صورت حال کا۔ بہت فخر سے مجھے بتاتے تھے کہ ان کی بیگم امریکہ میں فلسطینیوں کے حقوق کی مہموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ اردو سے انگریزی میں تراجم انہوں نے اس لئے بھی شروع کئے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ مغرب میں عوام کو ایک بہت ہی محدود جھلک دیکھنے کو ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی زندگیوں کے لا تعداد پہلوؤں سے بے خبر رہتے ہیں، اور ان کے ذہن میں مسلمانوں کا ایک بہت stereotypical view رہ جاتا ہے۔ لہذا ہمارے ادب کے کچھ اچھے معیار کے تراجم سامنے آنے چاہئیں تاکہ دیگر قومیں ہماری زندگیوں اور معاشروں کو بہتر طور سے سمجھ سکیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:
عمرمیمن:
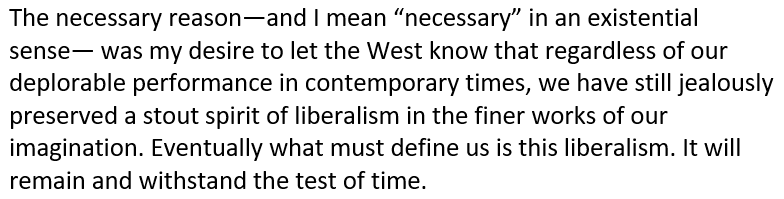
زہرا صابری: یہاں پہ جب وہ لفظ ’لبرلزم‘ استعمال کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اِسے ’رواداری‘ کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ خیر، بہت سی باتیں ہیں، بہت سی یادیں ہیں۔ باقی انشاء الله کسی اور دن بیان ہوں شاید۔ ان کے تراجم کے بارے میں سی ایم نعیم صاحب نے جو ایک جگہ لکھا ہے، وہ میں دہرا دیتی ہوں:
سی ایم نعیم :
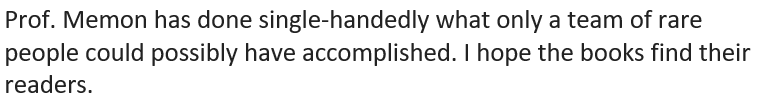
زہرا صابری: آخر میں بس یہی کہوں گی کہ آخری بار جب میری ان سے ’ملاقات‘ ہوئی تھی اسکائپ پر تو مجھے نہیں احساس تھا کہ وہ کس قدر بیمار ہیں، اور ان کا مرض کس حد تک بڑھ گیا ہے۔ یہ ان کی وفات سے کچھ ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات ہے۔ شاید درد کی شدت کے باعث وہ بار بار اپنی ڈیسک چیئر میں بیٹھے بیٹھے ذرا جھک سے جاتے تھے۔ میں انہیں کہتی کہ آپ کا چہرہ کمپیوٹر کی اسکرین کے لیول سے ہٹ رہا ہے۔ تو بہت ہی خاموشی سے اور مروت سے وہ اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ آخری دنوں میں بھی، جب انہیں معلوم تھا کہ اب ان کے پاس کم ہی وقت بچا ہے، انہوں نے دوستوں کے لئے وقت نکالا اور اپنی تکلیف بھی ظاہر نہ ہونے دی۔ آخر میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کے دوستوں میں حوری نورانی صاحبہ سے سب سے گہری دوستی تھی ان کی۔ یہ ایک مصنف اور پبلشر کے تعلق سے شروع ہوئی اور بڑھتے بڑھتے ان دونوں میں شفقت اور احترام کا ایک گہرا رشتہ قائم ہوا۔ حوری نورانی صاحبہ ہی جانتی تھیں کہ میمن صاحب کس قدر بیمار ہیں اور اس سب کی کیا تفصیلات ہیں۔ ورنہ میمن صاحب اس بات کو بہت private رکھنے کے حق میں تھے۔ مجھے خبر نہیں تھی لہذا جب آخری ملاقات ہوئی تو میں پوری طرح سمجھ نہیں پائی کہ ادب کے حلقوں کی عمومی صورت حال سے تکلیف آج اور بھی زیادہ نمایاں کیوں ہو رہی ہے۔ انہیں شدید کوفت تھی کہ بہت سے لوگ جو مفید کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شہرت کمانے اور بے معنی ادبی ایوارڈز بٹورنے کی خاطر اس قدر دوڑ دھوپ کیوں کر رہے ہیں۔ وہ اپنے تخلیقی اور علمی ارمانوں کو مزید بلند کیوں نہیں کرتے اور سچی طرح فنی اور پیشہ وارانہ کمال پانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ ان کا ماننا تھا کہ لوگوں کو ذاتی تشہیر (self-promotion) کم اور کام زیادہ کرنا چاہئے اور اپنے کام کے معیار کو بہتر کر کے اس میں نکھار لانا چاہئے۔ انہیں افسوس ہوتا تھا جب لوگ اپنی صلاحیتوں کو فضولیات میں گنواتے تھے۔ He was sorry to see certain prominent people in the literary establishment waste their talents in going after small gains۔ انہوں نے کچھ سال پہلے ایک خط میں لکھا تھا:
عمرمیمن:
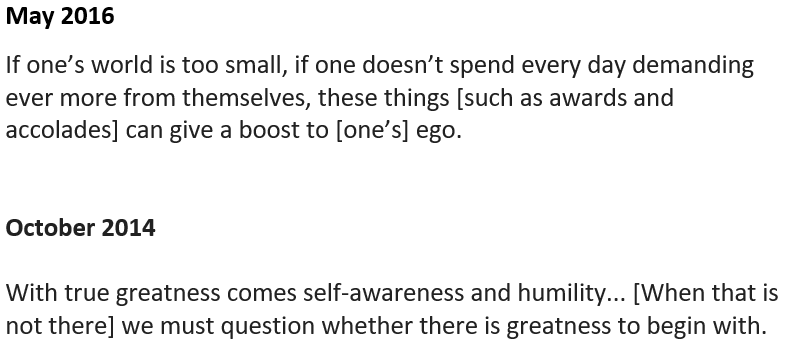
زہرا صابری: وہ ہرگز ایسے لوگوں میں سے نہ تھے جو صبح شام اپنی تعریف سننا پسند کرتے ہوں اور پھرسب تعریفیں بٹورنے کے بعد جھوٹ موٹ کی انکساری اور کسر نفسی کا ڈھونگ رچاتے ہوں۔ جتنا انہوں نے خود کام کر کے دکھایا تھا، آپ ان کی صلاحیتوں کو اس سے زیادہ سمجھیں یا سراہیں تو وہ آپ کو خود ہی ایسا کرنے سے روک دیتے تھے۔ وہ محمد حسن عسکری کے بارے میں اکثر اتنے شوق سے بات کرتے تھے کہ میں ان سے کہتی تھی کہ آپ اگر اس موضوع پر ذاتی طور پر کتاب لکھیں، تو انگریزی کے قارئین کے لئے کتنا مفید ہوگا۔ ایک خط میں جواب دیا:
عمرمیمن:
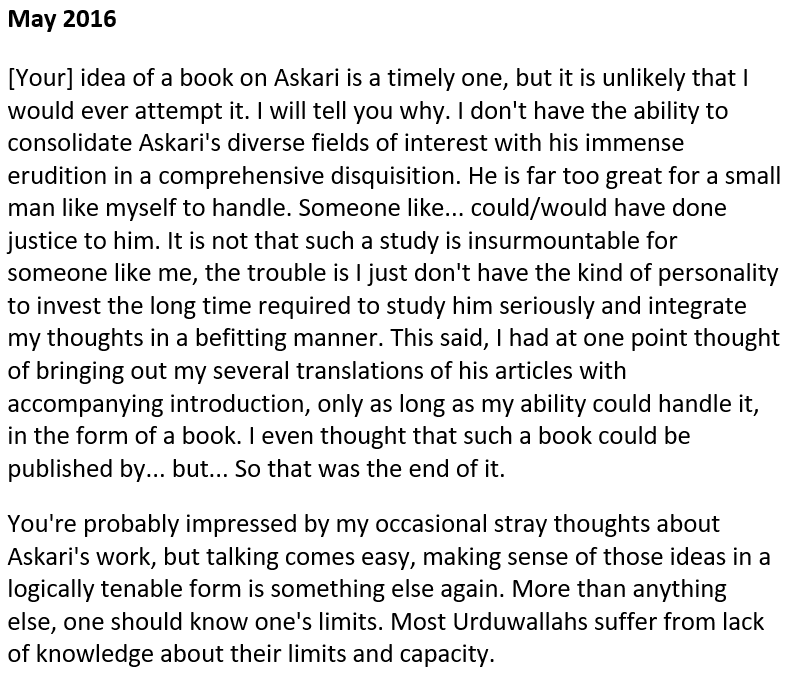
زہرا صابری: اس آخری ملاقات کے روز وہ اردو ادبی حلقوں کی کچھ عادتوں اور روایات سے کافی مایوس دکھائی دے رہے تھے، اور انہیں ایسی کچھ چیزوں کی بہت تکلیف تھی۔ اس گفتگو کو سن کر مجھے بھی ظاہر ہے بہت تکلیف محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ انہوں نے تو بہت بہتر دور دیکھا ہے اردو زبان اور اردو ادب کے لئے، ایسی ایسی شخصیات دیکھی ہیں، ایسے ایسے لوگوں سے سیکھنے کو اور گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے انہیں، اور پھر بھی وہ کافی رنجیدہ ہیں۔ اور ہم جن کی قسمت میں (زندگی رہی تو) لکھا ہے دیکھنا ان روایات اور ان علوم کے جنازوں کا اگلا ہی مرحلہ، سوئم، چہلم، پتا نہیں کیا کیا، ہمیں کس قدر تکلیف اور رنج ہونا چاہئے۔ جو یہاں اب ہوگا وہ ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ ان کو اتنی تکلیف ہے، ہمیں کتنی ہونی چاہیے اور ہمارے لئے کتنا مشکل ہو گا یہ سب دیکھنا۔ کیونکہ ہم تو شاید اس قابل بھی نہیں ہیں کہ جتنے وہ تھے اعلی سطح کی خدمات انجام دینے کے۔
آخر میں بس یہی۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب بہت بد قسمت رہے کہ ان جیسی شخصیت موجود تھی ہمارے درمیان اور وہ یہاں آنے کو اور ہم سب سے بات کرنے کو بھی تیار تھے حالانکہ یہاں پر اداروں کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں امریکن اکاڈیمیا میں کام کرتے ہیں۔ یہاں سے جاتے ہیں۔ پھر وہی ان کی دنیا بن جاتی ہے۔ وہ زیادہ تر اپنا تخلیقی اور تحقیقی کام اردو میں شائع بھی نہیں کرتے۔ وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں پیچھے مڑ کے کیونکہ وہاں پہ انہیں کئی زیادہ معاشی اور پیشہ وارانہ سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ میمن صاحب ان چند لوگوں میں سے تھے جو پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اردو قارئین تک ان کی محنت کے ثمرات پہنچیں۔ لیکن کچھ اور اسکالرز کی طرح میمن صاحب کو بھی علم کی قدر نہ کرنے والے پبلشرز نے کتنا ہی تنگ کیا۔ یہاں جو پبلشنگ کے غیر معیاری رویے تھے، ان سے وہ کافی پریشان ہو گئے تھے۔ کئی کئی مسودے پڑے تھے ان کے پاس جو پبلشرز کی حرکتوں کے جھنجھٹ سے بچنے کی خاطر انہوں نے شائع نہیں کروائے تھے۔ لیکن آخری سالوں میں اپنے دوست اکبر زیدی کے توسط سے ان کی حوری نورانی صاحبہ سے ملاقات ہوئی اور بہت سے کام خیر و عافیت اور تیز رفتار سے ہو پائے۔ ایک خط میں انہوں نے لکھا:
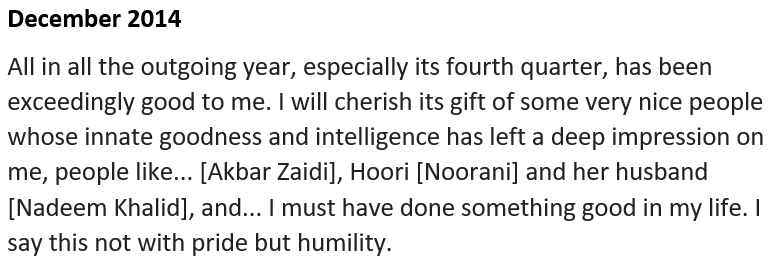
زہرا صابری: اتنی زیادہ انکساری کے ساتھ دوستوں کے لئے اظہارِ قدر دانی۔ بہت سی یادیں ہیں ان کی مروت اور اخلاص کی۔ اور مجھے افسوس ہے کہ ان کو اور ان جیسے کچھ دوسرے بھی ذمہ داری سے کام کرنے کی خواہش رکھنے والے ادیبوں کو اور اسکالرز کو ہمارے یہاں کے کئی پبلشنگ ہاؤسز اور اخبار والے مدیران اس قدر ستاتے اور ترساتے رہے ہیں۔ اگر کوئی ڈھنگ کا آدمی لکھ رہا ہے آپ کے لئے تو اس کی قدر کرو، اس کے کام کو چھاپنے میں احتیاط دکھاؤ نہ کہ اس میں اپنی لا پرواہی کی وجہ سے غلطیاں داخل کرو، اگر وہ تمہیں کوئی خط یا ای میل بھیجتا ہے تو اس کا تمیز سے اور ذمہ دار طریقے سے جواب دو، نہ کہ غلطی کرو اور غائب ہو جاؤ اور چوری کرو اور پھر سینہ زوری کرو۔ تمہارے پاس ایک اچھی چیز آ رہی ہے تو اس کی قدر کرو اور اس کے لکھنے والے کی قدر کرو اور اسے ڈھنگ سے چھاپو اور اپنے سب ایڈیٹرز کو بھی بات کرنے کی تمیز سکھاؤ۔ اور جہاں تک ادبی فیسٹولز وغیرہ کا تعلق ہے، انہیں بھی چاہئے کہ وہ دل بڑا کریں۔ سامعین کی ذہنی نشو و نما کا خیال کریں نہ کہ اپنی ہی انا کی پرستش۔ ہر سال ایک ہی تماشا لگانا، انہی چند لوگوں کو دعوت دینا جو شاید آپ کے خاص جاننے والوں میں سے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کی تعریف زیادہ کرتے ہیں اور آپ کو ٹھیک سے سلام کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اردو اور علم کو پیشِ نظر رکھیں اور اسی کو ترجیح دیں تو کوئی اگر آپ کی برائی بھی کرے لیکن اس کا علم اتنا زیادہ ہو اور اس کا علمی دنیا میں ایک جائز مقام ہو، تو ایسے موقعوں پر اس کو ضرور بلانا چاہیے اور سامعین کو اس سے ملوانا چاہیے۔ ہر سال وہی چار پانچ چہرے، وہی سنے سنائے خیالات کا اظہار، کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی کے پاس بھی اتنا مواد نہیں ہوتا کہ وہ ہر سال آ کر کوئی نئی بات کرے۔ ان ادبی تقریبوں کا نظام اتنا personalized نہیں ہونا چاہئے اور یہاں اتنی gate-keeping نہیں ہونی چاہیے ۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں ملک کے اندر بھی اور باہر بھی جن کا علم و فن عوام تک پہنچ نہیں سکتا۔ بالکل آخر میں، آخری خط جو میں نے محمد عمر میمن کو لکھا، اس کا اقتباس پیش ہے: