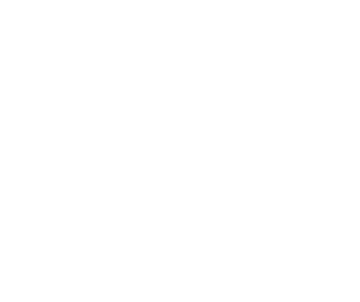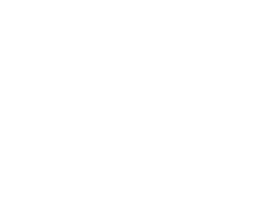گُرگِ شب: اکرام اللہ (تبصرہ: بلال حسن بھٹی)
بچپن میں جب آس پاس کے لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوں تو آپ کے اندر خود اعتمادی آ جاتی ہے۔ ایک ایسی خود اعتمادی جو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط شخصیت بنا دیتی ہے۔ لیکن جب کسی پیدائشی حادثے ، جس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، کے نتیجے میں آپ کے رنگ، عقل، نسل ذات کو لے کر اسی بچپن میں آپ کو ہر طرف سے طعنے، کوسنے اور تضحیک کا نشانہ بنایا جائے تو آپ کی شخصیت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ بچپن میں اپنے رنگ، عقل، نسل، اور ذات پر ہونے والی تنقید اور لوگوں کی ملامتی باتیں آپ کے لاشعور میں بننے والے پھوڑے کی طرح یا سانپ ڈسنے کے زخم کی طرح ہوتی ہیں جو اندر کا موسم سرد ہوتے ہی اپنے زہر کا اثر دوبارہ دکھانا شروع کر دیتی ہیں۔ موسم جو پرانے زخم کو مکمل تازہ کر دیتا ہے، زخم جو آپ کے وجود کو کچوکے لگاتا رہتا ہے، زخم جس سے آپ جان چھڑانے کی جتنی کوشش کر لیں سب بے سود نظر آتی ہیں۔
ایسے میں جب آپ ان طعنوں، کوسنوں اور تنقید کے سامنے بے بس ہو جائیں تو جوان ہوتے ہی آپ کے اندر اس ماحول سے فرار کی خواہش شدید تر ہو جاتی ہے۔ آپ وہاں سے بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ یہ فراریت یا تو کسی جرم کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جو اپنے ساتھ زیادتی یا نارواسلوک کرنے والے ہر شخص پر روا رکھا جاتا ہے یا یہ ایک نئی پہچان حاصل کرنے کی لگن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک ایسی پہچان جو معتوب کی پرانی پہچان کو مٹا دے۔ جو اسے ان سب سوالوں سے نجات دلا دے جو آس پاس کے لوگ اس کے سامنے قدم قدم پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ ایسا شخص کسی مثبت سرگرمی میں پناہ لیتا ہے۔ وہ پڑھ لکھ کر یا کوئی کام دھندا کر کے ایک ایسا مختلف شخص بن جانا چاہتا ہے جس کی معاشرے میں عزت ہو۔ عزت کہ جو اس تمام ذلت کو مٹا دے جو اس کے بچپن میں اس کے رنگ، نسل، یا ذات کے نام پر اس پر تھوپی گئی ہو۔ لیکن کیا دولت، عزت، شہرت کالک ملی اس تہہ در تہہ سیاہی کو جس کا وجود باطن پر نقش ہو دھو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ہے وہ سوال جو گُرگِ شب کو پڑھتے بار بار ذہن پر دستک دیتا ہے۔
گُرگِ شب کا شفیع بھی ایسے ہی ذلت بھرے لمحوں سے نجات کے لیے گھر چھوڑ کر اپنی محنت سے کپاس کا ایک بڑا تاجر بن جاتا ہے۔ پیسہ، شہرت، بنگلہ، گاڑیاں نیز طاقت کے ہر مروجہ مورچے کو حاصل کرنے اور اپنا نام بدل کر ظفر رکھ لینے کے باوجود وہ اس سیاہی سے نجات نہیں حاصل کر پاتا جو اس کے چہرے پر اس کی پیدائش سے پہلے مَل دی گئی ہے۔ وہ کالک تھی حرامی پن کی کالک۔ وہ اس سوال سے مسلسل نبردآزما رہتا ہے کہ کیا وہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھائی سمجھے یا باپ؟ اپنوں، اجنبیوں، دوستوں، دشمنوں، حتی کہ اس سے محبت کا دعوی کرنے والی حلیمہ سے اس بات کا ذکر سن کر، کے وہ اپنے بھائی غلام حسین کی اولاد ہے، اس کا وجود ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور اس کا خون منجمد ہو جاتا ہے۔ اس کے حواس اس کے ضبط سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ سوال اسے وجود کی شکست و ریخت کی طرف لے جاتا ہے۔ جب اس کے حرامی ہونے کی بات اس کے سامنے کی جائے تو اسکا وجودی بحران مزید بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک لمحے میں جب نہر پر نہاتے ہوئے اس کے دوست محسن نے کہا کہ ”رسولا کہتا ہے شفیع حرامی ہے“ تو اس لمحے شفیع کی کیفیت کچھ یوں ہو جاتی ہے۔ ”میں نے لحظے بھر اس کو دیکھا جیسے مرتا ہوا ہرن اپنی آبدیدہ آنکھوں سے شکار کو رحم طلب نظروں سے دیکھتا ہے اور کچھ کہے بغیر نہر میں غوطہ لگا دیا۔ میں بہت دیر پانی میں چھپا رہا۔ وہاں ایک بے حد دھندلا مٹی کے رنگ سا مبہم اجالا پھیلا تھا جس میں کچھ دکھائی نہیں پڑتا۔ اس خاموشی میں گزرتے ہوئے پانی کی ہلکی ہلکی سائیں سائیں اور میرے دل کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دیتی تھی۔ میں کچھ سوچ نہیں رہا تھا، کسی بے انصافی کا خیال نہیں تھا۔ صرف ایک خواہش تھی کہ میں باہر نہ نکل سکوں اور میرے خجل اور شرمندہ بدن پر اس کی دوبارہ نظر نہ پڑے ۔“
یہ سوال کہ شفیع کیا تم اپنے بھائی غلام حسین کی اولاد ہو؟ اس کی زندگی کا سب سے بڑا روگ بن گیا تھا جو اس کے وجود کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ خوف اور تنہائی کی اس اندھیر نگری سے نجات کے شفیع کو دو ہی طریقے نظر آتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو وہ تھا جس پر وہ عمل کر رہا تھا۔ یعنی شراب پینا اور اتنی شراب پینا کہ اس کے حواس بحال ہی نہ ہوں۔ ایک گلاس کو چوم کر غٹاغٹ پینے سے پہلے بولے گئے ان چند جملوں میں شفیع کے لیے شراب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ” واہ میری محبوب کیا کہنے تیرے۔ کبھی مجھ سے کچھ نہیں چاہا۔ اور ہمیشہ میرے دل میں چبھے ہوئے کانٹوں کو ایک ایک کر کے چُن لیا۔ اتنا ڈھیر سارا سکون مجھے کون دے سکتا ہے۔ میری پہلی اور آخری محبوب“ـ لہذا وہ اتنی پیتا تھا جتنی وہ پی سکتا تھا لیکن پھر بھی وہ جتنی پیتا تھا ہر رات سونے کے بعد اس کے خوابوں میں وہی ملامتی باتیں اور وہی الزامی واقعات ہوتے تھے۔ نجات کا دوسرا طریقہ تھا کسی عورت کی آغوش میں پناہ لینا۔ ایک ایسی عورت جو اس کی شخصیت کی گرتی عمارت کو اپنی نازک اداؤں اور محبت بھری نگاہوں سے سہارا دے۔ وہ اس راستے کو اپنی ذات کا مستقل حصہ بنانے کے لیے ایک سرکاری آفیسر کی بیوی کا سہارا لیتا ہے جو اس کو کندھا دینے اس کی خوابگاہ تک پہنچ جاتی ہے لیکن اپنے پرانے خوف اور ڈراؤنے خوابوں سے طاری ہوئی ہیجانی کیفیت ظفر کو اندر تک منجمد کر دیتی ہے جس سے اس کی جنسی کوشش کا اختتام بھی شرمندگی اور ذلت کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔

زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنے کے باوجود ظفر محسوس کرتا ہے کہ وہ کہیں دھنستا جا رہا ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے اور سانسیں بند ہو رہی ہیں۔ کہیں نیچے اتھاہ گہرائیوں میں تاریک وادیوں میں ڈوبتے ہوئے کہ جہاں اندھیروں کی بڑھتی ہوئی سیاہی میں اس کی آہ و زاری اور چیخ و پکار دب کر ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اسے اس بات کا احساس ہے کہ وہ اندھیروں سے نکلتی اس گونج کا اگر مسلسل شکار رہا تو اس کا سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، اس کی سالوں کی کمائی ڈوب جائے گی اور وہ ویسے ہی کوڑی کوڑی کو ترسا کرے گا جیسے وہ فیروز آباد سے نکلتے وقت ترسا کرتا تھا۔ مستقبل اور ماضی کی اس لڑائی میں لمحہ موجود میں بیٹھا ظفر گھن چکر بن کر رہ جاتا ہے۔ اس لڑائی میں ماضی جیتے یا نہ جیتے لیکن وہ آخر کار تھکا دینے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے۔ وہ خوابوں کے بھیانک پن کا شکار ہو کر شکست خوردہ ہو جاتا ہے۔ ایک بار وہ یوں سوچتا ہے کہ ”میں خوابوں کے بھیانک پن سے اتنا نہیں ڈرتا کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر خواب چاہے کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو اس کا خوف دل سے محو ہوتے ہوتے تقریباً بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جو چیز میرے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے، وہ ایسے خوابوں کا تواتر سے ہر رات آتے رہنا ہے۔ جو اس امر کی نشانی ہے کہ مجھے پتہ چلے بغیر میرے اندر ایک بہت بڑے پیمانے پر ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ اور کئی بدصورت، قبیح، بیمار اور اپاہچ قسم کی چیزیں جگہ جگہ میرے ذہن میں اپنی تخلیق کے ابتدائی مراحل طے کر رہی ہیں۔ میں یوں محسوس کرتا ہوں جیسے مجھ پر کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے جس کی بدولت کچھ عرصے بعد میں بیک وقت غلاظت پر بھٹکنے والی مکھی، ہزار پاؤں والا کنکھجورا، کلبلاتا ہوا کینچوا اور لج لج کرتی سیاہ جونک میں مبدل ہو جاوں گا۔ جس سے نہ صرف ہر دیکھنے والے کو گِھن آئے گی بلکہ مجھے خود گِھن آئے گی ۔ “ـ
کردار نگاری کے حوالے سے ظفر بظاہر شکست خوردہ لیکن اپنی اصل میں ایک توانا کردار بن کر ابھرتا ہے۔ شفیع یا ظفر کا کردار پورے ناول میں مرکزی حثیت کا حامل ہے۔ اپنے تمام تر مسائل سے آگاہ ہونے کے باوجود وہ بے بس نظر آتا ہے۔ اپنے خوابوں کے خلاف شعوری لڑائی اسے مینٹل ہسپتال تک لے جاتی ہے۔ اپنے ماضی سے چھٹکارہ حاصل کرنے اور مستقبل میں غربت کے ہاتھوں در بدر ہونے کا خوف اس کے حال کو الم ناک بنا دیتے ہیں۔ بطور مرکزی کردار اس میں خود کو بدلنے کے ارادے کی کمی نہیں ہے۔ بظاہر اس کا خوف اس کی تمام تر کوششوں پر حاوی نظر تو آتا ہے لیکن جو چیز اس کے کردار کو زندہ رکھتی ہے وہ ایک خاص قسم کی تہہ داری ہے۔ ایسی تہہ داری جس میں تمام تر الجھنیں، مایوسیاں اور خوف اس کو مکمل طور پر ہرانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ناول کے اختتام میں پہنچتے ہوئے ہم ظفر کو ختم ہوتے ہوئے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ خود کو دوبارہ زندگی کے منظر نامے پر لاتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔
لگ بھگ ایک سو پندرہ صفحات کا یہ مختصر ناول اپنے اندر وجودی بحران کی ایک المناک داستان چھپائے ہوئے ہے۔ تہہ درد تہہ اپنا آپ ظاہر کرتی اس کہانی میں ہمارے آس پاس موجود انسانی وجود پر لگے بے شمار چھپے کانٹے ابھر کر سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کانٹے جو ہم اپنے آس پاس کے متاثرہ لوگوں پر زبان کی لذت کی خاطر خود بھی جانے انجانے میں لگاتے ہیں۔ مجھے آندرے ژید کا وہ قول یاد آ رہا ہے جو اوپندر ناتھ اشک نے منٹو پر اپنے معروف خاکے’منٹو، میرا دشمن‘ کے ابتدا میں درج کیا ہے ’نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کمینہ بننا ضروری نہیں، لیکن زندگی کا المیہ یہ ہے کہ بھلے اور شریف لوگ، جو باہمی محبت کرتے ہیں، تمام تر نیک خواہشات کے باوجود ایک دوسرے کو سخت صدمے پہنچا سکتے ہیں‘۔یہ ناول ہمارے معاشرے کے اس اجتماعی رویے پر شدید تنقید ہے جس میں زخموں پر مرہم رکھنے سے زیادہ ان کو کرید کر مرچیں لگانے کا کردار ادا کیا جاتا ہے۔ سلیم الرحمن صاحب کے الفاظ میں ’ اکرام اللہ کا ناول ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم سب میں ہمدردی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کتنی کمی ہے اور دوسرے لوگ عذاب کیوں ثابت ہوتے ہیں ‘ جیسا کہ شفیع کے ساتھ اس کی بھابھی، دوستوں اور اس کی محبوبہ ریحانہ نے اس کو بتا کر یا یہ سوال پوچھ کر تکلیف میں مبتلا کیا کہ کیا وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے؟ اعلی طبقے کی منافقت، بے راہ روی اور مفادات کے لیے کسی حد تک گر جانے کی جو تصویر کشی اس ناول میں کی گئی ہے وہ مبنی بر حقیقت ہے۔ ناول میں لمبی چوڑی منظر نگاری نہیں کی گئی۔ تہہ در تہہ خود کو کھولتی اس کہانی میں واقعیت بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس واقعیت میں جلدی سے سب کچھ کہہ دینے کی خواہش نظر نہیں آتی بلکہ یہ دھیرے دھیرے اپنے اصل موضوع کو سامنے لاتی ہے۔
چار دہائیاں پہلے اکرام اللہ صاحب کا یہ ناول جب پہلی دفعہ شائع ہوا تو اس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ شاید اس وقت معاشرہ اپنی اقدار پر اس کہانی کو ایک حملہ سمجھتا ہو گا۔ لیکن آج، جب ہر طرف موبائل انٹرنیٹ کے زیر سایہ پروان چڑھتی نئی نسل انسیسٹ (incest) کا تب سے کہیں زیادہ علم رکھتی ہے، یہ کہانی پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں آج کی نسل کے لیے ان تمام خطرات سے آگاہی بھی موجود ہے جو اس راستے کے مسافروں کو پیش آ سکتے ہیں۔ اس آگاہی کے ساتھ ساتھ ایک تنبیہہ بھی ہے کہ یہ راستہ نہ صرف آپ کی بلکہ آپکی آنے والی نسلوں کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا ایسے میں یہ کہانی ہمیں نہ صرف انسان کے اندر معاشرے میں خوف پیدا کرنے والے عوامل سے آگاہ کرتی ہے بلکہ بین السطور ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے کی تجویز بھی پیش کرتی ہے۔ چار دہائیاں گزر جانے کے بعد آج بھی اس ناول کا موضوع اور کہانی تازہ ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو اپنے موضوع، اسلوب اور کردار کی مضبوطی کی وجہ سے خود کو لازوال بنا لیتی ہے۔ خوبصورت نثر، الجھا دینے والے سوال، مضبوط اور نپا تلا پلاٹ اسے ایک بڑا ادبی شہہ پارہ بناتے ہیں۔ ایسی کہانی پر معاشرتی شعور پنپنے کے خوف میں مبتلا حکومت ہی پابندی لگا سکتی ہے۔ محمد خالد اختر کے بقول ” ’گُرگ شب‘کے آنے سے مایوسی کا رنگ تازگی اور امید میں بدل گیا ہے اور بے کسی پر نوحہ خوانی کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اکرام اللہ نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ اگر چیئرنگ کراس پر سونے کا بُت قائم کیا جائے تو مناسب ہو گا۔“
ناشر: عکس پبلیکیشنز
قیمت: 300 روپے