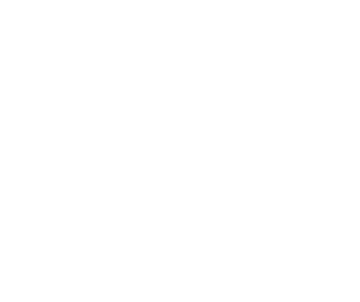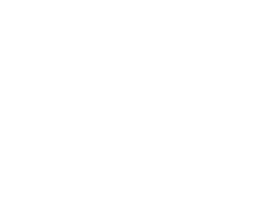اِک چُپ، سو دُکھ از آدم شیر- تبصرہ: بلال حسن بھٹی
”اِک چُپ، سو دُکھ“ آدم شیر صاحب کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ویسے تو یہ مقولہ مشہور ہے کہ ایک چُپ سو سُکھ لیکن ایک چُپ ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان کو اندرونی طور پر کاٹتی رہتی ہے۔ جس سے جذبات کا خاموش لیکن گہرا تلاطم پیدا ہوتا ہے۔ ایسی چُپ بظاہر تو انسان کو پرسکون دکھاتی ہے لیکن انسان اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے، بالخصوص وہ شخص جو اپنے اردگرد ہونے والے ظلم، زیادتی، حادثات اور واقعات کو اپنی تمام تر حساسیت کے ساتھ محسوس کرتا ہو۔ آدم شیر صاحب بھی انہیں میں سے ایک ہیں۔ چونکانے اور کچھ وکھرا دکھانے کا شوق ان کے ہاں نظر نہیں آتا۔ ان کی کہانیاں اور نثر انتہائی سادہ لیکن مشاہدات میں گہرائی نظر آتی ہے۔ وہ سادہ لیکن روایتی لاہوری زبان کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں پرانے لاہور کے لوگوں کی محرومیوں، تکلیفوں، رہن سہن اور سوچ کے انداز سے آگاہ کرتے ہیں جو اس لاہور سے بہت مختلف ہے جو زندگی کی تمام تر تیزیوں اور رنگینیوں کو اپنے اندر سموئے دوڑتا بھاگتا رہتا ہے۔ آدم شیر کے افسانے پڑھتے ہوئے ایک ایسے باپ کا تصور ابھرتا ہے جو اپنے بلکہ سب کے بچوں کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ ایک ایسے انسان کا تصور ابھرتا ہے جو انسان نما مخلوق کو عزت دینے کی بات کرتا نظر آتا ہے۔ عورت کو معاشرے میں عزت دینے کی التجا کرتے نظر آتا ہے۔ ایسا شہری ہمیں نظر آتا ہے جو دہشت گردی کا شکار ہونے والے اپنے بھائیوں کے لیے فکر مند رہتا ہے۔
افسانہ ”دُبدھا“ میں والدین کی ترجمانی کرتے ہوئے جب بارہ دری کے قریبی سکول کے چار بچوں کو خون کی چھپڑی میں کانے مارتے دیکھ کر ایک باپ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو لے کر کہاں جائے۔ کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں بچوں کی معصومیت تو باقی رہ سکے۔ آج ہر طرف جب بچوں کے ساتھ ہونے والے حادثات کی خبر ملتی ہے تو ایک دفعہ والدین سوچتے تو ہوں گے کہ وہ کس ماحول، کس معاشرے میں اپنے بچوں کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ ”دُبدھا“ میں آدم شیر والدین کی معاشرے کے بارے میں اس کشمکش کو ہمارے سامنے خوبصورتی سے پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ ”دُبدھا“ کے علاوہ ”ہیولا“ ایک ایسا افسانہ ہے جس میں قاری کو جکڑ لینے کی تمام خوبیاں ہیں۔ ایک خرادیہ کیسے اپنے لخت جگر کو ایک بڑے ہسپتال میں لے جا کر بھی بچا نہیں پاتا۔ ایک ماں جو وینٹی لیٹر نہ ہونے کی وجہ سے ایمبوبیگ سے اپنے بچے کی سانسیں بحال کیے رکھنے کی تگ و دو میں لگی رہتی ہے۔ یہ سب مناظر ”ہیولا“ کو دل دہلا دینے والی لکھت بنا دیتے ہیں۔ ایمبوبیگ چلانا کس قدر مشکل اور تھکا دینے والا کام ہے اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب آپ نے ایمبوبیگ چلایا ہو۔ مختلف قسم کے وہموں، سوچوں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے جب آپ کے ہاتھ میکانکی انداز میں اس ایمبوبیگ کو دبا رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کے کسی پیارے کی سانسیں جڑی ہوئی ہیں تو آپ کا وجود تو وہاں موجود ہوتا ہے لیکن آپ کی سوچ وہاں نہیں ہوتی اور جب کسی کے بلانے اور ہلانے پر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ اس وقت آپ خود کو تھکے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی آپ کی مدد کے لیے آئے تو آپ اخلاقی طور پر بھی انکار نہیں کر سکتے بلکہ فوراً ایمبوبیگ اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک ماں پتا نہیں کن سوچوں اور وسوسوں میں گم اپنے لخت جگر کو مصنوعی سانس دیتی ہو گی۔ یہ تو ایک ماں کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر اس ماں پر پتا نہیں کیا بیتی ہو گی جب نرس نے اسے کہا کہ ”بچے کا دل گھٹا نہیں ڈوب گیا تھا“۔ یہ دل ڈوب جانا کی ترکیب خوب ہے گویا دل کوئی گھڑیال ہو یا کوئی انجن ہو جس سے جوں جوں دور ہوتے جائیں تو آواز دور کہیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔
آپ اگر اس کتاب کا ٹائٹل افسانہ ”اِک چُپ، سو دُکھ“ پڑھیں گے تو آپ کو لاہور کے مشہور قہوہ خانے کے سامنے ایک بچہ لیٹا نظر آئے گا۔ جب اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ دروازے سے دور ہو کر سو جاؤ کہ دروازہ کھلنے سے تمہاری نیند خراب ہو جاتی ہے تو اس کا جواب دل چیر دینے والا ہوتا ہے۔ ”ایتھے ٹھیک آں دروازے تھلیوں ہوا آندی اے“ـ اور اسی افسانے کے آخر میں ایک جگہ لکھا ہے ” میں نے اسے اُس بچے کی لاش بھی دکھائی جو ماں کے پیٹ میں تھا اور اس کی ماں کو نہ ناچنے پر گولی مار دی گئی تھی جو بچے کے دل کو جا لگی تھی۔ وہ بھاگ جلی مرتے مرتے بھی باجا بجانے والے جیون ساتھی کی بچت کر گئی کہ اسے دو قبروں کے پیسے نہیں دینے پڑے“۔ اس سادہ انداز میں دل دہلا دینے والی حقیقتوں کو سامنے لانا بہت مشکل کام ہے جس میں آدم شیر کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔
”انسان نما“ اور ”دس ضرب دو برابر صفر“ ایسے افسانے ہیں جو ہم کو انسانیت کے احترام، عورتوں اور خواجہ سراؤں سے روا رکھے گئے سلوک کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ”انسان نما“ کا کردار رفیق ہمیں جہاں یہ سمجھاتا ہے کہ اگر شبیر جیسے انسان نماؤں کی مدد کی جائے تو وہ بھی عام انسانوں کی طرح زندگی میں پڑھ لکھ کر اچھے عہدوں پر پہنچ سکتے ہیں تو دوسری طرف اس کمزور طبقے کو ان کی تمام تر کمیوں کے ساتھ قبول کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ افسانہ والدین کو ہمت دیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خواجہ سراؤں کی ٹولیوں کو دے دینے کی بجائے ان کی ہمت بن کر ان کا ساتھ دیں تو وہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ”دس ضرب دو برابر صفر“ کی بلو جو کہ گھر سے باہر کام کرتی ہے تو اسے گلی محلے کے بچے بھی ”بِلو ڈیڑھ سو بِلو ڈیڑھ سو“ پکارتے ہیں۔ جبکہ سارا دن محنت مزدوری کر کے گھر پہنچنے والی بِلو چیخ چیخ کر سب کو بتاتی ہے کہ وہ دو نمبر نہیں بلکہ وہ لوگ جو اس پر الزام لگاتے ہیں وہ دو نمبر ہیں بلکہ دس نمبر ہیں۔ بِلو کہتی ہے ” میں دو نمبر نئیں۔۔ دو نمبر تھانیدار۔۔۔۔ دو نمبر محلے دار۔۔۔ دونمبر میدا کنجر۔۔۔۔ وڈے آئے اک نمبر۔۔۔ میں دونمبر آں تے تسی دس نمبر کنجرو“۔ ایسے میں ماں کے پاس تھڑے پر بیٹھے بچے اور بچی کو دکھا کر جو کہ انجانے خوف سے ڈر اور سہم کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بیٹھے ہیں۔ ایک کام کرنے والی خاتون کو تنگ کر کے ہم کس طرح اس کی آنے والی نسل کو خوفزدہ اور چڑچڑا بنا رہے ہیں۔
اپنی تمام تر حساسیت، سادگی اور روزی روٹی کمانے کے چکروں میں گھرے کرداروں سے ہٹ کر ”ارتعاش“ اور”بھکاری“ جیسے افسانوں کے کردار ہمیں ریاستی ظلم اور دہشتگردی کی سفاکیت سے آشنا بھی کرواتے ہیں اور سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ ”ارتعاش“ میں ایک جگہ دہشتگردوں کو پروانوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے پروانے دوسروں کی جلائی ہوئی آگ میں جل کر خود کو ختم کر دیتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی دہشتگرد بھی خود کو دوسروں کی جنگوں میں استعمال ہو کر برباد کر لیتے ہیں۔ پھر افسانہ ”بھکاری“ کا بھکاری جو نائن الیون کے بعد قبائلی علاقوں میں ہونے والی تباہی کی تلخ تصویر پیش کرتا نظر آتا ہے۔ یہ تصویر اس قدر تلخ ہے کہ بھکاری کے ہر جواب میں گھلی کڑواہٹ اپنی تمام تر شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے ۔ بے شک اگر کسی کے گھر پر میزائل گرا دیا جائے اور اس کا سب کچھ تباہ ہو جائے تو اس پر جو بیتتی ہے وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ۔ معاشرے کی سنگ دلی اور دوغلاپن دکھاتے ہوئے بھکاری کہتا ہے ”یہاں لوگ حق دار کو اس کا حق نہیں دیتے لیکن بھیک دے دیتے ہیں“۔
مجموعی طور پر آدم شیر صاحب اندرون شہر کے باسیوں کی زندگیوں میں پائی جانے والی مشکلات کی تصویر کھینچتے ہیں ۔ وہ مجبوریاں صرف اندرون لاہور کے رہنے والوں کی ہی نہیں بلکہ وہ معاشی، معاشرتی اور فکری مجبوریاں ہر جگہ کے رہنے والے غریب طبقے کو دیکھنا پڑتی ہیں۔ جن حالات و واقعات کا ذکر آدم شیر صاحب کرتے ہیں وہ صرف اندرون لاہور تک محدود نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے معاشرے کا اجتماعی المیہ ہیں۔ اکثر پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اندرون شہر کی زندگیوں پر بات کرتے ہوئے لکھاری کی قلم میں عجیب روانی در آتی ہے۔ وہ ایسے اندرون لاہور کی تصویریں دکھانا شروع کرتا ہے جہاں کئی راجے مہاراجے اور بادشاہ اپنے تمام تر جاہ وجلال کو پیچھے چھوڑ کر ویران قبروں میں پڑے ہیں۔ جہاں وینٹی لیٹر جیسی مشینیں نہیں ہیں۔ جہاں بچوں کی حساسیت اور ان کا بچپنا ختم ہو گیا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہانی لکھنا اور اس کو محسوس کر کے پڑھنا بہت تکلیف دہ اور مشکل کام ہے۔ لیکن اس کہانی پر بات کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ آدم شیر کی کہانیاں بھی ایسی ہی ہیں۔ جو بات کرنا بظاہر تو آسان ہے لیکن ان کہانیوں کو محسوس کر کے اس پر سوچنا بہت کٹھن کام ہے۔ یہ کہانیاں نہایت سادہ زبان اور تکنیکی اعتبار سے روایتی انداز میں لکھی گئی ہیں۔ خاص کر جس روایتی پنجابی زبان کو استعمال کیا گیا ہے وہ نثر کی خوبصورتی بڑھا دیتی ہے۔ اس شاندار آغاز کے بعد امید کرتے ہیں کہ آدم شیر افسانہ نگاری کا یہ سفر جاری رکھیں گے اور ان کے فکشن میں اور بھی توانائی آئے گی۔