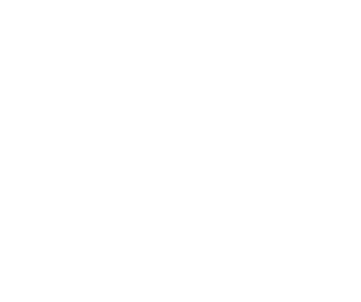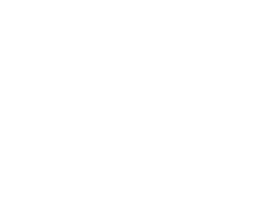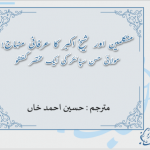انور صاحب کا گھر (تحریر: محمد حامد زمان)
مجھے معلوم تھا کہ انور صاحب اس روز گھر پر نہیں ہوں گے۔ اس کے باوجود میں ان کے گھر کی جانب رواں تھا۔
شہر سے بیس میل دور،ان کا یہ مسکن پرانی چھاؤنی کے وسط میں ہے۔ فاصلہ اس قدر زیادہ بھی نہیں کہ شہر سے وابستگی بھی نہ رہے، اور اس قدر قریب بھی نہیں کہ اس کا شور و غوغا اور آلودگی اعصاب پر اثرانداز ہوں۔ شہر سے نکلیں تو آڑھی ترچھی سڑکیں، کبھی مد اور کبھی جزر سے آشنا راہیں، انور صاحب کے کاشانے تک لاکھڑا کرتی ہیں۔ مئی کے اوائل میں یہاں پر خوب ہریالی تھی۔ گو دوپہر کے ساڑھے تین بجے تھے۔ سورج آسمان پر تھا تو سہی مگر شاید اپنی قوتِ تمازت اس جانب برسانے کا کچھ خاص متمنی نہ تھا۔ گویا نظامِ شمسی کے شہنشاہ کو اس امر سے قطعاً کوئی دلچسپی ہی نہ تھی کہ اس کے آسماں گیر ہوتے ہو ئے بھی، اور بادلوں کی چلمن کی عدم موجودگی کے باوجود، ہوا میں آسودگی باقی تھی ۔ فضا بھی اس روز گھٹن سے نا آشنا تھی۔
اس روز نہ جانے مَیں کن خیالوں میں گم تھا کہ اپنے معمول سے ہٹ کر میں نے ڈرائیور سے کچھ بھی بات نہ کی۔ نہ ہی اپنا ناتواں علم اس پر جھاڑا اور نہ ہی اس کی اپنی تاریخ اس کو سمجھائی اور نہ ہی اس سے کوئی سوال کر کے اس کا جواب خود ہی جھٹ سے گفتگو پر چسپاں کر دیا۔ وہ بھی شاید کسی خلوت کا رسیا تھا کہ اس نے بھی نہ کچھ پوچھا اور نہ کچھ کریدا۔ بیس منٹ کے سفر کے بعد ٹیکسی سڑک کے دوسری جانب رکی۔ مقررہ پتے پر ٹیکسی نے بنا کسی مشکل کے پہنچا دیا۔ میٹر دیکھا، کچھ نوٹ نکالے اور ڈرائیور کو تھما دیے۔ لین دین کے اس مرحلے پر اس نے بھی سر کو ہلکی سی جنبش دی اور میں نے بھی۔ اس نے گاڑی موڑی اور میں نے اپنے قدم، اور سڑک کی دوسری طرف آ نکلا۔
انور صاحب کے گھر کو ایک چھوٹی سے گلی جاتی تھی۔ گلی کے نکڑ سے انور صاحب کا گھر لگ بھگ دس منٹ کی پیدل مسافت پر تھا۔ چھاؤنی کے اس حصے میں روایتی ہرے رنگ میں فوجی ٹرک اور کچھ اور تنصیبات تو نظر میں آئیں مگر لوگ خال خال ہی تھے۔ ٹرک روایتی عسکری رنگوں کے کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے، گویا بوریت سے عاجز آ کر انہوں نے بھی چادر تانی اور آنکھیں موند لیں۔ اس چھوٹی سڑک کے دونوں جانب درخت اور بیل بوٹے تر وتازہ بھی تھے اور صحت مند بھی۔ ایک مقام پر آ کر یہ گلی رک گئی۔ اس مقام کے برابر ایک چھوٹا سا پارک تھا، جہاں لکڑی کے کچھ بنچ ایک دائرے کی صورت میں رکھے گئے تھے۔ اس وقت نہ اس گلی میں کوئی اور تھا اور نہ ہی اس پارک میں۔ یہ پارک غالباً تفریحِ طبع کے لئے تعمیر کیا گیا تھا۔ مگر یوں معلوم ہوتا تھا کہ اک عرصے سے ان بنچوں پر کوئی براجمان نہیں ہوا۔ اگر یہ پارک اس نیت سے تعمیر ہوا تھا کہ یہاں بیٹھ کر اہلِ خانہ کبھی دلبری کریں گے، یا شاید ساکنانِ محلہ غور و فکر کی نئی حدیں پار کریں گے تو وہ سلسلہ بظاہر ایک عرصے سے معطل تھا۔ ایک لمحے کے لئے میں نے سوچا کہ کیوں نا میں ہی اب اس منسوخ سلسلے کو دوبارہ آباد کروں اور کچھ دیر انہی بنچوں پر فکرِ روزگار اور سود وزیاں سے ماورا کچھ اور مسائل پر غور کروں ۔ ماحول خوشگوار بھی تھا اور یوں مجھے کسی کام کی جلدی بھی نہ تھی۔ دل کے کسی کونے سے صدا آئی کہ ایسا سکوت جس پر تقریر فدا ہو سکے کسی کسی کو کبھی کبھی ہی ملتا ہے۔ مگر نہ جانے کیا ہوا کہ کسی انجانی رکاوٹ نے مجھے ان بنچوں پر بیٹھنے سے باز رکھا۔ ان کی خاموشی ، اور ان کے عدم استعمال سے ایک ایسا طلسم پیدا ہوچکا تھا جسے توڑنے کا مجھے ہر گز کوئی حق نہ تھا۔ گویا یکایک ہمارے درمیان ایک ایسی دیوار آ گئی جسے پھلانگنے کی نہ مجھے اجازت تھی اور نہ مجھ میں صلاحیت۔ للچائی نظروں سے اس پارک کو دیکھتا ہوا میں بائیں جانب مڑ گیا جہاں انور صاحب کی رہائش گاہ کا صدر دروازہ تھا۔
صدر دروازه کچھ زیادہ خوشنما نہ تھا، مگر میری توقع بھی کسی الف لیلائی منقش در و دیوار کی نہیں تھی۔ مضبوط لوہے کی جالی ہٹا کر میں اندر داخل ہو گیا۔ میں اب اس احاطے کے اندر تھا جہاں اک زمانے میں بنا اجازت اندر آنے پر مکمل پابندی تھی ۔ روشنی کے لئے بھی یہ در و دیوار جائے ممنوعہ تھے۔ ۱۹۷۰ کی دہائی میں تعمیر ہونے والا یہ آشیانہ عجیب و غریب تاثرات اور احساسات کو جنم دیتا ہے۔ انور صاحب کی یہ رہائش گاہ ایک غیر معمولی تعمیر بھی تھی، اورانسانی نفسیات پر طاری ایک قوی خوف کا مظہر بھی۔ میں مزید اندر آگیا۔ چند قدم آگے بڑھا اور درجن بھر پیچ خوردہ سیڑھیاں مجھے زیر زمین لے آئیں۔ جونہی وہ سیڑھیاں ختم ہوئیں، میرے سامنے دو دروازے اور تھے۔ اس بار ان کی صناعی لوہے اور دھات سے نہیں بلکہ سیمنٹ اور کنکریٹ سے کی گئی تھی۔ دونوں دروازے آج وا تھے۔ اگر یہ وا نہ ہوتے تو میرے بازوؤں میں کسی طور بھی ان کو دھکیل دینے کی صلاحیت نہ تھی۔ ان دروازوں کی کنکریٹ کی چوڑائی کی پیمائش ہاتھ سے جو کی تو وہ میری ہتھیلی سے زیادہ وسیع نکلے۔ مزید اندرآیا تو اس جگہ پر اب خنکی کو بھی پایا اور اک عرصے سے معلق رہ جانے والی کہنہ ہوا کے احساس کو بھی۔ ان دو بڑے دروازوں کے بعد کچھ اور سیڑھیاں تھیں اور پھر ایک مستقیم راہداری۔
راہداری طویل تھی، اور حد نگاہ تک جاری رہنے کی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ جس جگہ میں کھڑا تھا، وہاں سے اس راہداری کا دوسرا سرا نظر نہ آتا تھا۔ دیواروں پر پرانی سفیدی تھی اور جا بجا اکھڑتی سفیدی پیچھے کی اینٹوں کو بے ستر کئے ہو ئے تھی۔ سر پر پرانے طرز کے موٹے بلب والے قمقمے جل رہے تھے، جن سے ہلکے زرد رنگ کی روشنی ٹپک رہی تھی۔ میں سیڑھی کے آخری زینے پر آ کر راہداری کی ابتدا میں ہی رک گیا۔
اس راہداری کے دونوں جانب چوکور کمرے یوں ایستادہ تھے جیسے تاریخ کی سڑک پرجا بجا نصب سنگِ میل۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
البانیہ کی قدیم تاریخ کےبہت سے سنگِ میل اب بھی باقی ہیں۔ قدیم زمانے کے دھند لکوں سے نکلیں تو سلطنتِ عثمانیہ کے دور کے کچھ سنگِ میل نمایاں طور پر نظر آئیں گے۔ ان میں سکندر بیگ کے عَلَمِ حریت کے رنگ بھی ہیں اور ایک بڑی سلطنت کی طاقت، بے پرواہی اورتنک مزاجی کی چھاپ بھی۔گو عمارات، مذہبی رجحانات اور کسی حد تک مزاجِ طعام میں البانیہ پر عثمانوی رنگ باقی تمام الوان سے زیادہ گہرا اور دیر پا ہے مگر اس کے باوجود البانیہ نے اپنی شناخت کے خدوخال کو کبھی مدہم نہیں ہونے دیا۔جان کی بازی لگا کر اپنی روایات کی رکھوالی کی۔ کئی صدیاں البانیہ کا کم و بیش سارا علاقہ عثمانوی سلطنت کی ایک چوکی رہا، مگر اس خطے کے باسیوں نے ترکی زبان کو ایک سیاسی اور دفتری زبان سے آگے بڑھنے نہ دیا۔داستانوں سے لے کر ماؤں کی لوریوں تک، غصے کے اظہار میں کہے گئے نازیبا جملے ہوں یا پھر پیار کے اقرار کے گیت، معاملہ کھلے بازار میں ہو یا پھر بند کمرے میں، البانیوں نے اپنی زبان کو نسل در نسل، قبیلہ در قبیلہ، اپنی شناخت اور اپنی ذات کے ساتھ منسلک رکھا۔ اور جونہی عثمانوی سلطنت کا سکہ چلنا بند ہوا، ترکی زبان نے بھی اپنی راہ لی۔
جب سلطنتِ عثمانیہ کی عمارت کے ستون بوسیدہ ہوئے، تو گرتے ہوئے اس ہیکل کو دھکا دینے والوں میں البانوی بھی تھے اور پردیسی بھی۔ بیسویں صدی کے آغاز سے لے کر دوسری جنگِ عظیم تک میراثِ سلطنت کے طرح طرح کے دعویدار منظرِ عام پر آئے۔ اس محبوب نے بہت سوں کو نئے خواب بھی دکھائے اور کچھ کو تختہ دار بھی۔ طالب ِ طاؤس و رباب میں اطالوی بھی تھے اور سرب بھی، ترک بھی اس راہ سے گزرے اور یونانی بھی۔ گردشِ زمانہ نے ایک بار یوں چکر کھایا کہ اچانک ایک نئے بادشاہ سلامت منظرِ عام پر آئے۔ شہنشاہ زوگ۔ ان کی حکومتی کشتی بھی سیاسی اور اقتصادی گرداب میں پیشتر وقت ڈولتی رہی اور پھر ڈوب گئی۔پھر ایک وقت ایسا آیا کہ تاریخ کے سارے سنگِ میل معمولی سنگ ریزے دکھائی دینے لگے۔ یہ ۱۹۳۹ کا سال تھا۔ بنی نوع انسان نے اپنے ہی بھائی بندوں کا گلا ایک عالمگیر سطح پر کاٹنا شروع کردیا۔
البانیہ نے دوسری جنگِ عظیم کے اتار چڑھاؤ میں بہت سے اتار دیکھے۔ جنگ کے اوائل میں مسولینی کی اطالوی حکومت نے البانیہ پر قبضہ کر لیا۔ دو سال بعد ایک بوجھل یتیم کی مانند ، البانیہ کو اطالوی حکومت نے اپنے رفیقِ اعظم نازی جرمنی کے حوالے کر دیا۔ایک دو سال تک یہ استعماری کاروبار چلتا رہا، مگر ایک طویل مدت تک اس سلسلے کا یونہی برقرار رہنا کچھ آساں نہ تھا۔ جرمنی کو ان دنوں کچھ اور بھی مسائل تھے ، مثلاً روس کے منجمد شہروں میں جرمن سپاہ گروں کی رسوائی ، اور یورپ کے مختلف محاذوں پر پسپائی۔ ایسے میں نازی حکومت اور افواج کے لئے البانیہ پر اپنا تسلط باقی رکھنا ممکن نہ تھا ۔ البانیہ کے چھوٹے بڑے قریے بھی یورپ کے ان بہت سے شہروں کی طرح تھے جہاں پر مدافعتی لشکر میں پیر و جواں بھی تھے اور مرد و زن بھی۔ بندوق بردار بھی تھے اور دہقاں بھی۔ طالبِ علم و فن بھی تھے اور سکول کی استانیاں اور استاد بھی۔ انہی اساتذہ میں سے ایک استاد کا نام انور ہوجا تھا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
میں راہداری میں موجود پہلے کمرے کے اند ر آ گیا۔ یہاں دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد کے دنوں کی تصاویر دیوار پر نمایاں تھیں۔ شاید یہ وہی دن تھے کہ جن دنوں میں امریکہ اور اس کے حامیوں کے ہاں ہر روز عید کا سماں تھا۔ وہی دن جب ہیروشیما اور ناگا ساکی کےبچ جانے والے زخم خوردہ عوام زندگی اور موت کے مابین ایک اندوہ ناک دوزخ میں معلق تھے۔ اور وہی دن کہ جب یورپ کے جنوب میں البانیہ کو ایک نئے نظام کی آمد کا امرت پلایا جا رہا تھا۔
عالمی سرد جنگ کے اوائل کے یہ دن البانیہ میں ایک نئے نظام اور اس سے چسپاں پراپیگنڈا کے ابتدائی دن تھے۔ ملک میں سوویت طرز کا نظام متعارف ہو چکا تھا۔ نقوش کہن جدھر نظر آ رہے تھے وہ مٹائے جا رہے تھے، کچھ بھوکے اور ناتواں مزدوروں کے پسینے سے، اور کچھ سوال کرنے والے اور راہ میں حائل شہریوں کے خون سے۔ میں جس کمرے میں کھڑا تھا اس کمرے کی تصاویر میں ماضی کی ان گنت دہائیوں کی تھکن سے ٓازدہ چہرے ، حال کے خوف سے شکستہ ماتھے ، اور ایک نا معلوم مستقبل کی آرزو لئے بھرائی آنکھیں، کیمرے کو دیکھ رہی تھیں۔ کسے معلوم کہ ان میں سے کتنے بچ نکلے اور کتنے پہلے برس ہی کھیت رہے؟ ان کی آوازوں کا کسی پیارے تک پہنچنا ممکن نہ تھا کہ ان دنوں ابلاغ کے ہر ذریعے سے ایک ہی طرز کی آواز آ رہی تھی۔ اک نئی سرکار کی آواز۔
کہا جا رہا تھا کہ صبحِ نو کی پہلی کرن البانیہ کے پہاڑوں کے اس پار بے تاب کھڑی ہے۔ کسی بھی لمحے اس کا ظہور ہونے کو ہے، اور پھر نہ کوئی بھوکا ہوگا اور نہ کوئی بے روزگار۔ نہ کوئی مفلس ہوگا اور نہ کوئی مظلوم۔ ان آوازوں میں سب سے زور دار اور پر یقین آواز ماضی کے اسی سکول ٹیچر کی تھی جو اب ملک میں کہنے کو تو سرخ انقلاب، مگر درحقیقت، سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ انور ہوجا۔
اگلا کمرہ چند فٹ کے فاصلے پر تھا، مگر یہاں تک پہنچنے سے پہلے مجھے تقریبا ایک دہائی کا سفر کرنا تھا۔اس دہائی کا جس میں آوازوں کو مقفل کیا گیا، سوچوں پر پہرے باندھ دیئے گئے اور اہلیانِ عالمِ ارواح کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا۔ اگلے کمرے میں اب ان برسوں کی تصاویر تھیں جب امید کی لو میں کچھ جان باقی نہ رہی تھی۔ شہریوں کی زندگی میں ایک جبری باقاعدگی آ چکی تھی۔ اب بات اس رسم سے کہ ”کوئی نہ سر اٹھا کے چلے“ سےبہت دور نکل چکی تھی۔ معاملہ اب رسم کا نہ تھا، بلکہ یہ تو حکمِ شاہی تھی۔ اس مطلق العنان شاہ کا کہ جو کہنے کو تو عوام دوست اور عوام شناس تھا اور طاؤس و رباب کو پاش پاش کرنے کو آیا تھا، مگر حقیقت میں اس شاہ کا دربار عشرت کے بیش قیمت مرمریں ستونوں سے سجا ہوتا۔ دربار میں سوغاتِ عالم بھی ہوتی اور قطار در قطار پہرے دار بھی یوں ایستادہ ہوتے کہ کوئی اہلِ دل و نگاہ سوال کرنے کو اس جانب نہ آن پہنچے۔ جن دنوں عوام کے پاس جھوٹی امید ، بوسیدہ سگریٹ اور سوکھی روٹی سے زیادہ کچھ نہ ہوتا ان دنوں حریت کے اس پیکرِ بے مثال کے ارد گرد خادموں کی اک فوج ہوتی جو اسے نازک آبگینوں میں سجے نایاب مشروب پیش کر تے۔ مگر کس کی ہمت کہ کوئی سوال کرے۔ محل کے باسیوں سے غرباء شہر کی رسائی تو ممکن نہ تھی مگر ہاں اتنا ضرور تھا کہ وقتاً فوقتاً اس حاکمِ وقت وبخت کی آواز ریڈیو پر سنائی دیتی تھی۔ کچھ باتیں فولادی یقین کی ہوتیں، اور کچھ دشمنانِ جان و مال کی ناپاک عزائم کی۔ چونکہ کہنے کو کچھ ہوتا نہیں تھا اس لئے تقاریر بہت لمبی ہوتیں۔ کبھی شعلہ بیانی سے جھوٹ بولا جاتا اور کبھی نرم گفتاری سے خیالی محل تعمیر کئے جاتے۔ زندگی اس قدر کٹھن ہوچلی تھی، اور بیزاری اس قدر شدید تھی کہ لوگ بھول چکے تھے کہ ریڈیو سے آنے والی آواز اُسی شخص کی ہے جو کسی زمانے میں علم کا فیض بانٹا کرتا تھا۔ وہی معلم اور مدرس: انور ہوجا۔
البانیہ کی اشتراکی حکومت نے اپنے آغاز میں سوویت یونین کو ہی اپنا مرشدِ اولیں تسلیم کیا۔ مگر جب جوزف اسٹالن جہانِ فانی سے کوچ کر گئے اور روس کی نئی حکومت نے اسٹالن کے رائج کردہ طرزِ حکومت، کہ جس کی بنیاد خاموشی، دہشت، رازداری، شک اور اپنوں سے بے وفائی کا ملغوبہ تھی، پر اعتراض کیا تو البانیہ کی حکومت نے گویا اس اعتراض کو دل پر لے لیا۔ کہا گیا کہ اسٹالن کے مظالم پر اعتراض گویا ہمارے عقائد کی توہین، بے حرمتی اور تضحیک ہے۔ البانیہ نے سوویت یونین سے منہ موڑا اور اپنا قبلہ چین کی طرف پھیر لیا۔ اس کے علاوہ علاقائی طاقتوں سے مڈ بھیڑ بھی جاری رہی۔ برابر میں یوگوسلاویہ سے بھی کبھی آنکھیں لڑائیں اور کبھی تعلقات اس قدر خراب ہو گئے کہ یوگوسلاویہ کا نام سنتے ہی حکام ِ اعلی کے منہ سے دھواں نکلنے لگتا۔ بین الاقوامی ہرجائیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں نہ ہی کوئی سرمایہ کاری ہوئی اور نہ ہی سیاحوں کی کوئی آمد و رفت۔ باہر سے تو کسی نے کیا آنا تھا، البانیہ کی حکومت نے اپنے لوگوں کو بھی بیرونِ ملک جانے سے روک دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ البانیہ کے باسیوں کے تخیل میں محفوظ ترقی کی کنجیاں دشمن لے اڑیں؟ ایک وقت ایسا آیا کہ البانیہ اقوامِ عالم سے مکمل طور پر کٹ کر رہ گیا۔ کہنے کو صدیوں پرانی ثقافت، جس کی جڑیں قدیم عہد سے جا ملتی تھیں، اب زمانے کی شاخوں سے کٹ چکی تھی ۔ ایک شخص کی ضد سے وہ دھرتی جو کبھی رومی اور کبھی یونانی تجارتی قافلوں کی دنیا سے منسلک تھی، اب ایک بیزار مقفل جزیرہ بن کر رہ گئی تھی۔ اس جزیرے میں آمد و رفت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو وقت کے ساتھ ایک انجانے خوف کی مکمل گرفت میں تھا۔ آنے والے وقت میں ایک انجانے قہر کا خوف۔ کیمائی اور جوہری جنگ کے خوف کا تسلط انور ہوجا کے دل و دماغ پر مکمل طور پر قابض تھا۔
اسی خوف کا نتیجہ تھا کہ انور ہوجا نے البانیہ کے چپے چپے پر زیر ِ زمین بنکر تعمیر کروائے۔شہر و قریہ، کوہ و میداں، سبھی کا سینہ چیر کر سیمنٹ، اینٹ اور پتھر کے بے ہنگم اور بد صورت چوکور ڈھانچے۔ ایک سیاہ مستقبل کے خوف نے انور ہوجا کو حال کی سیاہی دیکھنے کی سکت سے مفلوج کر دیا تھا۔ ایک طرف بے ڈھنگے زیرِ زمین ڈبے اور ان کی لاگت، اور دوسری طرف افلاس اور لاکھوں لوگوں کی بے سرو سامانی۔ انور ہوجا کے اس نفسیائی تناؤ کو دیکھ تو سبھی سکتے تھے، مگر کسی کو سوال کرنے کی نہ اجازت تھی اور نہ ہمت۔ کوئی یہ پوچھ نہ سکتا تھا کہ اگر جنگ سے پہلے ہم بھوک ہی سے مر گئے تو بنکر کس کام کے؟ یا پھر یہ کہ البانیہ کو تو اقوامِ عالم میں کوئی پوچھتا بھی نہیں، ہم پر بمباری کاہے کو کرے گا کوئی؟اگر بات دس بیس بنکر بنانے کی ہوتی تو شاید لوگ اسے بھی ایک اور مخبوط الحواس سربراہ کا ایک اورشاہی شوق کہہ کر ہنسی میں اڑا دیتے مگر یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ ۱۹۶۰ اور ۱۹۷۰ کی دہائی میں البانیہ میں ایک لاکھ ستر ہزار بنکر تعمیر ہوئے۔ کوئی کوچہ، کوئی گوشہ نہیں بخشا گیا۔ کچھ زمیں سے قریب تر، اور کچھ انتہائی گہرے۔ کچھ میں ایک خانوادے کے لوگ بھی بمشکل آسکیں اور کچھ اس قدر وسیع کہ سرکار کے پورے دفاتر سما جائیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
تاریخ کے سنگِ میل بدستور چلتے رہے۔ میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے سے جو گزر کرتا تو کئی برس پھلانگ لیتا۔ کچھ کمرے انور صاحب کے ماتحتوں کے تھے، اور کچھ ان کے محافظوں کے۔ یہ سب ان کے ہم خیال بھی تھے اور ہمنوا بھی اور شام ڈھلتے ہی ہم پیالہ بھی۔ محافظوں کے کمروں میں اپنے زمانے کا اسلحہ اور دیگر ہتھیار بھی نظر آئے۔ وہ ماسک بھی موجود تھے کہ جو کیمائی جنگ کی صورت میں اگر بر وقت پہن لئے جائیں تو تنفس کا سلسلہ منقطع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ میں محافظوں کے کمروں سے جو نکلا تو مستطیل راہداری یکایک ایک چوراہا بن گئی۔ بائیں جانب ایک اور راہداری تھی۔ میں اس جانب مڑ گیا۔ چند قدموں کے فاصلے پر یہ راہداری ایک بڑے کمرے میں ضم ہو گئ۔ کمرے میں درجنوں کرسیاں ایک ترتیب کے ساتھ نصب تھیں، اور ان کرسیوں کا رخ ایک اسٹیج کی جانب تھا۔ اس ہال کے دو بنیادی مقاصد تھے۔ اول تو یہ کہ اگر کبھی ایسا وقت آیا کہ باہر حالاتِ حرب بے قابو ہو گئے اور معاملاتِ سلطنت اس مسکن سے چلانے پڑیں تو یہ ہال ایک اسمبلی کا کام دے، اور اگر ایسا نہ ہو تو دل لگی کے لئے اس ہال کو تمثیل اور فلم دیکھنے کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مگر یہاں تفریحِ طبع کا انتظام صرف شاہ کے مصاحبوں کے لئے تھا۔ گو کہنے کو ملک بھر میں نظام اشتراکی تھا، مگر بصورتِ جنگ زندگی کی بقا کے وسائل میں عوام کی شرکت نا قابلِ تصور تھی۔
میں ایک اور جانب مڑ گیا اور تاریخ کے سنگِ میل عبور کرتا اب راہداری کے اس حصے میں آن پہنچا کہ میرے مدِ مقابل اسی شخص کا کمرہ تھا جس کی سوچ اور عمل کی چھاپ نے البانیہ کے خدوخال تبدیل کر دیے۔ راہداری میں موجود تمام کمروں کی شکل و صورت ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ چوکور، سفید اور سرد۔ مگر یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ اس کمرے کے کئی حصے تھے اور دیوار پر زرد رنگ تھا۔ لکڑی بھی استعمال کی گئی تھی۔عوامی لیڈر کے خاص الخاص ہونے کا ثبوت۔ کمروں کے اس جھرمٹ کا ایک بیرونی حصہ تھا۔
بیرونی حصے میں میز اور کرسی سجے تھے، اور ایک سیکرٹری کے کام کرنے کی سہولت موجود تھی۔ پھر ایک اور کمرہ تھا، جہاں پرکچھ صوفے اور میز موجود تھے۔ بوقتِ ضرورت یہاں پر اہم امور پر گفت وشنید بھی ہو سکتی تھی اور عوام کی قسمت کے فیصلے بھی۔ اس کے بعد کامریڈِ اول کا ذاتی کمرہ تھا۔ اس ذاتی کمرے میں ایک بستر تھا جس پر سرخ رنگ کا پلنگ پوش سجا تھا اور اس سے منسلک ذاتی غسل خانہ بھی تھا۔ اس مقام پر ایک عجیب تنہائی تھی۔ ہوا میں اداسی اور افسوس کا عنصر غالب تھا۔ اس وقت میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی اور موجود نہ تھا۔ مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید چار دہائیوں پر محیط دبی آوازیں آج اپنی داستان سنا دینا چاہتی ہیں۔ سالہا سال کے بوجھ تلے عوام کے یاس بھر ے فقرے، امیدوں کے شکستہ ستونوں کے گرنے کی صدا، آنسووں سے پرنم سانسیں، سبھی کچھ اس کمرے میں سنائی دیں۔ مگر نہ تو میرے قلم میں اس قدر طاقت ہے اور نہ ہی میرے دل میں اتنی ہمت کہ ان تمام داستانوں کو دہرا سکوں اور ان مقدس جذبات کا حق ادا کر سکوں۔ میں نے کمرے میں موجود در ودیوار اور سامان پر نظر جمانے کی کوشش کی کہ شاید کوئی پردہ ایسا ہو کہ جس کے اس جانب مجھے اس سوال کا جواب مل جائے جو میرے دل میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون سا ایسا خوف تھا کہ جس کے تسلط نے کئی دہائیوں تک اس خوبصورت دیس کے رئیس الامرا اور ان کے مصاحبوں کی صلاحیتِ اُنس و رحم کو مفلوج کر دیا۔ میں اس روزن کا متلاشی تھا کہ جسے کھول کر میں انور ہوجا اور ان کے ساتھیوں کی سوچ کو سمجھ سکوں۔ مگر یہاں تو کسی روزن کا امکان تک نہ تھا۔ در و دیوار خاموش رہے۔ نہ میرے سوال کا جواب ملا اور نہ کانٹے کی چبھن کا مداوا۔ میں اس کمرے سے باہر آ گیا۔ گو وسیع اراضی پر محیط اس قصرِ تہ ارض میں انور صاحب اور ان کے حواریوں کی باقاعدہ سکونت کی کبھی نوبت نہیں آئی مگر یہ خانہ بزرگ اس سوچ کا مظہر ہے جس نے چار دہائیوں تک ملک کے ہر گوشے میں خوف کا کاروبار کیا اور کیا خوب کیا۔
راہداری میں سورج کا گزر نہ تھا، مگر دل نے کہاکہ اس حصارِ سنگ کے اس پار اب شام ہو چلی ہوگی۔ میرے کوچ کا وقت ہو چلا تھا۔ میں نے مخرج کی راہ لی۔ کچھ اور سیاح بھی راہداریوں سے گزر رہے تھے۔ عمومی طور پر جہاں سیاح ہوں وہاں خاموشی کم ہی ہوا کرتی ہے۔ مگر یہاں پر تمام سیاح میری طرح خاموش تھے۔ شاید اس لئے کہ یہ جگہ لاکھوں لوگوں پر مسلط خاموشی کی یادگار ہے۔ شاید یہاں بات کرنا بے ادبی ہوگی۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے مگر کیا کہیے؟ ن م راشد کہہ گئے تھے کہ
؎بات کہنے کے بہانے ہیں بہت
آدمی کس سے مگر بات کرے؟
باہر آیا تو آسمان کی طرف دیکھا۔ مسکراتا سورج ابھی بھی تمازت سے مبرّا، ملائم روشنی کی چادر لئے کھڑا تھا۔ ہوا میں تازگی کی تاثیر تھی۔ میں نے آزادی کی گہری سانسیں لیں اور شکر ادا کیا کہ اس روز انور صاحب گھر پر موجود نہیں تھے۔