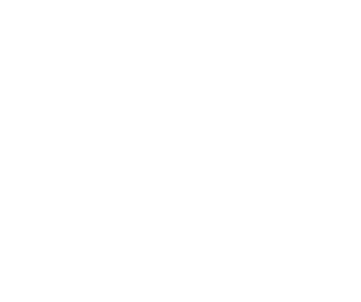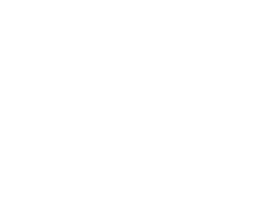ہمارے دو سماج: پیٹر ڈزیکس (ترجمہ:عاصم رضا)
نوٹ: پیٹر ڈزیکس، امریکی شہر بوسٹن میں رہائش پذیر، سائنس سے وابستہ ایک صحافی ہیں۔ ان کا مضمون بعنوان ’’ہمارے دو سماج‘‘ (Our Two Cultures)، 19 مارچ 2009ء کو نیویارک ٹائمز میں شائع ہوا۔ پیٹر ڈزیکس، درحقیقت ، برطانوی سائنسدان و ناول نگار چارلس پرسی سنو (C. P. Snow) کے مضمون ’’دو سماج اور سائنسی انقلاب‘‘ (The Two Cultures and the Scientific Revolutions) کو بنیاد بنا تے ہیں کہ زیرِ نظر مضمون کا عنوان بھی چارلس سنو کے مضمون ہی سے مستعار لیا گیا ہے ۔ ہماری ناقص معلومات کے مطابق ، اگرچہ چارلس پرسی سنو کے انگریزی مضمون کا ایک اردو ترجمہ دستیاب ہے ، تاہم مذکورہ مضمون کسی بھی قسم کی سنجیدہ علمی بحث و مکالمہ سے کم و بیش خارج ہے ۔ چارلس سنو کے مضمون کی علمی اہمیت کے پیش نظر ، پیٹر ڈزیکس کے مضمون کو اردو زبان کے قالب میں ڈھالا جا رہا ہے۔
بہت ہی کم ادبی کلمات ایسے ہیں جنھیں چارلس پرسی سنو (C. P. Snow) کے عنوان ’’دو سماج‘‘ (the two cultures) کی مانند ایک دائمی حیاتِ فردا نصیب ہوئی۔ چارلس سنو نے اس کلمے کو سائنسی و ادبی حیات کے مابین حائل خطرناک خلیج کو بیان کرنے کے واسطے وضع کیاتھا۔ لیکن آج کم ہی لوگ مذکورہ عنوان کی حامل چارلس سنو کی کتاب کو پڑھتے نظر آتے ہیں۔ اگراس کتاب کا مرکزی نکتہ اس قدر واضح ہے تو پھر اس جھمیلے میں پڑا ہی کیوں جائے کہ اسکے قارئین اتنے کم کیوں ہیں؟
1959میں مئی کے مہینے میں انگریز ماہر طبیعیات، سرکاری افسر اور ناول نگار چارلس سنو نے ’’دو سماج اور سائنسی انقلاب ‘‘ (The Two Cultures and the Scientific Revolutions) کے عنوان سے کیمبرج یونیورسٹی میں ایک خطبہ(لیکچر) دیا، جو بعد ازاں کتابی صورت میں شائع ہوا۔ چارلس سنو نوحہ کناں تھا کہ ’’مغربی معاشرے کی تمام تر عقلی حیات (intellectual life ) تیز رفتاری کے ساتھ دو متضاد (قطبی ) گروہوں میں تقسیم ہو رہی ہے‘‘۔ ایک جانب سائنسدان ہیں اور دوسری جانب ماہرین ادبیات (لٹریری سکالر ز) ۔ چارلس سنو نے (جانبین کے مابین) ’’باہمی عدم تفہیم کی کھائی‘‘ کے پیدا ہونے کا الزام ادبی گروہ کے سر ڈالا۔ چارلس سنو نے زور دیا کہ ’’(مذکورہ ادبی) دانشور حرحرکیات (تھرموڈائینمکس)کے دوسرے قانون جیسی بنیادی سائنسی حقیقت کو بھی نہیں سمجھتے اور اپنی اس نافہمی کے بارے میں افسوسناک حد تک لاپرواہی کا شکار ہیں۔ حالانکہ کسی شخص سے اس بابت دریافت کیا جانا ایسا ہی بنیادی سوال ہے جیسے کسی آدمی سے یہ دریافت کیا جانا: کیا آپ نے کبھی شیکسپیئر کو پڑھا ہے ؟‘‘
تقریباً نصف صدی کے عرصہ میں ’’دو سماج‘‘ نامی کلمہ ’’ہر جگہ چسپاں ہونے والا عنوان‘‘ (bumper-sticker) کی صورت اختیار کرچکا ہے، جیسا کہ ناسا (NASA) کے منتظم مائیکل گریفن نے 2007ء کی ایک تقریر میں کہا۔ (ظاہری طور پر، ایک سائنسدان کی حیثیت سے، گریفن نے بھی چارلس کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ چارلس سنو نے ایک ’’بنیادی کلیے‘‘ کا اظہار کیا تھا) اور بلاشبہ چارلس سنو کے موقف کو بعض غیرمتوقع محاذوں پر استعمال کیا گیا ہے۔ 1998ء میں نیوز ویک میں لکھتے ہوئے رابرٹ سیموئلسن (Samuelson) نے خبردار کیا کہ Y2K نامی کمپیوٹر کے متوقع بحران کو سنجیدہ نہ لینے کے حوالے سے ہماری نااہلی، ہو سکتا ہے کہ چارلس سنو کے کلمے کی صداقت کا ’’قطعی ثبوت‘‘ مہیا کر دے۔ (ایسا نہیں تھا)۔ دنیائے علم کے چند نمایاں افراد نے بھی چارلس سنو کی شکایت کو ازسرنو دہرایا ۔ 2001ء میں لارنس سمرس(Lawrence Summers) نے ہارورڈ کے صدر کی حیثیت سے اپنے افتتاحی خطاب میں اعلان کیا، ’’ہم ایک ایسے معاشرے، اور کیا میں یونیورسٹی کہ سکتا ہوں؟، میں زندگی بسر کرتے ہیں، جہاں چند لوگ ہی اس بات کا اعتراف کریں، اور شاید کوئی بھی فخر سے قبول نہ کرے، کہ اس نے شیکسپیئر کے کسی ڈرامے جیسے اہم اور بنیادی متن کا مطالعہ نہیں کیا‘‘۔ البتہ ’’یہ ایک عام اور قابلِ قبول بات ہے اگر کوئی کونیہ (جین) اور لونیہ (کروموسوم) میں فرق نہ کر پائے‘‘۔ یہ جینیاتی دور (DNA age)کے واسطے چارلس سنو کے موقف کا دوسرا جنم تھا، جسے ہارورڈ کے تدریسی عملے(فیکلٹی) نے سرد مہری سے سنا۔
یقیناً، چارلس سنو کے تصور کا حوالہ دینے میں کوئی قباحت نہیں۔ اس کی رائے کو کہ تعلیم کو بہت زیادہ اختصاص (specialization) کا شکار نہیں ہونا چاہیے، آج بھی عمومی طور پر ٹھیک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن چارلس سنو کو ہمارے ٹیکنالوجیکل مستقبل کے عیسوی مبلغ (evangelist) کی بجائے، ایک لولے لنگڑے دانشور طبقے سے تعلق رکھنے والے، ایک عقابی نگاہ کے حامل ماہر بشریات (anthropologist) کی حیثیت سے ذہن نشین کرنا گمراہ کن امر ہے۔ ’’دو سماج‘‘ نامی کتاب کا عمیق نکتہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں دو سماج وجود رکھتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ سائنس ہی وہ شے ہے جو ہماری ترقی اور تحفظ کی سب سے بڑی ضامن ہے۔ اگرچہ اس رجائیت پسندی کے حوالے سے چارلس سنو کا یہ تصورِ ترقی کسی حد تک فرسودہ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ثقافتی زمرہ بندی کے پیمانے پر مذکورہ تصور، زمانۂ حاضر سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔
بہرحال، دونوں سماجوں کی بابت چارلس سنو کی تصویرکشی بہت دقیق نہیں ہے۔ وہ اصرار کرتا ہے کہ سائنسدان ’’اپنے گودے (باطن) میں مستقبل سازی کے امکانات‘‘ رکھتے ہیں، جبکہ ’’روایتی ثقافت کا ردعمل، مستقبل کے انکار کی خواہش استوار ہے‘‘۔ مزید براں ، سائنسدان اخلاقی اعتبار سے ’’درست ذہنی استدلال کے مالک دانشوروں‘‘ میں سے ہیں، جب کہ ادبی اخلاقیات نسبتاً کمزور ہوتی ہے۔ اس کا استدلال ہے کہ ادبی ثقافت، اخلاقی زوال کے ’’عارضی وقفوں‘‘ کی حامل ہوتی ہے۔ وہ اپنے ایک سائنسدان دوست کا حوالہ دیتا ہے جو ایذرا پاؤنڈ، ولیم بٹلر ییٹس اور وینڈہام لیوس کے فسطائی میلانات کا ذکر کرتے ہوئے دریافت کرتا ہے، ’’کیا ان سب کے ادبی اثرات کی بدولت ( یہودیوں کی نسل کشی کے حوالے سے معروف ایک نازی کیمپ) آشوٹز (Auschwitz) نسبتاً زیادہ جلدی حقیقت میں نہیں ڈھل گیا ؟‘‘۔ اگرچہ چارلس سنو تسلیم کرتا ہے کہ ان تینوں مثالوں کا اطلاق ’’تمام لکھاریوں‘‘ پر نہیں کیا جا سکتا، لیکن سائنس کی اہمیت کے بارے میں اس جزوی دفاع کے نتائج واضح ہیں ۔
چارلس سنو کے مضمون نے کیمبرج کے نقاد فرینک ریمنڈ لیاوس (F. R. Leavis) کو اکسایا کہ وہ ایک تندوتیز اور ذاتیات پر مبنی (ad hominem) جواب دے، اور اس نے چارلس سنو کو ’’عقلی اعتبار سے ممکنہ حد تک گھٹیا‘‘ قرار دیا۔ لیونل ٹریلنگ (Lionel Trilling) نے اس مضمون کا ایک نپا تلا جواب دیا، اور لکھا کہ چارلس سنو نے ’’ایک ایسی کتاب لکھی ہے جو بلاشک و شبہ بڑے پیمانے پرسوئے فہم کا شکار ہے‘‘۔ ٹریلنگ کا استدلال تھا کہ چارلس سنو کی (بیان کردہ) ثقافتی قبائلی تقسیم نے’’عقلی بیانیے (ڈسکورس ) کے امکان ‘‘ کو کمزور کر دیا۔
آج، کئی لوگوں کے نزدیک سائنس انسانی صورتحال کو ان طریقوں سے مخاطب بناتی ہے جو چارلس سنو کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ پچھلی دو دہائیوں میں مدیر (ایڈیٹر) اور ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرنے والے جان بروکمان (John Brockman) سائنسدانوں، بالخصوص ارتقائی حیاتیات کے ماہرین ، نفسیات دانوں اور دماغی سائنس ( نیوروسائنس) کے ماہرین کو بیان کرنے کے لیے ایک ’’تیسرے سماج‘‘کے تصور کی پیشکش اور تشہیر کر چکے ہیں۔ وہ سائنسدان جو ’’ہماری زندگیوں کی عمیق تر معنویت کو آشکار کرنے کی خدمت سرانجام ‘‘ دے رہے ہیں اور ’’اپنی نسل کے افکار کی صورت گری‘‘ میں ادیبوں، اور دیگر غیر سائنسی ماہرین پر برتری کے حامل ہیں۔ 1960ء میں خود چارلس سنو نے تجویز دی کہ سماجی علوم کے ماہرین ایک ’’تیسرے سماج‘‘ کو وجود میں لا سکتے تھے۔
چنانچہ چارلس سنو نے کیونکر یہ سمجھا کہ دونوں سماجوں کے مابین حائل مفروضہ خلیج ایک مسئلہ تھی؟ چارلس اپنے مضمون کے آخری نصف حصے میں وہ وجہ بتاتا ہے کہ جس کے کارن بہت سے باصلاحیت اذہان سائنس کو بطور پیشہ(اور طرزِ حیات) اختیار نہیں کرتے (گویا سائنس کی بُلاہٹ(science as vocation) سے دامن بچاتے ہیں، از مترجم)۔ اور یہ طرزِ عمل ہمیں عالمی استحکام کو خطرے سے دوچار کرنے والے دنیا کے ’’بنیادی مسئلے‘‘، یعنی صنعت کاری (Industrialization) کی بدولت غیر مساوی تقسیمِ دولت (ویلتھ گیپ)، کو حل کرنے سے روک دیتا ہے۔ چارلس سنو اس بات کو مزید کھولتا ہے کہ ’’امیر و غریب کے مابین اس تفاوت کو غریبوں نے انتہائی شدت اور فطری انداز میں محسوس کیا ہے۔ اور ایسی تفاوت زیادہ عرصہ تک برقرار نہیں رہ پائے گی۔ اس وقت (یعنی 1959ء) کی دنیا کے کئی ڈھنگ 2000ء تک باقی رہیں گے، مگر امیر و غریب کے مابین تفاوت نہیں‘‘۔ (بعض وجوہات کی بنا پر، Y2K سے متعلق چارلس کی پیشین گوئیاں پوری نہیں ہوئیں)۔ چنانچہ چارلس سنو، جس نے دوسری جنگ عظیم میں کئی سائنس دانوں کو بیرونِ ممالک ذمہ داریاں سونپی تھیں، تجویز دیتا ہے کہ تیسری دنیا کو صنعتی بنانے کے واسطے ماہرین ٹیکنالوجی کے ایک دستے (corps) کو وہاں روانہ کیا جائے ۔
پھر ’’دو سماج‘‘ نامی مضمون اپنے بنیادی موضوع کی طرف آتا ہے، جس کا تعلق عقلی حیات کے مقابلے میں عالمی سیاست سے زیادہ ہے۔ چارلس سنو کا استدلال ہے کہ اگر جمہوری معاشرے غیرترقی یافتہ ممالک کو جدیدیت اور صنعت کاری سے روشناس نہیں کرواتے، تو پھر یہ کام، ’’اشتراکی (کمیونسٹ) ممالک‘‘ کے ہاتھوں سرانجام پائے گا اور یوں مغربی جمہوریت اس دنیا میں محض ایک الگ تھلگ جزیرہ بن کے رہ جائے گی۔ وہ لکھتا ہے کہ ان دونوں سماجوں کے مابین فاصلے کو ختم کرنے کی بدولت ہی ہم تیسری دنیا میں خوشحالی اور خود اختیاری کی ضمانت دے سکتے ہیں ، مستزاد یہ کہ ’’ہمارے پاس بہت مختصر وقت ہے‘‘۔
ان میں سے کچھ باتیں کانوں کو شناسا معلوم ہوتی ہیں؛ کئی دہائیوں تک ہم نے اقوامِ عالم کے مابین مسابقت کی غرض سے سائنس کو ناگزیر سمجھا ہے، ایک تصور جس پر حال ہی میں باراک اوبامہ نے بھی اپنی صدارتی مہم میں روشنی ڈالی۔ تاہم ایک دوسرے تناظر میں ’’دو سماج‘‘ نامی مضمون کا تعلق یقینی طور پر سرد جنگ کے زمانے سے ہے۔ چارلس سنو کی بیان کردہ شاہراہِ صنعت کاری، والٹ وٹمان روسٹو (W. W. Rostow) کے متعارف کردہ تصور برائے ’’مستقل ترقی کی خاطر اڑان بھرنے‘‘ کی پیروی کرتی ہے۔ روسٹو کا یہ تصور 1950ء کی دہائی کے نظریۂ جدیدیت کا حصہ تھا، جو اس بات کا دعویدار تھا کہ تمام ممالک ایک ہی قوسی خط (trajectory) کے مطابق ترقی کر سکتے تھے ۔ عوامی انقلاب کا تصور اور یہ خواہش کہ معاشی ترقی حکومتی عمل دخل سے ہی حاصل ہوتی ہے، دونوں ہی ردِ استعمار (ڈی کالونائزیشن) کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں ، اسی طرح چارلس سنو لکھتا ہے کہ (تیسری دنیا میں صنعت کاری کا) ’’عمل(پروسث) اس قدر بڑے پیمانے پر درکار ہے کہ اس کو ملکی سطح پر ہی انجام دینا پڑے گا۔ نجی ملکیت کے صنعتی ادارے، یہاں تک کہ سب سے بڑے ادارے، بھی یہ کام سرانجام نہیں دے سکتے اور کسی بھی معنی میں یہ ایک ایسا کاروباری خطرہ نہیں ہے جس کا بار اٹھایا جائے‘‘۔
میرے ( مصنف ہذا کے ) خیال میں یہی وجہ ہے کہ چارلس سنو کی تشخیص کو شہرت حاصل ہے جب کہ اس کے تجویز کردہ تریاق کو نظرانداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم اس بات پر اپنے آپ کو قائل کرنے میں کئی دہائیاں گزار چکے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل ترقی، کاروباری مہم جوئی کے اُس سیلِ رواں کی بدولت وقوع پذیر ہوتی ہے جو ناقابل پیشین گوئی ہے۔ اسی سیلِ رواں کی بدولت برپا ہونے والی تخلیقی تخریب میں ہماری تعمیر کی صورت مضمر ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے ، تو چارلس سنو ہمیں ایک چڑچڑے برطانوی ٹیکنوکریٹ کی حیثیت سے ایک نامرغوب (uncool) شخص دکھائی دیتا ہے جو تیسری دنیا کو صنعتی بنانے کے واسطے ایک بہت بڑے حکومتی سطح کے امدادی منصوبے کی دلالی کر رہا ہے (touting) ۔
اس کے باوجود، ’’دو سماج‘‘ نامی مضمون درحقیقت ترقی کے بارے میں ہمارے تصورات میں عمیق ترین الجھنوں کو جامۂ اظہار پہنا دیتا ہے۔ خود چارلس سنو بھی سائنس کی اس آزاد قوت پر یقین کرنے کا خواہاں ہے جو کسی بھی قسم کی سرپرستی کے بغیر دنیا کو بہتری کی طرف لے جائے گی۔ وہ لکھتا ہے کہ صنعتی انقلاب ’’کسی شخص کے بغیر‘‘ وقوع پذیر ہوا، یہاں تک کہ دانشور بھی ’’اس امر کا اندازہ نہیں لگا پائے کہ کیا ہو رہا تھا‘‘۔ تاہم ساتھ ہی وہ یہ استدلال بھی کرتا ہے کہ بیسیویں صدی میں ترقی کی راہ میں شاعروں اور ناول نگاروں کی بے اعتنائی حائل ہو رہی تھی۔ اسی کارن سنو نے ’’دو سماج‘‘ نامی مضمون قلمبند کیا۔ تو معاملہ آخر ہے کیا؟ کیا سائنس تغیر کا ایک کارندہ یا گماشتہ ہے، جسے زیر نہیں کیا جا سکتا، یا پھر کیا سائنس کو ایک ایسے زاویہ نگاہ کی حاجت ہے جو عمومی سے خصوصی (یا صعود سے نزول) (top-down direction) کی جانب روبہ عمل ہوتا ہے؟
مذکورہ سوال پر مبنی ’’دو سماج‘‘ نامی مضمون کی یہی جہت وہ شے ہے جو ہمیں آج کل سب سے زیادہ اپنا مخاطب بناتی ہے ۔(اس سوال کی بابت) آپ کا جواب اور بہت سے دوسرے ممکنہ جواب، غالباً اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ آپ سائنسی علم کی نشرواشاعت کے حوالے سے کتنی وسیع اور عمیق سوچ کے حامل ہیں۔ کیا ہمیں ماحولیاتی تبدیلیوں سے نبردآزما ہونے کے واسطے زیادہ سائنس دانوں اور انجینئروں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو کیسے بروئے کار لانا چاہیے؟ کیا ہمیں حکومتی فعل کی حمایت کے لیے اس مسئلے کی وسیع تر عوامی تفہیم کی حاجت محسوس ہوتی ہے؟ یا پھر ہمیں کسی اور شے کی ضرورت ہے؟
مجھے یقین ہے کہ عمل کی خاطر پکار (call for action)کے حوالے سے چارلس سنو کا بیان، بالآخر اس کے ابتدائی دعووں کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ ’’دو سماج‘‘ نامی مضمون ابتداء میں سائنس دانوں کے اخلاقی امتیازات اور برتری پر زور دیتا ہے، تاہم اس مضمون کا خاتمہ اشتراکیت (کمیونزم) کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سائنس سے مدد لینے کی درخواست پر ہوتا ہے۔ اشتراکیت کے نفوز کا خوف صرف سائنسی سوچ کے حامل لوگوں تک محدود نہ تھا۔ چارلس سنو کے بیان کردو دونوں سماجوں کی (باہمی ) جدائی کا بیان ایک چکنی ڈھلوان کی مانند خطرناک ہے۔ ’’دو سماج‘‘ نامی موضوع پر لکھی گئی کتاب کے مستقل مفاد میں ہے کہ ہمیں محض اسکے حوالے دینے پر بہت ہی کم، اور حقیقی معنوں میں (اس کے مندرجات پر) دوبارہ سے غور و فکر کرنےکے ضمن میں زیادہ وقت صرف کریں۔