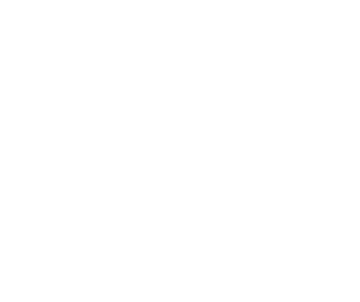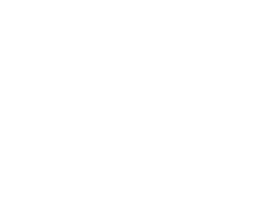انٹرویو، محمدعمر میمن: آبرو احمد خان (مترجم: نجیبہ عارف)
اردو کے صائب الرائے نقاد محمد عمر میمن اردو زبان و ادب کو بین الاقوامی دائرۃ المطالعات میں متعارف کرانے والے ادبیوں میں پیش پیش رہے ہیں۔ وسکانسن یونی ورسٹی، میڈیسن کے ’’شعبۂ مطا لعۂ اسلام اور اردو ادبیات‘‘ میں پروفیسر ایمریطس کے عہدے پر فائز، پروفیسر میمن نے پہلے سندھ یونی ورسٹی میں پڑھایا اور پھر امریکہ آگئے جہاں انھوں نے ہارورڈ یونی ورسٹی سے ’’السنہ و ادبیاتِ مشرق قریب‘‘ میں ایم اے اورکیلی فورنیا یونی ورسٹی ، لاس اینجلس سے ’’مطالعۂ اسلام، بہ تخصّص عمرانیات، تاریخ، عربی و فارسی‘‘ میں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لیں۔۱۹۷۶ء میں موتن، ہیگ سے چھپنے والا ان کا مقالہ، ’’ابنِ تیمیہ کی مروّجہ مذہب کے خلاف جدوجہد‘‘ تیرھویں صدی کے روایت شکن ، حنبلی مفکر ابنِ تیمیہ کے افکار و اعمال کا اولین مطالعہ ہے۔ میمن صاحب ایک مقبول مترجم اورباصلاحیّت افسانہ نگار بھی ہیں۔علاوہ ازیں وہ مجلّہ ’’ادبیات: مشرقِ وسطیٰ کا ادب‘‘ ،کی مجلسِ ادارت و مشاورت کے رکن، آکسفورڈ یونی ورسٹی پریس کی’’پاکستان رائٹرز سیریز‘‘ کے عمومی مدیر اور اردو زبان و ادب کے محققین کے لیے علمی مقالوں، تراجم اور آرا ء کی پیش کش کا وسیلہ بننے والے مطبوعہ و برقی مجلّے ’’سالنامہ درساتِ اردو‘‘ (Annual of Urdu Studies) کے مدیر بھی ہیں۔
میمن صاحب ایک ہمہ جہت ادیب ہیں۔ انھوں نے اردو افسانوی ادب پر کثیر تعداد میں انتقادی مضامین تحریر کیے ہیں جوکئی وقیع پیشہ ورانہ مجلّوں، مثلاً’’ماڈرن ایشین اسٹڈیز‘‘، ’’جرنل آف ایشین اسٹڈیز‘‘، ’’انٹر نیشنل جرنل آف مڈل ایسٹ اسٹڈیز‘‘، ’’ادبیات‘‘ وغیرہ میں شائع ہوئے ہیں۔ انھوں نے معاصر اردو ادب کا بھی خاصا ضخیم حصہ ترجمہ کیا ہے جس کے اب تک کئی مجموعے، بشمول، The Tale of the Old Fisherman, Domains of Fear and Desire, The Colour of Nothingness, An Epic Unwrittenاور Do you Suppose It’s the east Wind? طبع ہو چکے ہیں۔ انھوں نے انفرادی طور پر مختلف افسانہ نگاروں کے انتخابات کے بھی تراجم کیے ہیں جن میں عبدﷲ حسین کی Stories of Exile and Alienation ، حسن منظر کی A Requiem for the Earth، انتظار حسین کی The Seventh Door اور نیر مسعود کی Essence of Camphor اور Snake Catcher شامل ہیں۔ ان کے اردو تراجم میں مغربی اور عرب ادیبوں کے درجن بھر ناول اور صوفیانہ مابعد الطبیعیات اور مسلم فلسفے پر متعدد مقالات شامل ہیں۔ وسکانسن یونی ورسٹی میں اڑتیس (۳۸) برس طویل تدریسی خدمات سر انجام دینے کے بعد وہ ۲۰۰۸ء میں اس ذمہ داری سے سبک دوش ہوئے ہیں اور آج کل ہندوستانی ادیبوں کے افسانوی ادب پر مشتمل ایک جلد مرتب کرنے میں مصروف ہیں۔
پاکستانیات: آپ کے اوائل بچپن کے بارے میں گفتگو کریں ؟ کیا تب آپ کو معلوم تھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیا تب تخلیقی ادب اورتدریس کے پیشے سے وابستہ ہونے کا امکان محسوس ہوتا تھا؟
محمد عمر میمن: میں علی گڑھ میں پیدا ہوا تھا۔ اپنے والدین کا چھے میں سے آخری بچّہ۔ ہمارا گھرانہ قصبے کا واحد میمن گھرانہ تھا۔ کوئی صرف ’’میمن، علی گڑھ‘‘ لکھ کر خط بھیجتا تو ہمیں مل جاتا۔ آٹھ سال بڑی ایک بہن کے سوا، میرے سب بہن بھائی، میری پیدائش کے بعد جلد ہی گھر چھوڑ چکے تھے۔ عمر میں اکیاون سال بڑے اور ہر وقت کسی نہ کسی کتاب میں گم رہنے والے والد کے ساتھ پروان چڑھتے ہوئے میں نے بہت تنہا اور بے رنگ سا بچپن بتایاہے اور ایک مبہم سی اداسی زندگی بھر میرے تعاقب میں رہی ہے۔ اگرچہ میرے کچھ دوست بھی تھے اور ہم اس دور کے ہندوستانی لڑکوں کے عام کھیل بھی کھیلتے تھے۔زندگی کے مختلف ادوار میں، میں متعدد مشغلوں سے اناڑی پن سے الجھتا رہا ہوں، جیسے مصوری، چوب کاری، مکرامے بنانا، منقش موم بتیاں بنانا اور باغ بانی (ایک زمانے میں میرے پاس افریقی بنفشے کی ۱۵۰ اقسام تھیں جن میں سے ایک بھی خریدی ہوئی نہیں تھی، میں نرسریوں سے گرے ہوئے پتّے چنتا یا پھر دوستوں سے قلمیں لیتااورسنگ دودی اور مروارید کاآمیزہ استعمال کرکے انھیں خود بوتا)۔ بہر کیف، گزشتہ بیس برس کے دوران لکھنا، پڑھنا اور باغبانی ہی میری اہم مصروفیات رہی ہیں۔ملازمت سے سبک دوشی کے بعد تو میں خاص عزلت گزیں ہو گیا ہوں۔ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے اس ٹمٹماتی ہوئی سرخ روشنی کے ڈرسے ٹیلی فون کی طرف دیکھنا بھی برا لگتا ہے جس کامطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی کو جوابی ٹیلی فون کرنا پڑے گا۔
میں نے حال ہی میں ایک اور انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ میری زندگی عام سی تھی۔دوسرے لڑکوں کی طرح میں بھی لڑکپن اور نوجوانی کے کئی تجربات سے گزرا ۔اب ان سب کو دہرانا بے معنی ہے، حالاں کہ کچھ دہائیاں پہلے تک، جب مجھے زیادہ شعور نہیں تھا، میں بڑے شوق سے ایسا کرتا ۔اب ایسی باتیں صرف غیر اہم ہی نہیں، بالکل مضحکہ خیز بھی لگتی ہیں۔ کائنات کی اس بے کرانی میں ایک زندگی کی وقعت ہی کیا ہے؟
خیر، صرف آپ کے تجسس کی تسکین کے لیے۔۔۔ میں نے علی گڑھ سے ہائی سکول کا امتحان پاس کیا اور پھر ۱۹۵۴ء میں ہم کراچی منتقل ہو گئے۔علی گڑھ میں گزارے ہوئے کل پندرہ سالوں میں۔ان گرمائی چھٹیوں کے سوا جو ہم اپنے آبائی قصبے راج گڑھ، کاٹھیاواڑ، سواراشٹر(وہی مقام جہاں، میرے نزدیک، مہاتما گاندھی پیدا ہوئے اور علی برادران نے شر انگیزی کے الزام میں کچھ عرصہ جیل کاٹی) اور جہاں ایک گھرمیرے والدین کی ملکیت تھا۔۱۹۴۷ء کی راتیں میری یادداشت پر نقش ہیں۔جب تقسیم ہوئی، ہم راج کوٹ میں گرمیاں گزار رہے تھے۔ جب علی گڑھ لوٹنے کاوقت آیا تو میری والدہ اپنے پاؤں کے ایک چھوٹے سے، پہلے سے طے شدہ آپریشن کے لیے وہیں رک گئیں۔ واپسی کے سفر کے دوران میرے والد مجھے اورمیری بہن کو دہلی ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ کر خود کسی میٹنگ یا کانفرنس میں، جس کا پروگرام پہلے سے بنا ہوا تھا اور ابوالکلام آزاد اس میں ان کی شمولیت پر مصر تھے، شریک ہونے شہر چلے گئے ۔ والد صاحب نے اسٹیشن کو ہمارے لیے زیادہ محفوظ مقام سمجھا تھا۔میں اور میری بہن، ان دو تین گھنٹوں کے دوران ، دہلی کے پلیٹ فارم پر خوف کے ایک پر تشنّج جوار بھاٹا سے گزرتے رہے۔پھر ہم نے علی گڑھ کی ٹرین لی جو بخیر و عافیت پہنچ گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اگلی ٹرین کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا اور چند ایک جانیں بھی ضائع ہوئیں۔میں نے کہا تھا ’’۱۹۴۷ء کی راتیں‘‘۔ اگرچہ علی گڑھ یونی ورسٹی کے علاقے میں فرقہ وارانہ حادثات نسبتاً کم تھے لیکن ہمارے پڑوسی ہر وقت کسی اچانک حملے کے منتظر رہتے تھے اوراسی لیے انھوں نے منظورصاحب کے گھر، جہاں حملے کی صورت میں ہمیں اکٹھے ہونا تھا، کی چھت پر ایک بڑی سرچ لائٹ نصب کر دی تھی۔ ایک روز، صبح سویرے ہمیں بڑی جلدی میں جگایا گیا اور ہم منظور صاحب کے گھر کی طرف بھاگے۔ یہ ایک شدید سردرات تھی۔ مجھے یاد ہے سردی میری ہڈیوں میں اتر رہی تھی اور میں بے طرح کانپ رہا تھا۔ گرم کپڑے پہننے کا وقت نہیں تھا۔ جلدی میں، میرے شب خوابی کے لباس پر ہی ایک اوورکوٹ اڑھا دیا گیا اورمیں سلیپر پہنے ہوئے ہی چل دیا۔ خوش قسمتی سے رات بغیر کسی حادثے کے گزر گئی۔
کیا مجھے اندازہ تھا کہ میں مستقبل میں کیا کروں گا؟ ہاں، کچھ لڑکوں کو بخوبی علم ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں اور ہم ان کی زندگی کی ترجیحات اور کارکردگی کی ایک جھلک پیچھے ان کے ماضی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔میرے لیے تو زندگی محض لمحۂ موجود تھی۔میرا بچپن متشددانہ حد تک تحفظ زدہ تھا۔مجھے تو اپنے دوستوں کے ساتھ گلّی ڈنڈا اور کرکٹ کھیلنا، اسکول سے واپسی پر یونی ورسٹی کے باغوں سے آم اوردوسرے پھل چرانااور تیراکی کرنا پسند تھا۔ مجھے مستقبل کے بارے میں دریافت کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ شاید کوئی ’’مستقبل ‘‘ہو گا مگر اتناہی دور افتادہ اوربعید از دست رس، جتنی پریوں کی کہانی کی شہزادی۔ در حقیقت میں نے کبھی مستقبل پر غور نہیں کیا۔
پیشہ؟ بہت بڑا لفظ ہے۔ مجھے نہیں معلوم! یادش بخیر، میرا خیال ہے میں نے اپنے والد کے نقشِ قدم پر چلنا چاہا ہو گا۔ یہ نہیں کہ میری کوئی مرضی تھی۔ اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی مرضی نہیں تھی۔ بس ایک بے پایاں بے دھیانی تھی۔ ۔۔ مکمل، حقیقی اور معیار بند۔ اس سے آگے کچھ نہیں تھا۔ ایک بار اس میں داخل ہو گئے، پھر یہ خود بخود، اپنی ہی کسی منطق کے تحت، کسی سمت یا مقصد کا تعین کیے بغیر، لیے پھری۔
پاکستانیات: آپ کی تمام تر پیشہ ورانہ تربیت مطالعۂ اسلام سے متعلق ہے لیکن گزشتہ تیس برس کے دوران، اردو ادب آپ کے کام کا مرکزی موضوع رہا ہے۔ آپ اس بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گے؟
محمد عمر میمن: اردو میں ایک کہاوت ہے، کسی کی دکھتی رگ پرانگلی رکھنا۔ آپ نے بالکل یہی کیا ہے۔ میں بچپن ہی سے ان کاموں کا شوقین تھا جو ہمارے ہاں درمیانے طبقے کی روایات میں وقت کا ضیاع (کارِبے کاراں) سمجھے جاتے ہیں: تصویریں بنانا، کہانیاں پڑھنا، شعر کہنا، موسیقی وغیرہ۔ قدرتی بات ہے کہ یہ سب میرے والد صاحب کو، جو ایک راسخ العقیدہ مسلمان اور علی گڑھ مسلم یونی ورسٹی میں عربی ادب کے معروف سکالر تھے، گوارا نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں عربی پڑھوں۔ مجھے یہ سخت ناپسند تھا۔ لیکن کیا میری مرضی چلتی تھی؟ میں بغاوت نہیں کر سکا، سو ادھر ہی چل پڑا۔ ۱۹۵۴ء میں جب ہم پاکستان منتقل ہوئے تو ہندوستان کے سابق صدر ڈاکٹر ذاکر حسین کے بھائی، تاریخ دان محمود حسین اور تاریخ دان ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، دونوں پاکستان کی وزارتِ تعلیم سے منسلک تھے، انھوں نے میرے والدصاحب سے سنٹرل انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ قائم کرنے کو کہا؛ وہی ادارہ ، جہاں بعد میں فیلڈمارشل ایوب خان نے معروف سکالر ڈاکٹرفضل الرّحمان کو ڈائریکٹر تعینات کیا تھا۔ جب میرے والدصاحب یہ ادارہ قائم کرنے اور اس کے کتب خانے کے لیے کتابیں جمع کرنے میں مصروف تھے، اور ابھی تحقیق کا کام شروع نہیں ہوا تھا، تو کراچی یونی ورسٹی نے انھیں، ادارۂ تحقیق کی عملی سرگرمیاں شروع ہونے تک، شعبۂ عربی کی صدارت کی پیش کش کی۔ والد صاحب نے یہ پیش کش قبول کر لی۔ اس وقت میں بی اے کا طالب علم تھا اور اب مجھے کمرۂ جماعت کے رسمی ماحول میں ان کا سامنا کرنا تھا، آپ میری حالت کا اندازہ کرسکتے ہیں۔ لیکن جب وہ ادارۂ تحقیق میں واپس چلے گئے اور ان کے اپنے ہی ایک طالب علم ڈاکٹر سید محمد یوسف کو، جو سیلون (اب سری لنکا) میں پڑھا رہے تھے، ان کی جگہ لینے کی دعوت دی گئی تو میرے حالا ت میں انقلاب آفریں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ ڈاکٹر یوسف بلا کے ذہین تھے۔ انھوں نے عربی ادب کو اس قدرخوش گوار انداز میں پڑھایا کہ یہ مجھے پسند آنے لگا۔ میں کبھی بھی بہت اچھا طالب علم نہیں رہا تھا، تب تک میں کسی نہ کسی طوربس گزارا کرتا رہا تھا۔ اگر پڑھائی کا مطلب ’’عربی پڑھنا‘‘ تھا تو میرا دل اس میں نہیں لگتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر یوسف نے مجھ میں ایسی روح پھونک دی اورمیرے تخیل کوایسی تب وتاب دی کہ میں نے خود کو پڑھائی کے لیے وقف کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں پورے کلیۂ انسانیات میں اوّل آیا۔ بی اے آنرز کا امتحان میں نے امتیازی حیثیت سے پاس کیا اور ایم اے کے لیے وظیفہ حاصل کر لیا جو میں نے ایک سال میں ہی مکمل کر لیا اور یوں گویا میری تقدیرپرمہر لگ گئی۔ اس کامیابی نے میرے مستقبل کے پیشے کا فیصلہ کردیا۔ بغیر کسی اگر مگر کے۔
لیکن اپنی نئی محبت، عربی، کی آب یاری کرتے ہوئے میں نے اپنے پہلے عشق، اردو، کو بھی فراموش نہیں کیا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کی میں کوئی عقلی توجیہہ پیش نہیں کر سکتا۔ اس سارے عرصے کے دوران میں چھپ چھپا کے افسانے لکھتا اور ڈھیروں کے حساب سے افسانوی ادب پڑھتا رہا۔ اس کے بعد کے سالوں میں میں نے کبھی اتنا فکشن نہیں پڑھا، جتنا ان دنوں پڑھ ڈالا تھا۔ کافکا، کامیو، سارتر، سائمن ڈی بوار، ۔۔۔۔موپساں۔۔۔۔ ہیمنگوے، ولیم سرویان،
جس کسی کا بھی آپ نام لیں۔ اور سب سے زیادہ اردو ادیب۔
۱۹۷۰ء میں وسکانسن یونی ورسٹی نے مجھے شعبۂ عبرانی و سامی مطالعات میں عربی اور شعبہ ہندوستانی مطالعات میں فارسی پڑھانے کی دعوت دی۔ تدریس کے دوسرے سال مجھے مؤخر الذکر شعبے سے مستقل طور پروابستہ ہونے اورتدریسِ اردو کی ذمہ داری بھی قبول کرنے کو کہا گیا۔ میرے پاس اردو کی کوئی باقاعدہ سند نہیں تھی۔ یہ فیصلہ کرناخاصا مشکل تھا۔ مطالعۂ اسلام اورعربی کو ترک کر دینا کسی سانحے سے کم نہ تھااور ماضی کو یادکرتے ہوئے کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی دانش مندانہ فیصلہ نہیں تھا۔ لیکن اردو سے میرا لگاؤ فیصلہ کن حد تک ترغیب انگیزتھا۔جب مجھے یہ پیش کش کی گئی تو ہر شے کو ترک کرکے اپنے عشق سے بے حجابانہ ہم کنار ہونے کی آرزوایک وجودی تقاضے کی صورت اختیار کر گئی۔باقی ماندہ داستان سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔
بعد ازاں، میں نے، خود کو مطالعۂ اسلام سے دورنکل جانے سے بچانے کے لیے، اپنے طور پر اسلام، مسلم ثقافت، تصوف، مسلمان معاشروں کے ادب وغیرہ کے موضوعات پر کورس متعارف کرائے ۔بہ نسبت اردو کورسوں کے، جن میں طالب علموں کی تعداد افسوسناک حد تک کم ہوتی تھی، انہی کورسوں نے مجھے فکری طور پر مستعد رکھا۔ ان میں طالب علموں کی حاضری اطمینان بخش ہوتی اور میں نے خود ان کورسوں کی تدریس کے دوران بہت کچھ سیکھا۔
پاکستانیات: نیر مسعود کی Essence of Camphorاور Snake Catcher جیسی تخلیقات ادبی ادغام کی مثالیں ہیں جن کی بین السطور علامت نگاری کے مفاہیم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے قاری کو بہت چوکنا رہنا پڑتا ہے۔کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ایسی تخلیقات پر کام کرنا آپ کے لیے ’’دوہری ترجمہ کاری‘‘ کے مترداف ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو آپ اس ’’دوہری ترجمہ کاری‘‘ سے کیسے نمٹتے ہیں؟
محمد عمر میمن: معاف کیجیے، کبھی کبھی سیدھی سادی باتیں بھی میری سمجھ میں نہیں آتیں۔ مثال کے طور پر، میں ’’ادبی ادغام‘‘ اور ’’دوہری ترجمہ کاری‘‘ وغیرہ کو بالکل نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن مجھے کچھ کچھ اندازہ ہے کہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ میں آپ کے سوال کو غلط نہیں سمجھ رہا۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام اردو ادیب، حتیٰ کہ نیر مسعود بھی، اپنی ہر کہانی کو کسی کنائے یا ایمائی بات سے شروع نہیں کرتے۔ اگرچہ نیر مسعود کی کچھ کہانیوں میں ایسا ہوتا ہے اور وہ اس کی مدد سے کہانی کے مجموعی مزاج اور طرزِاحساس پردھندلی سی روشنی ڈالتے ہیں جو رمز و ایما کے استعمال کا اصل مقصد ہے۔ ظاہر ہے میں ہر رمزیہ سطر کی تمام تر معنوی پہلو داری اور تصوراتی جمال کوجوں کا توں ترجمے میں منتقل نہیں کر سکتا لیکن میں اس کے مفہوم کے ابلاغ کی کوشش ضرور کرتا ہوں۔
پاکستانیات: آپ ادیب کیسے بن گئے؟ کس شے نے آپ کو لکھنے اور اردو ادب کا ترجمہ کر کے اسے بین الاقوامی قارئین تک پہنچانے کی ترغیب دی؟ ایک بے لاگ انٹرویو میں احمد فراز نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ غزل تو چلتے ہوئے تانگے میں بیٹھ کر بھی لکھی جا سکتی ہے لیکن نظم کہیں زیادہ غور وفکر کی متقاضی ہے۔ اسی طرح کیا آپ بھی کسی خاص طرح کے استغراق کا اہتمام کرتے ہیں؟
محمد عمر میمن: میرے لیے ادیب اور مترجم دو مختلف شخصیتیں ہیں۔ یہ دونوں کسی ایک شخص میں بہم ہو سکتی ہیں لیکن ایسا ہونا ضروری نہیں۔ آپ جس قطعیت سے میرے ادیب ہونے کی بات کرتے ہیں، ا سے قبول کرنے میں مجھے تامل ہے۔ ہاں، میں بالکل عام معنوں میں ایک ’’لکھنے والا‘‘ ہوں، جیسے سونی کمپیوٹر کے استعمال سے متعلق پرچۂ ہدایات لکھنے والا ہوتا ہے۔ البتہ ایک تخلیقی ادیب کے مفہوم میں میں اب ’’ لکھنے والا‘‘ نہیں رہا۔ میں نے فکشن لکھنا خاصاعرصہ قبل ترک کر دیا تھا۔ یوں سمجھ لیجیے، میرے اس کرمِ دماغی نے H1N1 وائرس کے سامنے بہت جلد ہتھیار ڈال دیے۔ اب میں اکثر صرف ایک مترجم ہوتا ہوں۔ کوئی شخص ادیب کیسے بنتا ہے؟ اور یہاں ادیب سے میں صرف فکشن نگارمراد لے رہا ہوں۔ یہاں، میں نے ماریو برگس یوساکی ایک چھوٹی سی مسرت انگیز کتاب، ’’ایک نوجوان ناول نگار کے نام خطوط‘‘ سے جو بصیرت حاصل کی ہے، اسے دہرانے سے زیادہ بہترکچھ نہیں کر سکتا۔ ’’لکھنا‘‘ ایک وہبی صلاحیت، ایک الہامی عمل ہے۔ کوئی شخص ادیب ’’بن‘‘ نہیں سکتا؛ وہ ادیب ’’ہوتا‘‘ ہے۔ بہت زیادہ فکشن پڑھنے کے بعد انسان ا س تصنع کو محسوس کرنے لگتا ہے جس سے کوئی لکھنے والا اپنے بیانیہ کی خاکہ کشی کے لیے، افسانوی مواد کو موڑ توڑ کر اسے ایک نقلی، خیالی گھڑت میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس ہشیاری سے وہ یہ جوڑ توڑ کرتا ہے، اسی قدر اپنے لیے ایک منفرد انداز گھڑ لیتا ہے۔
مجھے ترجمے پرکس چیز نے اکسایا؟ میں پاکستان میں بھی ترجمہ کیا کرتا تھا۔ لیکن تب، ترجمہ بھی، تخلیقی تحریروں کی طرح، میرا شعوری انتخاب نہیں تھا۔ میں آپ کو اس کی کوئی وجہ نہیں بتا سکتا۔ یہ سرگرمی میرے شعور کا حصہ زیادہ تر اس وقت بنی جب میں۱۹۶۰ء میں امریکہ آیا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ تب، جب میں نے۱۹۷۰ء میں وسکانسن یونی ورسٹی میں پڑھانا شروع کیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک کے عرصے کے دوران بنیادی طور پر اس کے تین اسباب رہے ہیں؛ عملی، ضروری اور جذباتی۔ وسکانسن یونی ورسٹی میں تراجم کے ذریعے اردو فکشن پڑھاتے ہوئے، مجھے معقول تعداد میں اردو فکشن کے عمدہ تراجم، جو اردو فکشن کا ارتقا خاطر خواہ انداز میں پیش کر سکیں، حاصل کرنے میں دشواری ہوتی تھی۔ موجود مواد زیادہ تر غیر معتبر اور ناقص تھا۔ اس لیے میں نے خود ترجمہ کرنے کا سوچا۔ بعد میں، میں نے ان کہانیوں کو اپنے مجموعوں میں شامل کر لیا۔ (The Tale of the Old Fisherman, Domains of Fear and Desire, The Colour of Nothingness, An Epic Unwrittenاور Do you Suppose It’s the east Wind?) تو یہ تو تھا عملی سبب۔
ضروری سبب ۔ اور یہاں ضروری سے میری مراد وجودی معنوں میں ضروری ہے۔ میری یہ خواہش تھی کہ میں مغربی دنیا کو احساس دلاؤں کہ عہدِ حاضر میں اپنی افسوس ناک کارکردگی کے باوجود، ہمارے تخیل کے نفیس ترین نمونوں میں قابلِ رشک حد تک جرأت مندانہ بے تعصبی کی روح اب بھی موجود ہے۔ انجام کار، اسی بے تعصبی کو ہماری پہچان بننا چاہیے۔ یہی وقت کی آزمائش میں پوری اترے گی۔
خالصتاً جذباتی پہلو یہ ہے کہ مجھے اردو سے عشق ہے۔۔۔ حالاں کہ ہم میمن ہیں اور ہماری زبان گجراتی ہے؛ میری والدہ اپنے انتقال تک درست اردو نہیں بول سکتی تھیں۔ لیکن جذباتی ہونے کے باوجود میرا عشق بے خبر نہیں ہے۔ مجھے جدید عربی اور فارسی ادب پر خاصا عبور حاصل ہے۔ ہمارے اردو نثر نگاروں اور شاعروں نے۱۹۴۰ء تک جو ادبی مقام حاصل کر لیا تھا، ابتدائی عربی اور فارسی ادب میں اس کی کوئی جھلک نہیں ملتی۔ اگرچہ ۱۹۵۰ء کے بعد ہمارا ادبی انحطاط شروع ہو گیا تھا تاہم یہ بات تعجب خیز نہیں ہونی چاہیے کہ جدید فارسی شاعری کا پہلا مجموعۂ انتخاب علی گڑھ کے ایک ہندوستانی نے مرتب کیا تھا اور یہ تب کی بات ہے جب ایران میں جدید شاعری ابھی خود کو معتبر اور نمو پذیر ثابت کرنے کی سعی میں مصروف تھی۔
جہاں تک احمد فراز کے تبصرے کی بات ہے، خیر، یہ بے لاگ ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مبالغے اور بے خبری پربھی مبنی ہے۔ نرم ترین الفاظ میں اسے سادہ لوحی کہا جا سکتا ہے اور صاف صاف کہیں تو ناتجربہ کاری۔ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ غزل ہو، نظم ہو یا افسانہ، سب کے لیے اچھے خاصے تفکر کی ضرورت ہے، جو کبھی کبھی سالوں بلکہ عشروں پر محیط ہوتا ہے۔ انسان تانگے کی سواری کے دوران بھی تفکر میں مصروف رہ سکتا ہے (غالب کبھی کبھی لیٹرین میں شعر کہتا تھا)۔ تانگے میں سواری اور ادبی استغراق (میں اس کی بجائے لفظ ’’تفکر‘‘ یا غور وفکر کو ترجیح دوں گا) باہم متناقض نہیں ہیں۔
میں نہیں جانتا کہ یہ’’ استغراق‘‘ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جانتا ہوں کہ ایک مترجم ہوتے ہوئے بھی، میں کبھی خالی الذہن نہیں رہ سکتا، حتیٰ کی شام کی سیر کے دوران، گاڑی چلاتے یا خریداری کرتے ہوئے بھی، رات کو کیے جانے والے ترجمے کے حقیقی معنوی امکانات تلاش کرنے سے لے کر فلابئیر کے کسی برجستہ نکتے کے لیے کسی مخصوص لفظ کی تلاش میں غورو فکر کاعمل جاری رہتاہے۔ یہاں تک کہ اسلامی ثقافت سے متعلق میرے لیکچروں میں بھی ، فکشن سے اخذ کردہ بصیرت، غیر ارادی طور پر اس طرح ضم ہو جاتی ہے، یا پھرمیں دو دن پہلے ترجمے میں استعمال کیا جانے والا لفظ یوں برت لیتا ہوں کہ خود حیران رہ جاتا ہوں۔ تخلیقی ادیب کے لیے تو اس روش کو سوگنا زیادہ سمجھ لیجیے۔ جب تخلیق کا کیڑا وجود پر حملہ آور ہوتا ہے تو اپنے شکار کی پوری ہستی کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ دونوں ناقابلِ تفریق انداز میں ایک ہو جاتے ہیں۔ اپنی لپیٹ میں لے لینے والے اس گہرے انہماک کا ذکرکرتے ہوئے یوسا اپنے دوست کو Jose’ Mari’a کا اقتباس لکھتا ہے جو ایسے ہی کرمِ تخلیق (پیرِ تسمہ پا) کے ہاتھوں لاچارتھا:
ہم (کرمِ تخلیق اور Jose’ Mari’a ) دونوں بہت سے کام اکٹھے کرتے ہیں۔ ہم اکٹھے تھیٹروں، نمائشوں اور کتابوں کی دکانوں میں جاتے ہیں۔ گھنٹوں، سیاست، کتابوں، فلموں اور دوستوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اور تم سمجھتے ہو کہ میں یہ سب کچھ تمہاری طرح لطف اندوزی کے لیے کرتاہوں؟ تو تم غلط سمجھتے ہو۔ میں یہ سب کچھ ’’اس‘‘ کے لیے کرتا ہوں، اس کرمِ تخلیق کے لیے۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں اپنی زندگی خود اپنے لیے نہیں جی رہا بلکہ اس کے لیے جی رہا ہوں جسے خود اپنے اندر لیے پھرتا ہوں اور میں خود اس کے غلام سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہو سکتا ہے احمد فراز نے اس تخلیق کے کیڑے کو چھٹی کرانے کا کوئی انوکھا طریقہ ایجاد کر لیا ہو۔
پاکستانیات: توآپ نے فکشن لکھنا کیوں چھوڑدیا؟
محمد عمر میمن: اب تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آخر میں نے فکشن لکھنا شروع کیوں کیا تھا؟ اب سے بہت دور، زمانۂ جہالت میں، لکھنا آسان لگتا تھا کیوں کہ لکھنے کا شوق تو تھا لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ اچھا لکھنے کی کیا شرائط ہیں۔ درجنوں کہانیوں میں سے، جو میں نے ان دنوں لکھی تھیں، صرف دو تین ہیں جو عمدہ ہیں۔ باقی سے میں مطمئن نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ میری تحریروں کو پذیرائی نہیں ملی؛ بلکہ یہ اپنے دور کے مؤقر ادبی پرچوں، سویرا، ادبِ لطیف، نقوش، نیا دور، سات رنگ، داستان گو، نصرت اور دیگر میں شائع ہوتی رہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ’’سات رنگ‘‘ میں میری ایک کہانی پڑھنے کے بعد محمد حسن عسکری نے مدیر کے ذریعے پیغام بھیج کر مجھے بلایا تھا۔ شاید انھیں اس کہانی میں کوئی خاص بات نظر آئی تھی اور ان کا خیال تھا کہ وہ میری کچھ رہنمائی کریں گے۔ بلاشبہ انھوں نے مجھے کچھ باتیں سمجھائیں بھی اور چند ایک کتابیں بھی پڑھنے کو دیں جو زیادہ تر فکشن کے فن کے موضوع پر تھیں۔ ۱۹۸۰ء میں، دہلی میں، جہاں مجھے ایک سیمینارمیں مقالہ پیش کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، وقفے کے دوران درمیانی عمر کا ایک آدمی، حاضرین میں سے نکل کر میرے پاس آیا اور کہا کہ وہ کوئی علمی شخصیت نہیں، بس ادب کا ایک عام قاری ہے۔ وہ مجھے صرف یہ بتانے آیا تھا کہ ۱۹۶۰ء میں اس نے میری ایک کہانی ’’تاریک گلی‘‘ پڑھی تھی اور اس سے بہت لطف اٹھایا تھا۔
چناں چہ واقعہ یہ نہیں کہ تنقید کی عد م توجہی یا تحسین و ستائش کی کمی کے باعث تخلیق کے سوتے خشک ہو گئے تھے۔ اب بھی بعض اوقات میں اپنی کسی پرانی کہانی کو کسی افسانوی مجموعے یا انتخاب میں شامل دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں۔
میرے لکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس ملک میں میری پڑھائی تھی۔ لکھنے کے بارے میں تو سوچنے کا بھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعدایک مشقت طلب پیشے کے تقاضے نبھانے پڑے۔ جب میری زندگی کا آہنگ قدرے خوش لگام ہو گیا اورمیں اگر چاہتا تو لکھ سکتا تھا، تب مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں محض ہجوم کا حصہ نہیں بننا چاہتا اور یہ بھی کہ لکھنا ایک بھاری ذمہ داری ہے؛اس کے اتنے بہت سے تقاضے ہیں اور یوساکے الفاظ میں یہ سچ مچ انسان کو جکڑلیتی ہے۔ جوں جوں میں خود کو پرکھتا گیا یہ خیال پختہ ہوتارہا کہ مجھ میں وہ مستقل مزاجی، نظم و ضبط اور استقامت نہیں ہے جو ایک ادیب میں ہونی چاہیے۔ اردو کے چندہی ادیب ہیں جوان معنوں میں پیشہ ورہیں کہ وہ اپنی تحریروں سے کسبِ معاش بھی کرتے ہیں۔ میں نے کبھی ایک پیشہ ور ادیب بننے کا تصور بھی نہیں کیا۔ اس لیے لکھنا ترک کر دینے کا فیصلہ اتنا مشکل نہ تھا۔ کہانی ختم!
پاکستانیات: آپ کے تراجم کے عنوانات میں جو علامتیت پائی جاتی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ مثال کے طور پر ایک مجموعے کا عنوان ہے،Do You Suppose It’s the East Wind? ، اس میں ’’ہوائے شرق‘‘ (East Eind) سے کیا مراد ہے؟
محمد عمر میمن: میرے خیال میں تو کوئی علامتیت نہیں۔ بیشتر عنوانات تو مجموعے میں شامل کسی کہانی کا عنوان ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ خود کہانی کے عنوان میں کوئی باطنی علامتیت موجود ہو، جیسے ہوائے شرق۔ مشرق سے آنے والی ہوا فرحت بخش لیکن اس کے ساتھ ساتھ مغموم اور دلگیر کر نے اور یادوں کو جگا دینے والی بھی ہوتی ہے۔یہ بیک وقت تازہ دم بھی کرتی ہے اور پرانے زخم بھی چھیڑدیتی ہے۔ اسی موضوع پرمرحوم ضمیرالدین احمد کی ایک بہت عمدہ کہانی ہے، ’’پروائی ‘‘ یعنی مشرق کی ہوا۔
پاکستانیات: اردو زبان میں ایک خاص طرح کی خوش بیانی ، فصاحت اور شاعرانہ بلاغت ہے جسے ترجمے میں منتقل کرنا بہت مشکل ہے۔ایک پختہ کار مترجم کی حیثیت سے آپ اس مشکل پر کیسے قابو پاتے ہیں؟ اور کہانی کار یا اس کے کردار کی تمثیلیت، شگفتگی یا دل گدازی کو ترجمے میں کیسے قائم رکھتے ہیں؟
محمد عمر میمن: خاصے سوال اس ایک سوال میں مجتمع ہو گئے ہیں۔بہر کیف، اگرچہ اردو سے مجھے عشق ہے لیکن اس سے متعلق ایک مشکل بھی ہے جو مجھے ہی نہیں، اردو کے تمام ادیبوں کو محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر جب بات جدید فکشن کی ہو اور اس سے بھی زیادہ ، جب فکشن کے ترجمے کا مسئلہ درپیش ہو۔اگر آپ اجازت دیں تو میں وضاحت کر دوں کہ خوش بیانی اور شاعرانہ بلاغت وغیرہ ایسی اصطلاحات ہیں جن کا شاعری پر اطلاق ہوتاہے۔ فکشن، جیسا کہ مغرب میں اسے سمجھا جاتا ہے، اردو میں ایک مستعار صنف ہے۔ یہ، ایک فلسطینی۔اسرائیلی شاعر اور ناول نگارانطون شماس، جو زیادہ تر عبرانی میں لکھتے ہیں، کے بقول، فرد کی تنہائی کی پیداوار ہے اور، اگر میں اضافہ کروں توکہوں گا کہ قاری خود اپنی تنہائی میں اس سے حظ اندوز ہوتا ہے۔ یہ اردو شاعری کی طرح، جس سے مشاعرے کی ایک مستحکم روایت وابستہ رہی ہے، سامعین کے سامنے خطیبانہ انداز میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اردو ابھی تک، خواندگی کے مرحلے میں داخل نہیں ہوئی ہے۔ بڑی حد تک ابھی یہ ’’تقریری‘‘ مرحلے ہی میں ہے۔ اس کی نحوی ساخت بھی تقریری پیش کش کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ دوسری طرف، پڑھی جانے والی چیز لکھاری کوبے پایاں آزادی اور زبان کے لا تعداد امکانات کوپوری طرح برتنے کا موقع، حتیٰ کہ قواعد و رموزِ اوقاف کو بیانیے کی ساخت میں اس طرح مدغم کر دینے کی صلاحیت بھی فراہم کرتی ہے کہ اگر بیانیے کی مخصوص ترتیب کو بدل دیا جائے تو کہانی کامفہوم لازماً متاثر ہو۔ اس میں کان کی نسبت آنکھ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ آواز تو فوراً فنا ہو جاتی ہے، کاغذ پر لکھی گئی تحریرباقی رہتی ہے۔ جملہ خواہ کتنا ہی لمبا اور پیچیدہ کیوں نہ ہو، اگر زیرِ نظر تحریر کی بیانیہ ضرورت پوری کر تا ہے تو، آنکھ اس میں چھپے ہوئے تمام مفاہیم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بار بار اس پر نظر دوڑا سکتی ہے۔ کان بولے جانے والے چند ایک سے زیادہ الفاظ اسی ترتیب میں دہرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے جملے کو کافی مختصر اور نحوی پیچیدگی سے پاک رکھنا پڑتا ہے۔
لہٰذا اگر آپ ناول یا افسانے جیسی اصناف کو اردو میں ترجمہ کرناچاہیں تو اردو کی موجودہ نحوی ساخت، جو تقریری اظہار کے لیے وضع کی گئی ہے، ایک حد تک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ انگریزی کے کسی طویل جملے کو اردو کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں تو منتقل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کامکمل ترجمہ نہیں ہو سکتا جس کا نتیجہ وفور اور شدت کے افسوس ناک نقصان کی صورت میں ظاہرہوتا ہے ۔اس پر طرّہ یہ کہ رموزِ اوقاف کااستعمال بالکل من مانابلکہ غلط ہوتا ہے۔ اردو میں رموزِ اوقاف کے استعمال کے مقررہ اصول نہیں ہیں۔
’’صفت‘‘ کا استعمال ایک اور مسئلہ ہے۔ محمدحسن عسکری نے ایک بار اپنے ایک مضمون میں صفت کے مسئلے کی جانب نہایت خوش اسلوبی اور معقولیت سے اشارہ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہاں انھوں نے اس کی ذاتی و اشتقاقی نوعیت کی بات کی ہے جو اسم کی کسی خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے اور اس ثقافتی (ان کے معاملے میں صوفیانہ) مابعد الطبیعیات کے زیاں پر فریاد کی ہے جس کے تحت اسم، جوہر ہے اور صفت وجودی طور پرمادے اور نفس الامر سے تہی ہونے کی حالت یا خصوصیت کا نام ہے ۔ ان کی اس دلیل سے قطعِ نظر، جو کچھ انھوں نے ’’صفت‘‘ کے بارے میں کہا ہے وہ زیرِ بحث مسئلے پر کچھ روشنی ڈالتا ہے۔
میری ایک اور پریشان کن دقت یہ ہے کہ جب ہم نے فکشن لکھنا شروع کیا تو جدید تجربات اور ان سے پیدا ہونے والے احساسات کے اظہار کے لیے الفاظ ، جو قدرتی طور پر ہمیں ورثے میں ملنے والی اردو میں وجود نہیں رکھتے، وضع کرنے پر(مقتدرہ قومی زبان کی جیسی تیسی کوششوں کے باوجود) توجہ نہیں دی گئی۔ (یہاں تعیینِ قدر نہیں صرف ایک امرِ واقعہ کا بیان مقصود ہے)۔ جدید عربی اور فارسی میں صورتِ حال بہت بہتر ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ عرب اور ایرانی اپنی زبان کے مسئلے پر جھگڑا نہیں کرتے اور نہ اس کے بارے میں کسی احساسِ کم تری کا شکار ہیں جب کہ ہم نے۶۲سال سے آزادانہ حیثیت رکھنے کے باوجود ابھی تک اردو کو اپنی حقیقی قومی زبان کے طور پر نہیں اپنایا۔اب چوں کہ میں نے یہ پنڈورا باکس کھول ہی دیا ہے تو (بتاتا چلوں کہ) ایک اور چیز بھی مجھے بہت تکلیف پہنچاتی ہے اور وہ ہے ؛ایک موزوں، تازہ ترین اور صارف دوست اردو لغت کی غیر موجودگی ۔ میں اردو لغت بورڈ کی مرتبہ اردو لغت کی افادیت سے منکرنہیں ہوں لیکن ذرا ۲۲ ضخیم جلدوں کا تصور تو کیجیے جن میں سے ہر ایک کم از کم ۱۰ پونڈ وزنی اور جسامت میں ہاتھی سے مشابہ ہو۔ یہ عملی طور پر قابلِ استعمال نہیں اور صرف ایک خاص حد تک مفید ہے۔یہاں تک کہ میں نے جمیل الدین عالی، جو ۱۹۹۸ء میں بورڈکے ڈائریکٹر تھے اور ان کے ہر جانشیں سے کہا کہ اس ضخیم لغت کو سی ڈی پر منتقل کرنے کا کچھ سوچیں لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ ہم ایک زیادہ قابلِ استعمال لغت، جوگزشتہ سوسال کے دوران اردو ذخیرۂ الفاظ میں شامل ہونے والے تمام الفاظ کو سمیٹ لے، کیوں نہیں مرتب کر سکتے؟ ہمیں ادبی اصطلاحات کی ایک لغت کی بھی ضرورت ہے۔ ابھی حال ہی میں روجربوس کی، یورپ کی عشقیہ شاعری پر عرب اثرات سے متعلق، ایک تحریرکا ترجمہ کر تے ہوئے، لفظ Courtly Love کو بالکل درست طور پر بیان کرنا میرے لیے دردِ سر بن گیا۔ صرف ادبی اصطلاحات ہی نہیں، ذرا لفظ Calling اور Vocation کا اس مفہوم میں ترجمہ کر نے کی کوشش کیجیے جو یوسا نے پیش کیا ہے؛ یا بہت عام سا لفظ Passion ہی دیکھ لیجیے، آپ کو علم ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ کاش جمیل جالبی صاحب نے، مقتدرہ کے زیر اہتمام لغت مرتب کرتے ہوئے کچھ ایسے افراد کوبھی شامل کر لیا ہوتا جو جدید مغربی فکشن کے تراجم کا تجربہ رکھتے ہیں، جیسے محمد سلیم الرحمان۔
مجھے یہاں اس طرف بھی اشارہ کرنا پڑے گا کہ یہ ’’خوش بیانی ‘‘ اور’’ شاعرانہ بلاغت‘‘ ڈھکے چھپے انداز میں’’مرصع‘‘ ا ور ’’ آراستہ‘‘ کا مفہوم دیتے ہیں ۔ امید ہے آپ نے ان الفاظ کو ان معانی میں استعمال نہیں کیا ہو گا۔ بہرحال ہمیں ایک ایسی خوش بیانی اور بلاغت کی ضرورت ہے جو سادگی اور کفایت کی زائیدہ ہو؛ یعنی واضح، صاف، تراشیدہ، بے تصنع اور اپنی تاثر آفرینی پر اعتماد رکھنے والی زبان۔ اگر آپ ایسی زبان کی کاریگری دیکھنا چاہتے ہیں تو نیر مسعود کے افسانے پڑھیے۔ وہ صفات کے استعمال سے بھی گریزکرتے ہیں اور اس کے باوجودبھرپور قو ت کے ساتھ تاثرمنتقل کر دیتے ہیں۔ ایک اور ادیب جنھوں نے شعوری طور پر انتہائی سادہ زبان استعمال کرنے کی کوشش کی، ضمیر الدین احمد تھے۔
مجھے معلوم نہیں کہ میں کہانی کار اور اس کے کرداروں کی ’’تمثیلیت، شگفتگی اور دل گدازی‘‘ کو قائم رکھنے میں کامیاب رہتا ہوں یا نہیں۔ البتہ مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ میں بھرپور کوشش کرتا ہوں اور اس کے باوجود اپنی ناکامیوں اور مایوسیوں سے بھی باخبر ہوتا ہوں۔
پاکستانیات: ادب میں ترجمے کی کیا اہمیت ہے؟ کیا آپ کے تراجم آپ کی ادبی حیثیت سے متاثر ہوتے ہیں؟ اسی طرح آپ کا ترجمہ، اس ادبی کام سے، جس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں، کتنا متاثر ہوتا ہے؟
محمد عمر میمن: میرا خیال ہے کہ کسی دوسری زبان سے ترجمہ کرنے کا عمل ہمیں دنیا کی، خواہ وہ حقیقی ہو یا تصوراتی، ایک انوکھی بصیرت اور نادر اور غیر متوقع تجربہ عطا کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب میں فکشن نگار نہیں رہا۔ ترجمہ کاری سے میں نے جو اثرات قبول کیے ہیں وہ اسی بات سے واضح ہو جاتے ہیں اور بحیثیت استاد میری کارکردگی میں بھی نظر آتے ہیں۔
فکشن کے تراجم خاص طور پر اردو والوں کے لیے زیادہ اہم ہیں۔ بہت سی اصناف اردو میں مغرب ہی سے آئی ہیں۔ کتنا اچھا ہو اگر ہمارے اردوادیب، براہ راست انگریزی میں نہیں تو، تراجم کے ذریعے ہی سہی، دیکھ سکیں کہ مغرب میں یہ اصناف کتنی ترقی کر چکی ہیں اورخود انھیں ابھی کتنا اور آگے جانا ہے۔ عمدہ نمونے ہمیشہ رہ نما ہوتے ہیں۔ ہیں نا؟
پاکستانیات: اب ایک سوال زبان کی سیساست کے بارے میں! عام تاثر یہ ہے کہ اردو ایک شائستہ، شہری زبان ہے اور اکثر یہ بحث کی جاتی ہے کہ شہری ثقافت کا غلبہ دیہاتی ثقافت کو ارد ادب کا حصہ بنانے کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ایک ادیب کی حیثیت سے آپ ان رکاوٹوں کو کیسے عبور کرتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ نے اپنے انٹرویو میں اردو ادب میں موجود بے تعصبی کی روایات کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ کیا آپ اس بے تعصبی کی روایت کی وضاحت کریں گے؟
محمد عمر میمن: اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بات کے جواب میں انتظار حسین کے افسانے ’’ایک بن لکھی رزمیہ‘‘ کی چند سطریں بیان کروں!، کہانی کا راوی کہتا ہے:
’’چاروں طرف تعمیری ادب کا چرچا ہے۔ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ میں نے ادب میں آج تک کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو تخریبی ہو۔ جب ادیب تخریبی نہیں ہوتا تو تعمیری کہاں سے ہو جائے گا! ادب نہ تو تعمیری ہوتا ہے اور نہ تخریبی ہوتا ہے: وہ تو بس ادب ہوتا ہے۔‘‘ (گلی کوچے، ۲۰۰۷ء، لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنز، ص ۱۴۵)
آپ کونہیں لگتا کہ اس جملے میں دانش مندی موجود ہے ہمیں چاہیے کہ ’’سیاسی‘‘، ’’دیہی ‘‘ اور ’’شہری‘‘ جیسے الفاظ کو ادبی اصطلاحات یا اصناف سمجھنے کی غلطی کی اصلاح کر لیں۔ یہ الفاظ آپ کو جامعات کے نصابی تقاضوں کا پتہ تو دے سکتے ہیں، (روٹی تو کسی طور کما کھائے مچھندر) لیکن ادب کی باطنی حقیقت اور مقاصد سے آگاہ نہیں کر سکتے۔ ایک ادیب لازمی طور پر عمدگی سے کہانی گھڑتا اور ایسی دنیاؤں کی تخلیق کرتا ہے جو کہیں وجود نہیں رکھتیں؛ محض تخیل کی پیچیدہ اوربھول بھلیوں کی سی الجھی ہوئی ساخت میں، ادیب کی موجِ خیال اور اس کے یقین و بے یقینی کے درمیان کہیں ہلکے ہلکے جھلملاتی رہتی ہیں۔ فکشن چوں کہ زمان سے ماورا نہیں ہو سکتا اس لیے وقتِ موجود سے کچھ نہ کچھ مشابہ ضرور رہتا ہے لیکن یہ تخلیقی تحریر کااصل منشا نہیں ہوتا، یہ تو اس کے آلۂ اظہار اور ہیئت کی مجبوری ہوتی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ نثرکی مجبوری ہے۔ میلان کنڈیرا نے اپنے ناولوں کو تاریخ سمجھنے سے منع کیا ہے۔ وہ تو صرف بیانیے کی سرحدوں میں رہتے ہوئے، کردار کی اس وجودی کیفیت کی دریافت کی سعی کرتے ہیں جو اس کی پوری دنیا ہے؛ اس امر سے قطع نظر کہ اس دنیا کی مماثل کوئی دنیا حقیقت میں بھی موجود ہے یا نہیں۔اب اگر کوئی ناول کو سیاست، معاشرے اور الابلا سے متعلق نظریہ سازی کے آلۂ کار کے طور پر استعمال کرنا چاہے تو خیر، اس کی مرضی۔ لیکن یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایسے تجزیاتی عمل کے نتیجے میں کسی تخلیقی عمل کا کوئی چھوٹا سا گوشہ بھی منور ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی میں ادبی تنقید کے بارے میں، جو مجھے اپنی اصل میں اخذ شدہ، اثرپذیر اور اپنے وجودیاتی حجم سے محروم معلوم ہوتی ہے، سوچ کر تعجب کا شکار ہو جاتا ہوں۔ یہ ہمیشہ کسی پیش رو کے عقب میں رہتی ہے، طفیلیے کی طرح۔ زیادہ سے زیادہ ایک احتمالی، مشروط وجود کی صورت۔
لہٰذا جو ادیب کسی شہری یا دیہاتی ثقافت کی عکاسی کے لیے ناول لکھتا ہے وہ بلند پایہ ادیب نہیں ہوتا؛ کیوں کہ کم از کم میری رائے میں یہ باتیں فکشن کا معقول موضوع نہیں ہو سکتیں۔ ہاں یہ اس مقام (مکان) کا کام دے سکتی ہیں جس میں کسی فرد کی کہانی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اب آپ نیر مسعود کو کیا نام دیں گے؟ ان کا منظر نامہ دیہی ہے یا شہری؟ یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو پھر کیا ہے؟ یا پھر اسد محمد خان کی گرما دینے والی، دم بخود کر تی ہوئی ہنرمندی سے بُنی ہوئی کہانی، ’’برجیاں اور مور‘‘ لے لیجیے! یہ کراچی کے ’’ریڈلائٹ‘‘ علاقے کے پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ کیا یہ بڑے شہروں کی ثقافت کے کریہہ پہلوؤں کی کہانی ہے؟ یا پھر آپ اسے سابقہ حقیقی دیوا کی کہانی کہیں گے، ۔۔۔۔۔
مجھے پچھلے دنوں ایک ہندوستانی ادیب کی کچھ کہانیاں پڑھ کر افسوس ہوا جنھیں ان کے فلسفیانہ موضوعات کی وجہ سے بہت سراہا گیا تھا۔ اگر یہی معیار ہے تو پھر فلسفہ ہی کیوں نہ لکھا جائے جب کہ لکھنے والے صاحب خود ایک یونی ورسٹی میں فلسفہ پڑھاتے ہیں! فلسفہ یوں تو کسی کہانی کا موضوع نہیں بن سکتا البتہ کہانی کے مرکزی کردارکی شخصیت کی تفہیم میں ثانوی طور پرمددگار ثابت ہو سکتا ہے بشرطے کہ کہانی کے بیانیہ تقاضے کو پورا کرتا ہو اور قصے کی تعمیر کا تابع ہو، اس پر غالب نہ آجائے۔ پریم چند کی کہانی ’’کفن‘‘ جوا س نے اپنی عمر کے آخری د ور میں لکھی تھی، ہمیشہ میری دلچسپی بیدار کرتی رہی ہے۔ مصنف کے فکشن کو سماجی اصلاح کا آلۂ کار سمجھنے کے نظریے کے برعکس، دونوں مرکزی کردار کسی نہ کسی طرح مصنف کے اعلانیہ مقصدسے منحرف ہو کرایک حد تک آزادی حاصل کر لیتے ہیں۔ دیہی اور جاگیردارانہ منظر نامہ پھر بھی موجود رہتا ہے اور اگر آپ پسند کریں تو اسے غریب اور محروم طبقے کے استحصال کی کہانی سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یوں تو اس میں مصنف کی ظاہر اور پنہاں مقصدیت کو دریافت کرنازیادہ مشکل نہیں، لیکن آخر میں یہ دوبہت منفرد کرداروں کی کہانی ہی لگتی ہے ۔ قاری کے شعور پر ان کی شقاوت اور سنگ دلی کا نقش مرتسم ہو جاتا ہے، ان حالات کا نہیں جو اس کا سبب بنے۔ اگرچہ میرے طلبہ میں سے کئی ان کی حمق زدہ بے مائگی، اخلاقی دیوالیہ پن اوربے دردی سے مایوس بھی ہوتے تھے لیکن کوئی بھی سنجیدہ قاری انہیں شدیدنفرت سے رد نہیں کر سکتا ۔ بس یہی وہ کام ہے جو ایک اچھی تحریر کرتی ہے، یعنی اس کی اخلاقیات پر حکم لگانے کی بجائے، آپ کو اس گھڑت، اس جعل سازی، اس آنکھوں میں دھول جھونکنے کے عمل میں شامل ہو جانے کی دعوت دیتی ہے۔ بالکل ہنگری کے ناول نگار ساندور مارائی کے ناول ’’ایستھر کی وراثت‘‘ کے ایستھر کا سا رویہ، جو ا س کے قاری کا رویہ بھی ہونا چاہیے۔
اردو کے ترقی پسندوں سے میری اصل شکایت اسی بات پر بنیاد رکھتی ہے کہ وہ سماجی حقیقتوں کوزیادہ اہمیت دیتے ہیں اورفرد کی، وقت، تاریخ اور خواہش کے تھپیڑے کھاتی ہوئی پیچیدہ ہستی کو(ادب سے) بالکل خارج کر دیتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں انسان انفرادیت سے محروم ہو کر محض معاشرے کی اقتصادی اصلاح کے آلۂ کار کی ادنیٰ حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ مگر میں ترقی پسندوں کے نہایت اہم کردار کے اعتراف سے منکر نہیں ہوں۔ انھوں نے کم از کم اتنا ضرور کیا ہے کہ اردو افسانے کو اس کی ابتدائی اکتا دینے والی رومانویت سے نکال کر ایک زیادہ مانوس انسانی منظر نامے سے آشنا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، میں یہ بھی کہوں گا کہ، کچھ مسلمہ انفرادیت کے مالک فکشن نگارادیب، جو ابتدا میں ترقی پسندی کے علم بردار تھے، بعد میں ترقی پسندی کے، ادب کو جبراً سماجی مقاصد کی حبس زدہ، بند گلی میں دھکیل دینے کے رجحان کے سبب اس سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ میں ادب کوایک سماجی دستاویزکے طور پر پڑھنے کی بات کو تسلیم نہیں کرتا کیوں کہ یہ کبھی ادب کی علتِ غائی نہیں رہی۔ بلکہ میں تو اسے ادب کے طور پر پڑھے جانے کی تائید کروں گا یعنی انسان کی لذتِ ایجاد کے ایک امکان، اس کے تخیل میں ایک جہانِ غیر موجود کی اختراع اور قاری کو اس اختراع پر ایمان لانے کی شدید ترغیب کے طور پر۔
ایک مرتبہ فکشن کی تخلیق کے پس پشت پنہاں حقیقی مقصد کو سمجھ لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جس شے کو آپ نے ’’دیہی کلچر‘‘ کے نام سے بیان کیا ہے وہ اور اردو فکشن میں ’’شہری کلچر‘‘ کے ہاتھوں دب کر نہیں رہ گئی۔ بہت سے اردو ادیبوں، خاص طور پر پریم چند، نے دیہاتی پس منظر میں افسانے لکھے ہیں۔ حیات ﷲ انصاری اور احمد ندیم قاسمی نے بھی اکثراپنی کہانیوں کی بنت دیہی ماحول میں کی ہے۔
جی ہاں مجھے پورا یقین ہے کہ اردو ادب کی روح میں اساسی طور پر رواداری اور بے تعصبی ہے۔ آپ کلاسیکی شاعری، بالخصوص غزل، پڑھ کر دیکھ لیجیے! کیا ؔ میر، سوداؔ ، مومن ؔ اور غالبؔ میں کہیں تنگ نظر، مذہبی کٹر پن کا، جسے موجودہ زمانے میں بنیاد پرستی کہتے ہیں، کوئی سراغ ملتا ہے؟ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ اردو شاعری میں واعظ، شیخ اور زاہد کی کیا گت بنتی رہی ہے؟ اور غالبؔ ، جو سمجھتا ہے کہ جنت محض اک گمان، اک موجِ خیال ہے جس سے انسان اپنا دل بہلا لیتا ہے اور یہ تمام کائنات، انسان کی غیر متزلزل خواہشِ تسخیر کے لیے قدم بھر کا فاصلہ ہے۔ اگر یہ بے تعصبی نہیں تو اور کیا ہے؟ (آپ جوں ہی تنگ نظرمذہبیت اور طے شدہ نظریات سے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ایمان کو اپنی ارادی قوت اور اختیار پر استوار کرتے ہیں، تو لازماً بے تعصبی کے منطقے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ناول کی صنف تو، میلان کنڈیرا کے بقول، بطورِ خاص اسی لیے ایجاد ہوئی ہے کہ مختلف متقابل سچائیوں کو بیک وقت ایک ہی مقام میں موجود رہنے دیا جائے، بغیراس کے کہ ایک سچائی دوسری کو نابود کردینے کی کوشش میں رہے اور باختن کے الفاظ میں ’’مکالماتی طریقِ کار‘‘ پر، شک و شبہے کا اظہار کیے بنا)۔ یہ سب قبل از جدیدیت کے زمانے کی باتیں ہیں۔ اور اب۔۔۔ خیر، ایک مرتبہ پاکستان جاتے ہوئے، جہاز کے لمبے سفر کے دوران مطالعے کے لیے میں نے اپنے کتب خانے سے دو کتابوں کا انتخاب کیا۔ ان میں سے ایک وٹولڈ گامبرووگز کا ناول Pornographia تھا جسے میں نے ۱۹۶۴ء میں خریدا تھا اورکسی وجہ سے تب تک پڑھا نہ تھا۔ دوسرا ایک نسبتاً تازہ، مختصر ناول L’Abbe C جو جنسی ناول نگار Georges Batailla کی پہلی تخلیق تھا۔ دونوں ایمان اور عدم ایمان کے درمیان موجود کشاکش سے الجھتے ہیں۔ اردو فکشن میں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ اکثر اردو فکشن میں مذہب کا کردار، خواہ وہ کتنا ہی ڈھل مل، متذبذب اور گزراں ہی کیوں نہ ہو، ظاہر نہیں ہوتا؛ لیکن زیادہ ترمغربی فکشن کو پڑھ کر یہ سمجھتے ہوئے گزر جانا، کہ اس میں کسی مذہبی رجحان کی، خواہ وہ تخیلاتی ہو یا تعاملی، جھلک موجود نہیں ہے، مشکل ہے۔ براہ کرم مجھے غلط مت سمجھیے گا! میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مغربی ادب اپنی نوعیت کے اعتبار سے بنیاد پرست ہے یا کسی نوع کی کلیسائی مبارزت کا علم بردار ہے۔ اس تقابل سے صرف یہ مقصود ہے کہ اردو ادب کا ایک وقیع حصہ ان مذہبی مباحث سے بے نیاز رہا ہے جو کسی فرد کی زندگی کی صورت پذیری میں شریک ہوتے ہیں اور انھیں ایک خود مختار بیانیہ کی غایت کی طرف متحرک کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس بات کا تعلق ادب کے اساسی نظریے سے ہے جو مسلم ثقافت میں غالب رہا ہے۔ یہاں ادب حقیقت کی عکاسی اور نقالی کے سوا کچھ بھی ہو سکتا تھا یعنی ایک ایسی سرگرمی جس کی سب سے اہم توجیہہ اور قلم رو محض تخیل ہو۔ ممکن ہے کہ ادب کے متعلق اس رجحان کی تلچھٹ ابھی تک ہمارے ساتھ چپکی ہو۔ مجھے اپنے معاصر ادب سے مایوسی محسوس ہو سکتی ہے لیکن اس مایوسی کا سبب، ادب کی مذہب یا مذہبی موضوعات سے وابستگی نہیں۔
یہ بات تعجب خیزہے کہ مذہب اسلام ہماری روزمرہ زندگی پراس قدرغالب ہے لیکن ہمارے ناول نگاروں میں سے کسی نے ایک ایسا، بڑے پھیلاؤ پر محیط ناول لکھنے کی کوشش نہیں کی جس کے کرداروں کی زندگی میں انفرادی اور مذہبی اخلاقیات کے درمیان تصادم اورکش مکش کی صورت مرکزی حیثیت میں پیش کی گئی ہو جیسا کہ، مثال کے طور پر Batailla کے ناول L’Abbe C میں دو بھائیوں، پادری رابرٹ اورآزاد خیال چارلس کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے (اردو ادب میں) اس پہلو کی عدم موجودگی پر واقعی دکھ ہوتا ہے۔ بے شک میں نذیر احمد کے ناصحانہ ناولوں سے واقف ہوں لیکن وہ مذہبی کش مکش سے واسطہ نہیں رکھتے اور انھیں ایک استثنا سمجھنا چاہیے۔
اردو شاعری نے کئی روایات فارسی سے مستعار لی ہوں گی لیکن اردو زبان خالصتاً ہندوستانی ہے۔ حتیٰ کہ اس کے ابتدائی نام بھی ہندوی، گوجری وغیرہ تھے۔ چوں کہ میں ترجمے کا کام کرتا ہوں اس لیے میں آپ کو ایسی بات بتا سکتا ہوں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس دعوے کے باوجود کہ اردو ایک مسلم زبان ہے (جیسے اس نے مکہ سے وضو کر رکھا ہو) یہ بات حیران کن ہے کہ جان ٹی پلیٹس کی ۱۲۵۹ صفحات پر مشتمل لغت میں، ’’ص‘‘ سے ’’ق‘‘ تک کل آٹھ خاص عربی حروف سے شروع ہونے والے الفاظ صرف ۵۶ صفحات میں نمٹ گئے ہیں جن میں سے کچھ حروف کے الفاظ تو ایک دو صفحات سے زیادہ جگہ نہیں گھیرتے؛ جب کہ صرف ’’گ‘‘ کے الفاظ ۵۲ صفحات پر مشتمل ہیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اردوکا۸۰ فی صد ذخیرۂ الفاظ ہندی الاصل ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ ۱۹۴۷ء کے لگ بھگ اردو کے عظیم ترین ادیبوں میں سکھ اور ہندو ادیب بھی، شامل تھے اور وہ بھی برائے نام تعداد میں نہیں۔ مسلمان ادیبوں کویہ دعویٰ کرتے ہوئے کچھ ذہنی پختگی اور راست فکری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ لسانی قومیت ہے جس کا اطلاق گزشتہ زمانے پر ہوتا ہے۔ بلاشبہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ مجھے آپ کویہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہندوستان میں اردو کی کیا گت بن رہی ہے، جہاں یہ بالآخر ختم ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، لیکن پاکستان میں یہ، اپنے تہذیبی و ادبی ٹھکانوں سے کٹ کر بھی قائم رہے گی۔ کراچی سے آنے والے ایک حالیہ برقی خط میں ایک صاحب نے مجھے لکھا: ’’جی حضور، میں آپ کو اخبارSend کر دوں گا‘‘۔ مستقبل کا غالب اسی زبان میں لکھے گا۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ میں کسی دوسری زبان سے الفاظ مستعار لینے اور انھیں اپنی زبان میں جذب کرلینے کے عمل کے خلاف ہوں، دراصل زبانیں افعال کم ہی مستعار لیتی ہیں۔ زیادہ تر تو اسما اور صفات ہی لیے جاتے ہیں۔ مجھے صرف ’’فلمانا‘‘ یاد پڑتا ہے جو To film کا اردو بدل ہے۔ شاید چند ایک اور بھی ہوں لیکن زیادہ نہیں۔
پاکستانیات: کیا آپ خود کو ایک سماجی حقیقت نگارسمجھتے ہیں جس کا بنیادی مقصد زمان و مکاں کے درمیان موجود رشتے کو بیان کرنا ہو؟ آپ کے تراجم اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت متنوع ہیں۔ آپ ترجمے کے لیے فن پاروں کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟
محمد عمر میمن: میں سماج پسند، حقیقت نگار یا کسی بھی قسم کا ’’نگار‘‘ نہیں ہونا چاہتا۔میں تو صرف فکشن پڑھنے کا خواہش مند ہوں اور وہ بھی حقیقت کی ہو بہو عکاسی کے طور پر نہیں، بل کہ کسی نادریافت شدہ منطقے میں وجود کی کسی جداگانہ روش کی تمثیل کے طور پر۔ چوں کہ اب میں فکشن نہیں لکھتا اس لیے خوش قسمتی سے میں اس بھاری ذمہ داری کی ادائیگی سے معاف رکھا جا سکتا ہوں۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، فکشن کسی نہ کسی حد تک ضرور زمان و مکاں کے سماجی رشتے پر اثر اندازہوتا ہے۔ لیکن یہ اثر ضمنی ہوتاہے، ادب کا منتہائے مقصود نہیں ہوتا۔
دراصل پڑھنا میرے لیے حظ اندوزی کا باعث ہے اور کبھی کبھی جب کوئی چیز پڑھنے میں اچھی معلوم ہو تو اس کا ترجمہ کرنے کوبھی جی چاہتا ہے۔ صاف بات تو یہ ہے کہ اردو ادب کے زیادہ تر تراجم یا تو تدریس کے مقصد سے کیے گئے اور یا پھرمغرب کو جدید اردو فکشن اور اس کے تخلیق کاروں سے واقف کرانے کے لیے۔ اردو میں جن تحریروں کا ترجمہ کیا گیا ہے ان میں یا تو فکشن ہے یا صوفیانہ مابعد الطبیعیات سے متعلق مضامین اور یامسلم۔ یا اگر آپ چاہیں تواسلامی کہہ لیں۔ تہذیب کی ان علمی خدمات کے بارے میں مضامین، جن کی نمود ادب، فلسفے اور سائنس کے شعبوں میں ہوئی۔ ایک اور بڑا سبب اردو محاورے پر دوبارہ عبورحاصل کرنا تھا، جو ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔
پاکستانیات: آپ’’ نو آبادیات‘‘، ’’ مابعد نو آبادیات‘‘ اور’’ تیسری دنیا‘‘، وغیرہ جیسے ادبی عنوانات کے بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گے؟ ان عنوانات سے ماورا کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ ان عنوانات کی کیا اہمیت یا معنویت ہے؟
محمد عمر میمن: مکرر کہوں گا کہ میرے نقطۂ نظر کے مطابق ان میں سے کوئی بھی ادبی تصور نہیں ہے۔ مزید یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ادیب ’’نو آبادیاتی‘‘ یا مابعد نو آبادیاتی ‘‘ ناول لکھنے کا ارادہ باندھتا ہے۔ یہ عنوانات بعد میں وہ لوگ ادب پر چسپاں کر دیتے ہیں جوفن پارے کو اپنے ایک خود مختار تخیلاتی جہان میں نمود پاتے ہوئے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر نیر مسعود کی کہانیوں ہی کو لیجیے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مجموعے ’’سیمیا‘‘ کی پانچ کہانیوں میں سے کوئی ایک بھی کسی معلوم جغرافیائی خطے سے تعلق رکھتی ہے؟ ان کی انتہائی سادہ اور تارتار نثر تہذیبی اعتبار سے مبہم اورغیرمعین ہے، مبالغہ آرائی سے یکسر پاک اور اس کے باوجود تحیرانگیز جذباتی توانائی سے لبریز۔ غیر جذباتی ہوتے ہوئے بھی سرشار کر دینے والی۔ تو پھر آپ ان کے فکشن میں نمودار ہونے والے تخیل زاد منظر نامے کو کس کھاتے میں رکھیں گے؟ کوئی اردو نقاد، کم از کم میری معلومات کے مطابق، ان کے فکشن کے منظر نامے کی معنویت قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوالیکن اس کے باوجود کوئی بھی اس کے تموج آفرین اور مہیب وجودی تاثر کومحسوس کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکا۔ اور آپ کافکا کو کس خانے میں رکھیں گے؟ ہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا فن خارجی حقیقت کا، جو اس کے تجربے میں آئی، ایک ہیجان انگیز رد عمل ہے، لیکن اس خارجی زندگی کا کوئی امتیازی پہلو، قابلِ فہم طور پر اس کی تحریر میں موجود نہیں۔ اورمحمد سلیم الرحمان کی عام سی کہانی ’’سائبیریا‘‘ کے مرکزی کردار منورخان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ایک عام کلرک ہے۔ وہ کسی مبہم مگر مسلسل ذہن کوکھٹکنے والے مہلک خوف کا شکار ہے۔ ایک شام کام کے بعد گھر لوٹتے ہوئے وہ برف کے گالوں کو تواترسے اس شہر میں گرتے ہوئے دیکھتا ہے، جس میں ازل سے کبھی برف باری نہیں ہوئی۔ ایک شہرجومابعد سے آگے کہیں ہے، ایک ایسے ملک میں جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، ایک ایسی صدی میں جو ہماری صدی کے مشابہ لگتی ہے، صرف اس لیے کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں؟ برف کے گالوں کے سوا ہر شے خارجی حقیقت کا عین عکس ہے۔ کسی طاقت ور عدسے سے کھینچی گئی تصویر کی طرح۔ اس کے باوجود جو تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے وہ اس خارجی حقیقت کو ناقابلِ شناخت طور پر مسخ کرتی ہوئی لگتی ہے۔
ماخذ: پاکستانیات