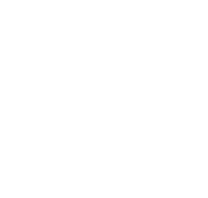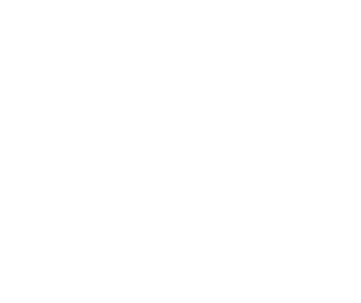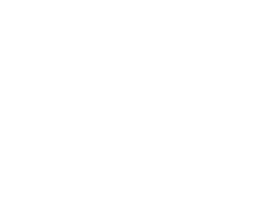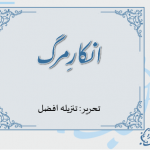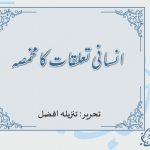مولانا ایوب دہلویؒ: اپنی روایت کے سیاق و سباق میں۔ گفتگو: احمد جاوید (حروف کار: عاصم رضا)
نوٹ: غالباً اپریل 2024ء میں یہ ریکارڈنگ یوٹیوب پر شیئر ہوئی تھی۔ تمام تر پیراگرافنگ اور رموز اوقاف، بعض فقروں کے درو بست میں تبدیلی نیز بعض انگریزی تراکیب کے اردو مترادفات سمیت منجملہ املائی اغلاط کی ذمہ داری حروف کار پر عائد ہوتی ہے۔ احمد جاوید صاحب نے امام غزالیؒ اور شاہ ولی اللہؒ صاحب کے بعد مولانا ایوب دہلویؒ کو شمار کیا ہے جب کہ حروف کار کے نزدیک اس فہرست میں علامہ اقبالؒ کو بھی شامل کرنا چاہیے کیوں کہ علامہ صاحب کے ہاں بھی فلسفیانہ، صوفیانہ اور متکلمانہ روایت کی بیان کردہ تعریفاتِ عقل باہم جمع ہوئیں۔ علاوہ ازیں، احمد جاوید صاحب نے وحدت الوجود کے ذیل میں ’’الموجود واحد‘‘ کا ذکر کیا ہے۔ یادش بخیر، یہ ترکیب ملا علی قاری کے ہاں بھی ہے جس کے مطابق، انبیائے کرام ’’الموجود واحد‘‘ کی تبلیغ نہیں کرتے تھے۔
مولانا ایوب دہلویؒ صاحب، یوں کہہ لیجیے، جیسے ایک بہت مکمل آدمی تھے۔ مطلب، ان کی آدمیت بہت مکمل تھی، اُن کا علم پختہ اور عمل سب سے زیادہ۔ ایسی شخصیت تھے جنھیں دیکھ کر آدمی انہیں اپنا آئیڈیل بنا لے، تو وہ اپنے ساتھ بھلائی کرے گا۔ اِن کے کاموں کی نوعیت تین طرح کی ہے جیسے معروف شاہ صاحب نے بہت اچھا تعارف کروایا: علم کلام، doctrinal tassawuf (نظری تصوف)، اور فلسفہ۔ اِس کے علاوہ یہ اصولِ فقہ کے بہت بڑے ماہر تھے۔ یہ اِن کے جیسے چار میدان ہیں جس میں اُن کا کام بہت پُرزور انداز میں موجود ہے۔
اِن کے کاموں کی اہمیت اور انفرادیت کی طرف بعد میں اشارہ کریں گے، پہلے ہم ایک اصولی بات کر لیں کہ ایسی میٹا فزکس جس کی بنیاد اللہ پر ہے، مطلب (یعنی) اُس طرح کی میٹا فزکس جو کسی مذہبی روایت سے پیدا ہوتی ہے، کسی revealed religion (ابراہیمی مذہب) کی پراڈکٹ (پھل ) ہوتی ہے، تو اِس میں ہمارے یعنی مسلمانوں کے یہاں فلسفیوں اور عارفوں یعنی اہلِ عرفان (gnosticists) صوفیوں اور متکلموں کے درمیان بہت تصادم کی فضا رہی ہے۔
میرے خیال میں (اِس) تصادم کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے عقل کی definition (تعریف)۔ اِن تینوں کے یہاں عقل کی definition مختلف ہے۔ عقل (کو) ایک object (شے) سمجھ لیں اور یہ تینوں اُس ابجیکٹ کو الگ الگ ڈیفائن (تعریف) کرتے ہیں۔ عقل کی ذمہ داریاں، عقل کے حدود، اور عقل کی authenticity (استناد) اِس پر تینوں کی رائے مختلف ہے۔ اب یہ میں میٹا فزیکل (مابعد الطبیعیاتی) مباحث میں کہہ رہا ہوں یعنی ہم پیچھے چلے جائیں۔ عقل کی موجودہ یا Kantian definitions وغیرہ کو اپنے ذہن سے نکال کر ہم کلاسیکی ماحول میں چلے جائیں جہاں میٹا فزکس اور اُس کے حقائق سے ہر ذہن مانوس تھا اور علوم کی تشکیل، خیالات کے بننے کا عمل، چیزوں کو ماننے یا نہ ماننے کے فیصلے، وہ ایک metaphysical essence (مابعد الطبیعیاتی جوہر) کے ساتھ ہوتے تھے چاہے لوگوں کو اُس میٹا فزکس کا rationale (عقلی جواز) نہ معلوم ہو (اور) نہ اُس کا تجربہ ہو۔ لیکن اِس کے باوجود، وہ بنیادی مادہ /وہ بنیادی جوہر جس سے ذہن کی، شخصیت کی اور دنیا کی معنویت (meaningfulness) متعین ہوتی ہے جو سب کے لیے definer کا کام کرتی ہے وہ میٹا فزکس ہے۔ وہ میٹا فزکس جو ایمان کی دین تھی۔ ہماری میٹا فزیکل روایت کو اگر ہم ذرا سہل بنا کر کہنا چاہیں، تو وہ صرف اتنی ہے کہ وہ مسلمانوں کے عقائد کی تفصیل ہے۔ وہ حقائق کی اپنے طور پر دریافت نہیں ہے، بلکہ بتائی ہوئی حقیقتوں کو rationalize (عقلی) کرنا، empiricise (اختباری و تجربی) کرنا، اور اُس کو ماننے میں جس طرح کے یقین کی حالتوں کی ضرورت ہے وہ حالتیں پیدا کر کے دکھانا، اور شعور کی بہترین قوتوں کو ایمانی اثبات کی تائید میں صرف کرنا، اور قلب و ارادے وغیرہ کی بھی مرکزی قوتوں کو اُس بتائی گئی حقیقت سے مانوس رکھنا۔ یہ سارے مسائل تھے۔
اِس میں ہمارے یہاں فلسفہ youngest tradition ہے اور وہ فلسفہ ہمارا ہے بھی نہیں۔ جب ہمارے یہاں یونانی فلسفے وغیرہ کے تراجم ہوئے، تو اُس کے نتیجے میں ایک طرح کی rational metaphysics (عقلی مابعد الطبیعیات) کے مباحث ہمارے علم میں آئے، ہمارے درمیان پھیلے اور اُن مباحث کو (نیز) اُن کی religiosity (مذہبیت) سے قطع نظر، اُن کا خدا مرکز ہونے سے قطع نظر، اِس دعویٰ کے ساتھ قبول کر لیا گیا کہ عقل بھی اُس حقیقت تک اپنے چینل سے پہنچ سکتی ہے جو حقائق پیغمبر بتاتے ہیں (مثلًا، ابن طفیل کا حی ابن یقضان، از حروف کار)۔ یہ ہماری مسلم فلاسفی کا بنیادی ترین مسلمہ تھا۔ اِس کے نتیجے میں ظاہر ہے کچھ مسائل پیدا ہوئے۔ اِس کے نتیجے میں وحی اور عقل کے درمیان جہاں ٹکراؤ ہوتا تھا، وہاں فلسفی عقل کے حق میں وحی کو زبردستی کا بنا دیتے تھے تو اس کو دو طبقات کی طرف سے نوٹس کیا گیا۔
فلسفہ ہمارے یہاں،ہماری روایت میں، ہماری theology (الہٰیات) میں، حتی کہ ہماری belief consciousness (ایمانی شعور) کے جو بنیادی اصول اور حدود ہیں اُن میں ایک تخریبی کردار ادا کرنے لگا تھا۔ اُس پر رَوک لگانے کے لیے دو disciplines (شعبوں/دائروں) کے لوگ اٹھے۔ ایک، متکلم تھے اور دوسرے (gnostic) صوفی۔ اِن میں متکلموں نے اصرار کیا کہ جس عقل کو تم خود self-sufficient (خود مکتفی) سمجھ رہے ہو، جس عقل کو تم حقیقت سے بلاواسطہ correspond (مطابقت) کر سکنے کی قوت مان رہے ہو، پہلے ہم اِس کی کسی تعریف پر متفق ہو جائیں۔ عقل کومتفقہ طور پر define کرنے کے عمل کی ناکامی کے نتیجے میں پھر پورا کلامی ڈسکورس پیدا ہوا۔
ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ عرفانیات میں، کلام میں، اور فلسفے میں عقل کیا ہے۔ اُس کے بعد اِن کے اختلافات کی نوعیت حقیقت میں سمجھ آ جائے گی۔ اِن کے اختلافات ایسے نہیں ہیں کہ صوفی اور متکلم ایک کیمپ میں ہے اور فلسفی ایک مورچے میں ہیں۔ تصوف اور کلام میں بھی عقل کی تعریف میں اختلاف ہے۔
اس میں متکلموں نے یہ مؤقف اختیار کیا کہ عقل، زیادہ سے زیادہ، ایمانیات کو اپنی ذہنی ضرورتوں یا معاشرے میں مروجہ epistemic values (علمی اقدار) کے مطابق ثابت کرنے کی ذمہ داری رکھتی ہے۔ (یعنی) اِس سے آگے اِس کا کوئی کام نہیں ہے۔ عقل، وحی کی ماتحتی سے اگر نکل جائے، تو پھر وحی میں بیان شدہ حقائق جو ہیں اُن کی ماہیت بدل جاتی ہے چاہے اُن کا نام مشترک رہے۔ عقل، وحی سے بے نیازی کی حالت میں، وحی کے contents (موضوعات/محتویات) پر جب اپنے طور پر غور کرتی ہے (نیز) اُن contents کی طرف وہم اور تجزیے کا اپنا راستہ نکالتی ہے، تو پھر یہ گویا ایک ایسا عمل ہے جیسے قرآن عقل کے تجربات کا ایک حصہ ہے۔ عقل کے سٹرکچرز کو بننے کے لیے جو اینٹیں چاہییں اُن میں سے کچھ اینٹیں قرآن میں بھی ہیں۔ تو وحی گویا supportive (معاون) بننے پر مجبور کر دی جاتی ہے۔ وہ جو تخریبی کردار ہے واضح ہے۔ مطلب، ہمارے مسلم فلسفے کی روایت میں جو چیز سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے وہ خدا سے ذہنی، عملی اور اخلاقی تعلق ہے۔ اُس سے تصورِ دنیا اور تصور حقیقت وغیرہ بھی بدل گیا۔ بس وہی جو یونانیوں سے لیا تھا ہم پر لاد دیا گیا۔
جو Godless theology (بے خدا الہٰیات) کی میٹا فزکس تھی اُس میں ہمارے فلسفیوں نے تکلفاً خدا کو بھی شامل کر دیا۔ لیکن وہ خدا کوئی قادر، علیم، مطلق اور حاکم ذات نہیں تھی۔ وہ (درحقیقت) idea of divinity (تصورِ الوہیت ہی) تصور میں personify (مجسم) ہو گیا تھا۔ ہمارے فلسفیوں کی خدا پر گفت گو پڑھیں تو اِس سے زیادہ کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ انہوں نے آئیڈیا (تصور) کو ذہن ہی ذہن میں personify (مجسم) کر دیا اور عجیب عجیب طرح کے مباحث چھیڑ دیے۔ خدا کا علم کیا ہے؟ خدا کی قدرت کی نوعیت کیا ہے؟ خدا کی ذات کا اپنی صفات سے تعلق کیا ہے؟ کیا کائنات کا ذرہ ذرہ اُس کی قدرت کے دائرے میں ہے؟اُس کے علم کے دائرے میں ہے؟کیا اُس کی قدرت ابھی بھی استعمال ہو رہی ہے؟ جاری ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اِس سب میں مسلم فلاسفہ نے جو جوابات قبول کر کے اُنھیں پیش کیا وہ سبھی روایتی مسلم intellect (عقل) کے لیے بھی ناقابل قبول، اجنبی اور destructive (تباہ کُن) تھے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ اُس زمانے کے ایک فلسفی سے پوچھیں کہ عقل کیا ہے۔ وہ کہے گا کہ عقل، غیب کا اثبات کرنے کے لیے، غیبی حقائق کو ماننے کے لیے، اُسے جاننے کی واحد قوت ہے۔ یعنی ماننے میں جب جاننے کی ضرورت آجائے کہ میں جو مانتا ہوں اُس کو جان بھی لوں، تو عقل اِس تقاضے کو پورا کرنے کی واحد قوت ہے۔ مطلب، یہ فلسفے کی definition (تعریف) کا حصہ ہے۔ ٹیکنیکل زبان میں وہ کہیں گے کہ عقل universals کو particularize کرنے اور particulars کو universalize کرنے والی قوت ہے (کُلیات کو افراد /جزئیات میں اور افراد/جزئیات کو کُلیات میں ڈھالنے والی قوت ہے، از حروفِ کار)۔ اب یہ قوت اگر عقل ہے کہ وہ کُلیات کو جزئیات بنا سکتی ہے، جزئیات کو کُلیات سے منسوب کر سکتی ہے یعنی وہ پورا existential (وجودی) اور conscious order (شعوری ترتیب ) بنانے کے لائق ہے۔ (تو) وجود اور ذہن میں تعلق کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ تمام قسمیں ذہن کے حوالے سے عقل کے قابو میں ہیں، عقل کے تصرف میں ہیں۔ عقل کا جانا ہوا ہی مانا جائے گا (نیز) عقل کے مانے ہوئے کو ہی جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ تھوڑٖا paradoxical (متناقضہ) سا ہے لیکن اُن کا پورا ڈسکورس ہے عقل کے بارے میں۔ (یہاں تک کہ) افلاطون سے بھی پوچھتے تو وہ یہی کہتا۔
اب اِس صورت حال میں جو چیز سب سے زیادہ affect (متاثر) ہو رہی تھی وہ ایمان میں غیب پر یقین کرنے والی کیفیت تھی۔ یعنی شعور کو total passivity (مکمل انفعالی حالت) پر رکھتے ہوئے یعنی اِس کی اوریجنل حالت میں رکھتے ہوئے کچھ حقائق کو اِس سے قبول کروا لینا ہے، تیقن کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اور permanence (حضوری) کی فضا میں۔ یہ جو passive (انفعال) شعور ہے جو ایمان کو قبول کر کے اپنی نچلی active (فعال) سرگرمیاں یعنی اپنی activity (فعلیت) کے سب گوشوں کو، سب قوتوں کو، سب مقاصد کو ایمانیات کے تابع رکھتا ہے۔ کیوں کہ passive (انفعال) شعور ہی میں ideas of consciousness (تصوراتِ شعور)، methods of consciousness (شعوری طریقہ ہائے کار) سب ہیں۔ جتنا active consciousness (فعال شعور) اپنے passive consciousness (انفعال شعور) کے مرتبے میں موجود آئیڈیاز اور مسلّمات کو دکھائی دینے والی چیزوں کے ساتھ تعلق میں ایک فیصلہ کن قوت کی طرح برقرار رکھتا ہے تو وہاں متکلمین اور صوفیاء دونوں کے نزدیک، گویا عقل اپنے حقیقی دائرے میں ہے۔ عقل پھر اپنی حقیقی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے کہ passive consciousness (انفعالی شعور) میں موجود آئیڈیاز کو conceptualize بھی کر رہی ہے، actualize بھی کر رہی ہے، اور اُن سے بیک وقت علم بھی پیدا کر رہی ہے جسے اسے بدلتے رہنا ہے۔ اور اُسے عقیدے میں جسے کبھی نہیں بدلنا، پختگی کےنئے نئے رنگ پیدا کرنے ہیں۔
یہاں تک سب مانتے ہیں عقل کو۔
آپ ذرا سا بھی غور کریں کہ اگر فلسفیانہ نقطۂ نظر ہی سے دیکھیں تو شعور کی passivity (انفعالیت) یعنی original consciousness (اصلی شعور) کو شامل کیے بغیر، اِس کو شعور کی دیگر active faculties (فعال قوتوں) پر غالب رکھے بغیر، میٹا فزکس پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ میٹا فزکس pure transcendence (خالص تنزیہہ) کا ادراک ہے / اثبات ہے اور اُس transcendence (تنزیہہ) کے ساتھ transcendent real (حقیقی باعتبار تنزیہہ) یا reality (تنزیہی حقیقت) کی جو manifestation (ظہور) کا پورا ایک نظام ہے جس کو عقل دریافت کرتی ہے اور اُسے بدلتی رہتی ہے۔ اُن کی ترتیب بدلتی رہتی ہے۔
جب یہ ہونے لگا کہ جو اپنے ایمان پر دلیل نہیں رکھتا اور دلیل بھی Aristotelian logic (ارسطالیسی منطق) کے مطابق، تو اُس کا ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو پھر متکلمین نے کہا کہ فلسفی عقل کو جو جگہ دے رہے ہیں وہ جگہ خدا کی ہے۔اُنھوں نے عقل کو گویا حجت مان کر اُسے الوہیت کی کرسی پر بٹھا رکھا ہے چاہے یہ اُسے یہ نام نہ دیں۔ لیکن اس میں ساری حاکمیت عقل کی ہے۔ اِس پر اُنھوں نے عقل کی clinical definition اور حدود دریافت کرنے کی کوشش کی کہ عقل بالقوۃ یعنی potentially، reason as such (عقل فی نفسہ)، یہ کیا ہے؟ اِس کے حدود کیا ہیں؟ اِس کا کام کیا ہے؟ اور شعور کے کن projects (منصوبوں) میں اِس کی حیثیت سند کی ہے یا اِس کی حیثیت ماننے والے کی ہے؟ شعور کے بہت سارے project (منصوبے) ہیں، شعور کے بہت سارے احوال ہیں تو اُن میں سے بعض احوال جو ہیں وہ اپنی verification (تصدیق) اور justification (توثیق) عقل سے مانگتے ہیں۔ عقل اگر انہیں verify اور justify کر دے تو گویا وہ مجموعی شعور کا قبول کردہ content (مواد) بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر عقل انہیں رَد کر دے تو وہ مجموعی شعور جو ہے جس کا عقل محض ایک حصہ ہے وہ اُس پراجیکٹ کو تَرک کر دیتا ہے۔ لیکن انہی projects (منصوبوں) میں، conscious states (شعوری حالتوں) میں کچھ ایسے بھی ہیں جن میں عقل کا کردار حَکم کا، حجت کا، فیصلہ کرنے والا کا نہیں ہے۔ وہاں عقل رہبر ی نہیں ہے۔ وہاں عقل صرف کمنٹیٹر (مبصر/ شارح) ہے۔ جیسے ایک کھیل ہو رہا ہے، عقل اس کی کمنٹری کرتی ہے اُس کھیل کے قوانین، form (بنتر)، اور نتائج کو ذرا برابر تبدیل کیے بغیر اور کسی کھلاڑی کا کوچ بنے بغیر۔ کمنٹیٹر کسی کھلاڑی کا کوچ نہیں ہوتا، وہ کھیل کے اصول پر اثر انداز نہیں ہوسکتا۔ بلکہ اُسے کھیل کے اصول کو ماننا چاہیے جبھی وہ اچھی کمنٹری کرے گا۔ وہ کسی کھلاڑی کو تربیت نہیں دے سکتا۔ وہ کسی کھلاڑی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ایسے کھیلو ویسے کھیلو۔
اِن state of consciousness (شعوری حالتوں) میں primary states (بنیادی حالتیں) ہیں جو higher states of consciousness (اعلی شعوری حالتیں) ہیں۔ اِن میں عقل کا کردار محض passive (انفعالی) ہے اور ایسی passivity (انفعالیت) کے ساتھ ہے کہ عقل اِن اصولِ علم کو، اِس principles of cognition اور affirmation کو مانے (نیز) انہیں مان لینے کے نتیجے میں اپنی تمام سرگرمیوں میں انہیں مرکزی قوت کے طور پر استعمال کرے۔ یعنی عقل کو prior perspective (ماقبل تناظر) کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل کو جاننے ماننے، ہونے، نہ ہونے کی جو سچویشنز ہیں جو بالکل یونیورسل سچویشنز ہیں، یہ آئیڈیاز عقل کو اُن کے معنی سجھاتے ہیں۔ یہ عقل کو پابند رکھتے ہیں کہ وہ کائنات سے تعلق میں جو علم کا flow (بہاؤ) آتا ہے اُس کو قابو میں رکھے اور اُس میں یہ فیصلہ کرے کہ مجھے کیا چیز رَد کرنی ہے اور کیا چیز قبول کرنی ہے، کس چیز کی طرف متوجہ رہنا ہے کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے، اِس cosmic situation (کائناتی صورت حال) میں، اِس psychic situation (نفسی صورت حال) میں۔ یعنی وجودی کنڈیشنز بن جانے والی چیزوں میں۔ وہ جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ رَد و قبول کا، وہ فیصلہ خود نہیں کرتی۔ وہ فیصلہ مدلل بنا کر اپنے اور اپنے objects (محتویات) پر apply (لاگو) کرتی رہتی ہے۔
جیسے علم کے لیے ایک پیشگی perspective (تناظر) ضروری ہوتا ہے۔ علم خلا میں نہیں پیدا ہوتا۔ علم ایک مقصد سے اور ایک apriori idea (ماقبل قیاسی تصور) سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا جو تصورِ علم اور مقصدِ علم ہو گا، دوسری چیزوں کے بارے میں آپ کا علم اُس کا پابند ہوگا۔ اگر ہم اپنے conscious order (شعوری نظم) کو اِس کی صحیح ترتیب اور hierarchy (مراتب) میں دیکھیں تو ایسا ہو گا۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عقل جو علوم کا نقشہ بناتی ہے اُس نقشے پر عمارتیں بناتی ہے، یہ کسی prior perspective (ماقبل تناظر)، کسی binding perspective (لازمی تناظر) اور کسی metaphysical semantic (مابعد الطبیعیاتی معانی) سے آزاد رہ جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ عقل کا جو بھی حاصل علم کی صورت تیار کرتا ہے، ذہن کا فیصلہ بنتا ہے۔ یعنی عقل رد یا قبول کا فیصلہ کرتی ہے اور اپنے objects (محتویات) کے معنی مقرر کرے۔ یہ اگر اُن کو اپنے بنائے ہوئے نظام وجود میں ڈھالے گی تو پھر یہ اپنے ہر object (محتوی) کو corrupt کرے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ عقل میں خود ایک idea of existence (تصورِ وجود)، idea of reality (تصورِ حقیقت)، idea of meaning (تصورِ معانی) پہلے سے اُس کے passive portion (انفعالی حصے) میں موجود ہو او ر وہ اِس لیے ہو کہ یہ ایسی چھتریاں ہیں جو فلاں طرح کی بارش ہو رہی ہو تو اس طرح کی چھتری کے ساتھ نکلنا۔ اور دوسری طرح کی بارش ہو رہی ہو تو کس چھتری کے ساتھ نکلنا۔ اُن چھتریوں سے بے نیازی کی حالت میں عقل اپنے موضوعات میں جو بلحاظِ وجود metaphysicality ہے اُس کا ادراک نہیں کرسکتی۔
اِسی وجہ سے ہماری روایت میں بھی خاص طور پر اور تقریباً تمام traditions میں، حتی کہ آج بھی یہ بات خاصی مضبوط معلوم ہوتی ہے کہ جاننے کا پورا process اپنی بنیاد میں میٹا فزیکل ہے۔ ہونے کا سارا نظام اپنے جوہر میں مابعد الطبیعی ہے۔ یعنی موجود، وجود کے تصور سے جڑا ہوا ہے اور وجود ایک میٹا فزیکل تصور یا مسلّمہ ہے۔ اسی طرح ہر چیز اپنے essence (جوہر) کے ساتھ میٹا فزیکل ہے۔ اپنی form (بنتر) میں فزیکل ہوتے ہوئے in itself (فی نفسہ) میٹا فزیکل ہے۔ کیوں کہ وجود کا نظام metaphysicality کے جوہر کے بغیر ممکن نہیں ہے تو علم یعنی وجود کا ذہنی ورژن یہ metaphysicality کے بغیر کیسے ممکن ہے۔ جیسے اگر نوجوان لوگوں کو یا نئے لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہو، تو چیز کا نام entified نہیں ہے۔ نام وجود نہیں ہے۔ وجود وہ ہے جس کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ نام اُس وجود کی تعریف کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ نام اُس وجود کو سمجھنے کا واحد دروازہ ہےاور یہ نام اُس وجود کے تجزیے کے نتیجے میں پیدا ہو جانے والے اختلافات سے بھی متاثر نہیں ہوتا۔ آپ نے میز کو صحیح سمجھا، میں نے غلط سمجھا۔ لیکن ہم دونوں میز کے نام پر متفق ہیں۔ (یعنی) علم کی تشکیل کا سارا عمل metaphysicality کے ساتھ ہے۔ خود معنی (meaning) کا جو وجود ہے، ہمیں گویا experience (تجربہ) کرواتا رہتا ہے۔meaning of thing (شے کا معنی) نہ شے کی ملکیت ہے، نہ ذہن کی ایجاد ہے۔ معنی ایک ایسی transcendence (ماورائیت) رکھتا ہے، ایک ایسی transcendence (ماورائیت) کے ساتھ ذہن میں موجود ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم جانتےہیں کہ یہ ہماری تخلیق نہیں ہے۔ یہ ہمارے شعور میں مادۂ شعور کے طور پر اِس کی حرکت کرنےسے پہلے رکھ دیا گیا ہے۔ تو خود معنی میٹا فزیکل ہوتا ہے۔ میٹا فزیکل ٹچ نہ ہو تو معنی غائب ہو جائیں (یعنی) معانی ذہن میں جگہ ہی نہیں پا سکتے۔
خیر، یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو متکلمین اور صوفیاء کے نزدیک قابلِ قبول ہیں جس میں صوفیاء اور متکلمین کی range (پھیلاؤ) میں فرق ہے، بعض مقاصد میں فرق ہے، لیکن definition میں فرق نہیں ہے۔
فلاسفہ کے اس مؤقف پر کہ عقل حق اور حقیقت کی تحقیق کا واحد ٹول ہے، متکلمین نے یہ کہا کہ نہیں، علم تابعِ معلوم ہوتا ہے لہٰذا عقل پر بھی کوئی binding (واجب) ہونی چاہیے۔ کوئی آئیڈیا، کوئی text (متن) binding ہونا چاہیے۔ اُسے قبول کرنے میں عقل کی تنقیدی نظر کام میں نہیں آنی چاہیے۔ اِس کا مطلب یہ تھا کہ عقل وحی کے تابع ہے اور وحی و عقل کے فہم میں اگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا، تو عقل کا مؤقف ترک کیا جائے گا۔ یہ متکلمین نے کہا اور اِس میں انہوں نے بڑے بڑے کمالات دکھائے یعنی فلسفہ دانی کے بھی بہت بڑے بڑے کمالات ہمارےیہاں متکلمین میں دکھائی دیتے ہیں۔ اُس میں متکلمین نے جیسے عقل کو clinically analyze کیا کہ عقل ہر صورت میں اپنے ہر کام میں کسی ذریعہ کی محتاج ہے۔ دنیا کی چیزوں کے تعقل میں یہ حواس کی محتاج ہے۔ اسی طرح میٹا فزیکل مباحث میں حقائق غیبی کے ادراک میں یہ وحی کی محتاج ہے۔ یہ نبی کی طرف سے دی گئی خبر کی محتاج ہے۔ یہ کسی بھی revealed divine text (الہامی مقدس متن) کی محتاج ہے۔ اِس کے بغیر یہ دونوں دائرے میں قدم رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ یعنی حواس نہ ہوں تو عقل اور دنیا کا تعلق، forms (بنتروں) کا تعلق نہیں قائم ہو سکتا۔ اسی طرح divine script (مقدس متن) نہ ہو اور وحی کا حامل نبی نہ موجود ہو، تو عقل جو ہے وہ حقائق سے مناسبت یا حقائق کا تصور بھی نہیں باندھ سکتی۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ عقل میں حقائق کا تصور ہی وحی سے آیا ہے۔ ورنہ عقل جو تھی وہ صرف یہ ہے کہ یہ ایسا ہے تو کہیں یہ ویسا نہ ہو۔ یہ سورج بہت بڑا ہے، کہیں یہ اصل حقیقت نہ ہو۔ وہ تو جب وحی آئی اُس نے بتایا کہ اصل حقیقت transcendence (ماورائیت/تنزیہہ) ہے اور transcendent correspondence (ماورائی مطابقت) میں ہے۔ عقل یہ سمجھ ہی نہیں سکتی کہ بیک وقت reality اور form میں transcendence، اور immanence، اور correspondence کیسے جمع ہو سکتی ہیں۔
اِس میں متکلمین نے عقل کی تعریف وضع کی اور اُس میں کوشش کی کہ فلسفیوں سے زیادہ فاصلہ نہ پیدا ہو، تاکہ logic (منطق) مشترک ہو جائے۔ استدلال کا طریقہ ایک رہے۔ اِس تعریف کے ساتھ انہوں نے فلسفے کے جو rational (عقلی) دعوے ہیں یعنی rationalism (عقلیت پرستی) کو انہوں نے دعوت دی کہ تم جس منطق پر فُلاں چیز کا انکار کر رہے ہو، آؤ ہم تمہاری ہی بنائی ہوئی منطق کے مطابق ثابت کرتے ہیں کہ تمہارا انکار غلط ہے اور بے عقلی ہے۔ یعنی صرف اِتنا نہیں کہ یہ خلافِ دین ہے، خلافِ قرآن ہے۔ اِس میں متکلم مفتیانہ کردار نہیں اداکر رہا، وہ بین السطور چلتا رہتا تھا کہ خلافِ قرآن ہے۔ انہوں نے فلسفیوں کے ساتھ ایک ایسا مباحثہ اور مکالمہ شروع کیا اُن کی تردید کرنے کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے کہ جس مکالمے کی شرائط فلسفیوں کی قبول کی گئی ہیں۔ یعنی عقل کی definition فلسفیوں کی مان کر، اُسے فرض کر کے ان سے کہا گیا کہ اسی definition کے مطابق ہم تم پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ تمہاری defined عقل جہاں فیصلے کرتی ہے وہاں اکثر بے عقلی کی مرتکب ہوتی ہے۔ تمہارے جو تصور میں موجود عقل ہے وہ عمل میں موجود ہونے کے لائق نہیں ہے۔ وہ خود کوئی طاقت نہیں ہے۔ بلکہ وہ اپنی کمزوری پر راضی رہنے کے لیے طاقت کا ایک تصور ہے۔ اِس لیے علم کلام کی تعریف یہ کی گئی کہ عقل کے انکار کو عقل ہی کے نظامِ استدلال کے مطابق اقرار میں بدلنا۔ دین کا عقل جہاں جہاں انکار کرے گی کُلی یا جزوی، تو اُس کا اسی عقل کی مدد سے دفاع کر کے دکھایا جائے گا۔ یہ ہے علمِ کلام۔
مولانا ایوب دہلویؒ کے بقول، متکلمین نے علم کلام کی یہ تعریف کی ہے۔ ’’کلام وہ علم ہے کہ جس سے دلائل کے ذریعہ سے عقائدِ دینیہ کے اثبات پر اور اُن پر جو شبہات ہوں اُن کے ابطال پر قدرت حاصل ہو جائے‘‘ (مقالات ایوبی، جلد اول)۔
جو میں نے پہلے عرض کیا، وہ اِسی کی تفصیل ہے مختلف لفظوں میں۔
اب معاملہ یہاں تک نہیں رُکا۔ یہ تو ہو گیا کہ متکلمین نے فلسفیوں کو ہماری جو rationality (عقلیت) ہے اُس کو زیادہ توڑنے پھوڑنے نہیں دیا۔ فلسفیانہ rationalism (عقلیت پرستی) چاہے وہ یونانی ہو یا معتزلہ کا ہو، اُن کو mainstream میں داخل نہیں ہونے دیا۔ یہ متکلمین کا بڑا کام ہے۔ لیکن خود متکلمین کے یہاں کچھ مسئلے تھے، کچھ کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں۔ یعنی عقل کو رَد کرتے کرتے اِ ن کے اندر شعور کی جو virgin (خالص) ایمانی ساخت ہے وہ متاثر ہو گئی۔ مطلب، اپنے دلائل پر اُنھیں عقیدے کی عبارت سے زیادہ اعتقاد پیدا ہو گیا تھا اور عقل کی حاکمیت یا عقل کا بہت مرکزی ہونا اِن کے اندر بھی سرایت کر گیا تھا۔
اُس کو جواب دیا ہے صوفیاء نے۔ یعنی متکلمین نے فلاسفہ کی تردید کی اور صوفیاء نے متکلمین کو رَد کیے بغیر اِن کے اندر پیدا ہو جانے والی کمزوریوں کی نشان دہی کی۔اُس روایت کو بھی ساتھ ہی ساتھ یعنی مسلم rationality یا مسلم فکری روایت جو بھی نام دیں، وہ صوفیوں کو شامل کیے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی۔ صوفیوں نے تردید کا مؤقف اختیار کیے بغیر یہ گویا دکھا دیا کہ فلسفی ہوں یا متکلم ہوں، دونوں کا معقول یعنی عقل کا مانا ہوا وجود اور اُس وجود کو ماننے کے لیے عقل کے مسلمہ دلائل، یہ غلط نہیں ہیں۔ ناقص ہیں۔یہ آدھی باتیں کہتے ہیں۔ آدھی بات یہ اِس لیے کہتے ہیں کہ عقل کو انسان کی property (صفت) سمجھتے ہیں۔ اب یہ وہی جو میں نے کہا کہ عقل کی تعریفات ذہن میں ہونی چاہییں۔ تو صوفیوں نے عقل یعنی Reason کو divine intellect (الوہی دانش) سے گویا organically (نامیاتی اعتبار سے) جوڑ دیا۔ یعنی انہوں نے انسانی عقل کو divine intellect (الوہی دانش) کا ایک معمولی سا مظہر بتایا۔ وہ عقل جو غیب کا ادراک کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، جو اللہ کو ماننے کی قوت رکھتی ہے،ماننے کی ایسی قوت جو اُس ماننے کو مدلل بھی بنا دے، وہ عقل انسان کے حصے میں بہت تھوڑی آئی ہے۔ انسانی عقل جسے خِرد کہیں یا Reason کہیں یا عقلِ جزوی کہیں، اِس کا کام یہ ہے کہ وہ جو divine intellect order (الوہی عقلی نظام) ہے اُس سے خود کو مربوط رکھے۔ تو اُن کا تصورِ عقل بالکل مختلف ہو گیا۔ اُس میں ان کی تھیوریز الگ الگ ہیں (یعنی) اِن دونوں سے بالکل الگ۔ ابھی اُس کی تفصیل میں نہیں چاہتا۔ میری خواہش ہے کہ کبھی ہم صوفی ڈسکورس پر بات کریں، تو اُس میں ان شاءاللہ اِس کی تفصیل بھی کریں گے۔ سرِ دست تو یہ دکھانا تھا کہ میٹا فزکس کی یہ تین روایتیں، metaphysical realm (مابعد الطبیعیاتی اقلیم) میں رہنے والے یہ تین قوتیں ہمارے یہاں سرگرمِ عمل رہی ہیں۔
مولانا ایوب دہلویؒ صاحب اِن تینوں کے بہترین وارث تھے اور اِن کے synthesizer (جامع) تھے۔ فلسفے کے تو وہ ناقد تھے۔ فلسفے کی تو وہ بالکل تردید کرتے تھے لیکن صوفیاء اور متکلمین کے درمیان پیدا ہو جانے والے اختلاف کو، اِن کے درمیان بظاہر دکھائی دینے والے تضادات کو مولانا نے حل کر کے دکھایا۔ اِن دو متضاد دکھائی دینے والی چیزوں کو وحدت میں پرو دیا، ایک بنا دیا۔ اِس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری روایت کے جو صوفیانہ اور متکلمانہ پیراڈائمز ہیں وہ پہلی مرتبہ تو غزالی نے جوڑے۔ پھر شاہ ولی اللہ صاحب کے ہاں نظر آئے۔ اُس کے بعد اگر کہیں ہیں تو وہ مولانا ایوب دہلویؒ ہیں۔ اِن کا ہر متکلمانہ مؤقف ایک صوفیانہ state of presence (حالتِ حضوری) کے ساتھ ہے۔ خیر صوفی فکر کے نمائندے کی حیثیت سے اپنا تعارف نہیں کرواتے تھے لیکن بہرحال یہ کارنامہ بہت بڑا ہے اگر غور کیا جائے۔ جیسے صوفی کہتے ہیں، متکلم حجاب میں ہیں۔ ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وہ پردہ بھی خود اِن کی عقلیں ہی ہیں۔ مولانا اِس اعتراض کو مانتے ہیں۔ چونکہ اِن دونوں کا مدلول واحد ہے تو اِن میں حق اور ناحق کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کو وہ بھی پورے شعور سے مانتے ہیں، صوفی وہ ہے جو پورے وجود سے مانتا ہے۔ یہ پورے وجود سے ماننا اور پورے شعور سے جاننا، مولانا کے یہاں ایک ہو جاتا ہے۔ اس کے ایک اور synthesize ہو نے کی صورت یہ ہے کہ متکلمانہ مؤقف، متکلمانہ دعوے اور تصورات وہ ایک حالتِ حضور اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ صوفیوں کا فائدہ ہے۔ اگر متکلم صوفی سے فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر اس کے دلائل میں تجرید کی بجائے empiricize ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک presence کے ساتھ اُس کی دلیل لوگوں میں منتقل ہوتی ہے۔
مولانا نے وحدت الوجود پر بھی کلام کیا ہے عقلی زاویے سے اور اُس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وحدت الوجود کو اگر ہم rationalize کریں اور reason کی اپنی تعریف پر رہتے ہوئے اُسے rationalize کریں، تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت کا انکشاف ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ’’الموجود واحد‘‘۔ وحدت الوجود میں انہوں نے یہ ترمیم کی کہ وجود الواحد، وجود صرف ایک ہے۔ یہ غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ اِس سے pantheism بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اُس کو روکنے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں رہ جاتا۔ وجود ایک ہے، موجود بہت سارے ہیں۔ مولانا نے تھوڑا اِس کو یوں کیا جیسے مارکس نے ہیگل کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے کہا، نہیں، یہ جملہ اس طرح ہونا چاہیے کہ الموجود واحد۔ یعنی جس میں موجود اور وجود، form (بنتر) اور essence (جوہر) کی غیریت ختم ہو گئی ہے۔ جسے موجود کہو تو بھی ٹھیک، وجود کہو تو بھی ٹھیک۔ وہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ یہ بہت ہی بڑی correction کی ہے مولانا نے اور یہ correction کرنے کے بعد متکلمین اور صوفیاء میں ایک وحدت کی گنجائش نکالی ہے، ایک productive وحدت کی۔ یہ میرے خیال میں مولانا کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔
(ختم شد)