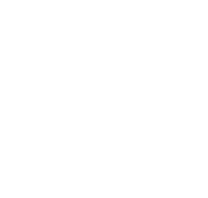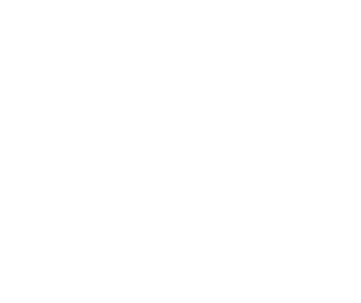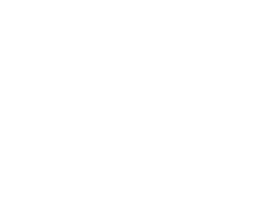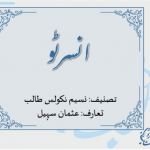عنوان: سرمد صہبائی: تقدیسِ بدن کا شاعر- گفتگو: احمد جاوید صاحب (حروف کار: عاصم رضا)
نوٹ: مَیں یعنی حروف کار ہی تمام تر پیراگرافنگ، رموزِ اوقاف نیز بعض جملوں کی ترتیب میں تبدیلی کا ذمہ دار ہوں۔ احمد جاوید صاحب کی گفتگو یہاں سے سنی جا سکتی ہے: قسط اول اور قسط دوم ۔
آج ایک بہت جینوئن شاعر پر گفت گو کرنی ہے۔ میں اِس بات پر شرمندہ ہوں کہ اُن کا خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا۔ ہمارے ہم عصر شاعروں میں سے ایک بہت جینوئن، بہت منفرد اور بہت پُرزور کیفیاتی شاعری کرنے والے ہیں سرمد صہبائی صاحب (پیدایش 1945ء)۔ اب یہ شاید پاکستان سے باہر رہتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے بہت سارے disciplines (شعبوں) میں ماہر آدمی ہیں اُس کا ذکر مَیں ابھی کروں گا۔ اِن کے جو تخلیقی مظاہر اور کارنامے ہیں ہم نے اُن میں سے مجبوراً غزل کو چُنا ہے کہ ہم آج اِن کی غزل پر بات کریں گے۔ خاص طور پر یہ دکھائیں گے کہ ان کے یہاں اظہار سے لے کر احوال اور احساسات تک مکمل انفرادیت کس رنگ سے اور کس شان سے ظاہر ہوئی ہے۔
اُنھیں میں کبھی ملا نہیں ہوں لیکن مَیں نے اِنھیں بہت پہلے دیکھا ہے۔ سنہ 1980 ء میں اسلام آباد میں میرے ایک تعلق والے ڈاکٹر جبار خان صاحب ہوا کرتے تھے۔ وہاں پر گھر میں ہی اُن کا بڑا سا کلینک تھا۔ مَیں وہاں اُن سے ملنے یا کسی وجہ سے بیٹھا ہوا تھا تو ایک بہت کشیدہ قامت صاحب، قدرے نوجوان، داخل ہوئے۔ انہوں نے سفید رنگ کی قمیض شلوار (جیسے) کپڑے پہنے ہوئے تھے اور قمیض کھنچی ہوئی تھی (یعنی) شکنوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ لگتا ہے کہ سوتے سے اٹھ کر اُسی حلیے میں آ گئے۔ اُس وقت مجھے منیر نیازی (1928ء تا 2006ء) کی یہ لائنیں یاد آئیں۔
کل دیکھا اک آدمی اَٹا سفر کی دھول میں
گم تھا اپنے آپ میں، جیسے خُوش بُوپھول میں
ایک خود فراموشی کے ساتھ جس کا ایک سب سے کم تر اظہار اُن کے لباس سے ہو رہا تھا مجھے بڑی کشش سی ہوئی۔ پھر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ سرمد صہبائی ہیں۔ مَیں، غائبانہ، ظاہر ہے جانتا تھا انہیں کہ بہت مشہور تھے اپنی نوجوانی ہی میں اور اُس وقت یہ غالباً پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کیا کرتے تھے۔ یہ اُس وقت اپنی نظموں کی وجہ سے بہت مقبول اور مشہور تھے۔ لیکن یہ تھے شاعروں کے شاعر، خواص کے شاعر۔ ان کی مقبولیت عوامی نہ اُس وقت تھی اور نہ ہی شاید اب ہو۔ اللہ کرے کہ نہ ہو۔ اُس وقت مجھے یہ عجیب سا لگا کہ اُن کی شاعری جتنی مَیں نے پڑھی ہوئی تھی، چھپی ہوئی تھی وہ شاعری فنون وغیرہ میں، رسالوں میں پڑھی تھی۔ مجھے لگا کہ ایسی شاعری ایسا ہی آدمی کر سکتا ہے۔ اپنے تخلیقی تجربات اور اُن کی نوعیت اور اُن کے اظہار میں جو چیزیں پائی جاتی تھیں وہ سب کی سب مجھے جیسے ان کی قدوقامت میں اور ان کے اُس وقت کے حلیے میں مجسم نظر آئیں۔ مجھے بڑا اچھا لگا لیکن موقع ایسا نہیں تھا کہ مَیں اِن سے ہاتھ ملاتا یعنی اِن کا پرستار ہونے کا فائدہ اٹھاتا۔ یہ مجھے ایسے آدمی لگے کہ جس کا جسم کسی زلزلے کی لپیٹ میں آئی ہوئی مٹی سے بنا ہے۔ مطلب، اُس میں ایسا مخفی ارتعاش ہے کہ اُس پر کپڑے اگر جل نہیں گئے تو تعجب اِس پر ہونا چاہیے۔ اِس پر نہیں کہ وہ شِکن آلود کیوں تھے۔ خیر، وہ ایک تاثر تھا۔
پھر اُس کے بہت بعد میرے ایک دوست ہیں کرنل آفتاب صاحب، اُنھوں نے اِن کا ذکر کیا کہ میرے دوست ہیں۔ مَیں نے کہا کہ بہت اچھا۔ پھر جب اُن کے کہنے پر میرے ذہن میں آیا کہ ارے، سرمد صاحب کو تو مَیں بالکل بھولا ہوا تھا۔ ان پر تو کام کر چکنا چاہیے تھا، سو (اب) مَیں کرتا ہوں۔
آج مَیں اِن پر گفتگو کروں گا اور اِس گفتگو میں شاید پہلی مرتبہ ایک بہت بڑے تخلیقی theme کا تذکرہ آئے گا۔ اُس کی تفصیل آئے گی جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک وہ باتیں کی نہیں ہیں جو آج سرمد صہبائی کی نظموں غزلوں وغیرہ سے inspire ہو کے کروں گا۔ ’’ماہِ عُریاں‘‘ (مطبوعہ 2014، دستاویز) اُن کی غزلوں کا مجموعہ ہے ۔ ہم نے جو انتخاب کیا ہے وہ اِس میں سے کیا ہے ۔
٭٭٭٭٭
70ء کی دہائی میں شاعروں کو کچھ لقب دیے جاتے تھے۔ یہ ایک فیشن تھا۔ جیسے عبید اللہ علیم (1939ء تا 1998ء) کو ہمارے استاد نے کہا کہ یہ آشوبِ ذات کا شاعر ہے۔ کوئی تطہیرِ جذبات کا شاعر ہے۔ کوئی فلاں کا شاعر، کوئی فلاں کا شاعرہے۔ ایک بڑا مضمون اُس سے منسوب کر دیتے تھے۔
اُسی روایت پر رہ کے اگر مَیں کہوں تو ’’سرمد صہبائی تقدیسِ بدن کے شاعر ہیں‘‘۔ یہ جسم کی تقدیس کے داعی ہیں اور اِن کی شاعری سے اظہار پانے والے تمام تجربات، کیفیات، خیالات اور مضامین چاہے بیان شدہ حالت میں (ہوں)، چاہے unsaid (ان کہی) کیفیت میں (ہوں)، اِن کا یہ جوہر شامل ہوتا ہے۔ یعنی اِن کے یہاں جو بڑی کیفیات ہیں، جو بہت بنیادی کیفیات ہیں، وہ تقدیسِ بدن کی قدر پر پیدا ہوئی ہیں۔ اُس پر ہم جائیں گے لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں بھی آ جائیں گی جنھیں کہنے سے داڑھی رکھنے کے بعد ظاہر ہے کہ مجھے بھی جھجک ہونے لگی ہے۔
مَیں اِس کی تمہید میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے، بل کہ، ہر ایسا اخلاق ڈھکوسلا ہے جو جسم کی تقدیس کا احترام نہ کرتا ہو۔ جیسے ہمارے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی (1165ء تا 1240ء) کا ایک قول ہے جو مشہور ہے کہ جب آدمی وصلِ جسمانی یعنی (physical intimacy) میں ہوتا ہے تو اُس وصل ِ جسمانی سے حاصل ہونے والی لذّت، یکتا لذّت، کامل ترین لذّت، غالب ترین لذّت، فنا و بقا کے تجربے سے حاصل ہونے والی لذّت ہے۔ آدمی سمجھتا یہ ہے کہ اُسے جسمانی لذّت حاصل ہو رہی ہے لیکن درحقیقت وہ لذّت libido (جنسی طلب) تک محدود نہیں ہے۔ وہ لذّت جیسے کوئی عاشق ِ صادق اپنے محبوبِ حقیقی کے حضور میں فنا و بقا کے احوال سے گزر رہا ہے، یہ وہ لذّت ہے۔ شیخِ اکبر کا یہ قول ہماری اس تمام باتوں کے لیے، جو ہم کریں گے، ایک بنیاد فراہم کردیتا ہے۔ کہنے والے کو بھی ہوشیار رکھتا ہے، (اور) سننے والے کو بھی مُتنبّہ کر دیتا ہے کہ یہ ساری گفت گو جو ہے اِس میں الفاظ جسمانی ہوں گے معانی جسمانی نہیں ہیں۔
تقدیسِ جسم کا مطلب ہی یہ ہے کہ جسم کو روح کے لائق بنانا، ذہن کے قابل بنانا۔ ایک اخلاقی کُل کا فعال اور productive کارکن بنانا۔ یہ جو تصوّر ہے کہ آدمی مرد اور عورت کے تعلق میں جس لذّت سے گزرتا ہے، ایک تو وہ لذّت اپنے تجزیے میں، اپنے biological context (حیاتیاتی سیاق و سباق ) میں بھی جسم کو حاصل ہو سکنے یا ہوتے رہنے والی تمام لذّتوں سے ممتاز ہے۔ یہ لذّت ایسی ہے کہ انتہائی گہرے معانی، انتہائی قابل ِ فخر احوال اور انتہائی روحانی اعتماد اور ذہنی vitality (قوّتِ حیات) کی ضمانت دیتی ہے اُس آدمی کو بھی جو شاید یہ الفاظ نہ جانتا ہو۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے رومی (1207ء تا 1273ء) نے کہا،
شہوتِ دنیا مثال ِ گلخن است
کہ از و حمامِ تقویٰ روشن است
یہاں شہوتِ دنیا میں آپ libido (جنسی طلب) سمجھیں کہ لیبیڈو کے جو تقاضے ہیں، تجربات ہیں، وہ ایندھن کی طرح ہوتے ہیں کہ اِسی سے تقویٰ کا سماوار (چائے دَم کرنے یا پانی گرم کرنے کا انگیٹھی دار ظرف، از حروف کار) گرم رہتا ہے۔ تو مجھے اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے جس حرارت کی ضرورت ہے اُس حرارت کی پیدایش میں جسم کی شمولیت نہ ہو، تو وہ حرارت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یعنی آدمی عشقِ خداوندی میں بھی ایک state of vitality (قوّتِ حیات کی حالت) پر، ایک سٹیٹ آف خود فراموشی پر ہوتا ہے۔ وہ اُسی وقت وہی آدمی ہوتا ہے جو اِس لذّت کے آداب پورے کر چکا ہو اور اِس لذّت نے اُسے قوی کیا ہو، جسم سے لے کر ذہن اور ذہن سے لے کر روح تک۔
مَیں واقعی کبھی غور کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جنسی معاملات کی بیش تر شاعری فحش ہے۔ اُسے فحش کہنا چاہیے کیوں کہ جسم اپنی ہر لذّت میں فحش ہے جو ذہن اور اُس کی روح کے لیے کارآمد نہ ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ اگر یہ لذّت میرے دماغ کو متاثر نہیں کرتی، میرے دماغ کے کام نہیں آتی تو ظاہر ہے کہ اِس کا اظہار، اِس کا احساس، سب فحاشی ہے/ فحش ہے/ حیوانی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی چیزوں کی معاملہ بندی جو شاعری میں ہو، وہ اگر کسی بڑے meaning (معانی) پر end (انجام) کرے/ کسی بڑے حال میں صَرف ہو اور صَرف اس طرح نہیں ہو کہ یہ گھٹیا چیز ہے اور بڑھیا چیز آگئی تو اِس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ (بل کہ) اُس بڑائی کے بنیادی جوہر کے طور پر اُس بڑائی میں داخل ہو جانا، اُس بڑائی کے بنیادی معمار کی حیثیت سے۔ یہ ہے جسم کا مرتبہ اور جسم کا وہ مقام جس کو ہم اگر نہ سمجھ سکے تو ہماری روح خیالی، ہمارا دماغ فضول اور ہمارا جسم مریض ہے۔
ہمارے یہاں اگر آپ غور کریں تو فارسی میں دو شاعروں کو پڑھ کے دیکھیے ۔ دونوں صوفی شاعر ہیں، دونوں عالم شاعر ہیں۔ لیکن ان کے یہاں libido (شہوت ) سے پیدا ہونے والی vitality (قوّت)، ان کے یہاں جسمانی لذّت کے اس سرچشمے سے فائدہ اٹھانے والی روحانی سرشاری نظر آئے گی۔ وہ ہیں رومی خصوصًا سمجھنے کے لیے اپنی مثنوی میں اور تجربہ کرنے کے لیے دیوان میں، اپنی غزلوں میں۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک بالکل جواں مرد جو جواں مردی کی تمام definitions (تعریفات) پر پورا اترتا ہے۔ مردانگی کا اثبات کرنے والی تمام جو دلیلیں ہیں وہ اُس کے اندر متحرک حالت میں موجود ہیں۔ جس کا libido (شہوت) بھی اُس کی روح کی طرح مضبوط (اور) طاقت ور ہے۔ دوسرے حافؔظ (شیرازی: 1315ء تا 1390ء) ) ہیں۔ حافؔظ کے یہاں تو مجھے ہمیشہ محسوس ہوا کہ اگر یہ ایک strong libido (طاقتور شہوت) کے مالک نہ ہوتے تو ان کی شاعری کا یہ رنگ نہ ہوتا، مطلب، دیوانِ حافظ وجود میں نہ آتا۔ وہ دیوانِ حافظ جو روحانی حقائق اور عشقِ حقیقی کے احوال میں سند کی حیثیت رکھتا ہے وہ وجود میں نہ آتا اگر ان کی libido (طلب) سیراب نہ ہوتی، اُن کے نفس کا یہ حصّہ شاداب نہ ہوتا۔ بل کہ، اُن کے کچھ شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ کچھ تو بہت مشہور ہیں۔ اب اُن کے معانی روحانی ہیں لیکن وہ کیفیت پیدا ہی نہیں سکتی تھی جب تک اس کیفیت میں جسم کا تجربہ نہ داخل ہو۔ مثال کے طور پر،
زلفت ہزار دل بہ یکے تار مو ببست
راہ ہزار چارہ گر از چار سو ببست
اپنے ایک بال سے ہزاروں دل شکار کر کے باندھے ہوئے ہیں۔ ہزاروں دل تیری زلف کے ایک ایک تار میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہزاروں چارہ گروں، ناصح (موجود) ہیں (لیکن) اُن سب کا راستہ چاروں طرف سے بند کر دیا ہے اِس ایک تارِ مُو نے ۔
اب اِس (شعر) میں کہیں جسم اور یہ سب نہیں آیا۔ دوسرے مصرعے میں جو تحکم اور قوت اور Passion اور ایک لگن جیسے شعلۂ سیاہ والی حرارت آپ محسوس کر سکیں گے۔ یہ شعر اُس vitality کے بغیر نہیں ہو سکتا ۔ مطلب، اتنا زیادہ زور سے کہا گیا ہے کہ تیری زلف نے ہزار دل باندھ رکھے ہیں ۔ نہ صرف یہ کہ وہ بندھے ہوئے ہیں بل کہ تیری زلف نے ہر ہر طرف سے ناصحوں یعنی جسم کی ناقدری کرنے والوں کا راستہ بند کر رکھا ہے ۔ کس زلف نے بند کر رکھا ہے؟ جس کے ایک بال میں ہزاروں دل گرفتار ہیں۔ ظاہر ہےجس کے ایک بال میں ہزاروں دل بندھے ہوئے ہوں تو اس کے لگائے ہوئے چاروں طرف کے barriers (جنگلوں ) کو کوئی نہیں توڑ سکتا ۔ جیسے اِس میں ایک سرشار آدمی ہے۔ وہ نہیں ہے کہ اس کا جسم بھی خیالی لذّتوں میں ہے، ذہن بھی خیالی معرفتوں میں ہے ۔ مطلب، یہ تجربہ ہی نہیں بن پائے گا ۔
(یہاں احمد جاوید صاحب کوخُدائے سخن میرؔ کا مندرجہ ذیل بھی شعر یاد آنا چاہیے تھا، از حروف کار،
صد رگِ جاں کو تاب دے باہم
تیری زلفوں کا ایک تار کیا)
اِسی طرح (حافؔظ کا) ایک اور بہت زیادہ مشہور شعر ہے،
گرچہ پیرم تو شبے تنگ در آغوشم گیر
تا سحر گہ ز کنار ِتو جواں بر خیزم
اگرچہ میں بوڑھا ہوں، لیکن ایک رات تو مجھے اپنی آغوش میں ذرا جکڑ لے۔ اگر ایسا ہو جائے تو صبح اٹھتے اٹھتے میں جو بوڑھا ہوں وہاں سے جوان ہو کر نکلوں۔ اب اِس کے معنی بہت ہیں۔ یہ کوئی جوش ملیح آبادی کا شعر نہیں ہے۔ اس کے معنی بہت ہیں ۔ بہت qualified (سند یافتہ /لائق) عقل کو بھی متوجہ کر نے والے معانی ہیں اِس میں ۔ لیکن اُن سب کی جو بنیاد ہے وہ اِس vitality پر ہے۔
(بعینہ)،
چُو پیراہن شوم آسودہ خاطر
گرش ہمچون قبا گیرم در آغوش
مَیں پیراہن کی طرح /لباس کی طرح/ کُرتے کی طرح آسودہ خاطر ہو جاؤں یعنی میرے دل کی ہر مراد ہمیشہ کے لیے پوری ہو جائے/ میری کوئی آرزو پیاس کی صورت میں باقی نہ رہ جائے، اگر وہ مجھے قبا کی طرح آغوش میں لے لے۔
یہ جدید سے جدید (شعر) ہے ۔ یہ شعر تو ایسا ہے کہ اب میں کیا بتاؤں اِس کی خوبی۔ سنہ 3500ء میں اگر شاعری باقی رہ جاتی ہے تو اس وقت بھی یہ شعر اگر سنا دیا جائے تو اس وقت موجود شاعروں کے بڑے بڑے بڑھک باز جو ہیں وہ جھک جائیں گے ۔ یہ شعر بیالوجیکل بڑھاپے میں نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح اور بہت سارے شعر ہیں ۔ مطلب، یہ ایسی کوئی معمولی چیز نہیں ہے ۔ کسی بھی پہلو سے یہ نظر انداز کیے جا سکنے والا مضمون نہیں ہے ۔
مجھے بڑی حیرت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، اچنبھا بھی ہوا۔ رومی، ابن ِعربی اور حافظ کے تصوّرِ بدن بالخصوص تصوّرِ جنس جہاں بدن بالکل کھَرا ہوتا ہے۔ بدن پورا ہوتا ہے اس تصوّر میں۔ بھوک پیاس اور غصے غم میں نہیں ہوتا۔ اُس میں کوئی نہیں نبھا پایا ہمارے یہاں۔ لیکن ایک شاعر ایسا آج موجود ہے جو اس روایت کو اچھی طرح بھی اور انفرادیت کے ساتھ نبھانے پر نکل کھڑا ہوا ہے اور اس نے کام یابی حاصل کی ہے۔
یہ اِس گفت گو کا ایک عنوان ہے، ’’تقدیسِ بدن کا شاعر‘‘۔ آگے بھی ہم کریں گے۔ ابھی جو مَیں نے انتخاب لکھا ہے وہ بعد میں پڑھ دیتا ہوں۔
٭٭٭٭٭
اسی طرح سرؔمد صہبائی جو ہیں اب تو ماشاءاللہ یہ مجھ سے بڑے ہوں گے ۔ ان کی ایک انفرادیت آج کل کے ماحول میں بھی ہے کہ یہ بہت تخلیقی تنوّع رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تخلیقی یک رُخا پن غالب ہے ہمیشہ سے، صرف اس زمانے میں نہیں۔ وہ لوگ کم ہوتے ہیں جن کی creativity (تخلیقی صلاحیت ) الگ الگ صورتوں میں manifest (ظاہر) ہوتی ہے۔ مثلًا، یہ شاعر ہیں۔ اِن کا ایک پہلو ہے ان کا شاعر ہونا۔ شاعری کی جس صنف میں بھی اُنھوں نے طبع آزمائی کی ، (یعنی) نظم میں، بل کہ وہ کافیاں بڑی زبردست ہیں، غرض جس صنف میں بھی، اُس میں اپنی تخلیقی انفرادیت کو برقرار رکھا ۔ تخلیقی انفرادیت صرف اچھے شعروں میں نہیں ہوتی۔ اگر برے شعروں میں انفرادیت نہ ہو مؔیر کی طرح تو آپ کی انفرادیت خالص نہیں ہے ۔ ان کی ہر ہر لائن جو ہے / ہر ہر شعر، ان کی انفرادیت پر گواہ ہے۔ اسی طرح یہ آرٹس میں گئے، ڈرامےبنائے، فلمیں بنائیں، مؔیر پر بہت اچھی (فلم) بنائی ۔ جو جو کام اُنھوں نے کیے جو مجھے معلوم ہیں اور جو نہیں معلوم، وہ سب جو ہیں اپنی انفرادیت کے نئے مظاہر پیدا کرنے کے عمل کے طور پر کیے ہیں۔ انھوں نے کوئی کام اوپری طور پر نہیں کیا۔ اُنھوں نے کوئی کام کسی اور غرض سے نہیں کیا۔ اُنھوں نے کوئی کام کسی سے واہ واہ کروانے کے لیے نہیں کیا۔ یہ مجھے یقین ہے۔
یہ ایک جیسے زاویہ نشین جوگی کی طرح شخصیت رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پانی بھی پیتے ہوں گے تو اس میں بھی کوئی انفرادیت کا پہلو نکلتا ہو گا۔ مطلب، انفرادیت ان کا خمیر ہے۔ وہ لوگ جو دیگر فنون جانتے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ یہ ان disciplines (دائروں /شعبوں ) میں کتنے منفرد ہیں اور کتنے مخلص اور سچے ہیں۔
اِن کی جو غزل ہے جس پر آج ہمیں بات کرنی ہے وہ یوں سمجھیں کہ ان کا کتابِ تخلیق فرض کیا دس ابواب پر ہے تو ان میں سے ایک باب ہے غزل ۔ نو (9) ابواب ابھی باقی رہتے ہیں ۔ ہم گویا ایک کتاب کے ایک باب کو دیکھ رہے ہیں ۔ مَیں نے ان کی نظمیں بھی دیکھی ہیں ۔ ان کا نظموں کا مجموعہ ’’نیلی کے سو رنگ‘‘ (مطبوعہ 2009، دستاویز) ہے ۔ اُس میں یا غزلوں میں یا ان کی تمام شاعری میں کچھ چیزیں جیسے مشترک ہیں ۔ ظاہر ہے کہ کمہار کا ہاتھ تو وہی رہتا ہے، پیالے وغیرہ الگ الگ بنتے ہیں۔ وہ ہے کہ ان کی شاعری ایک پُرزور اور پُرجوش، لیکن گہری اور شانت واردات کی طرح ہے۔ ایک ایسی واردات یا کیفیت کی طرح ہے جو بہت پُرزور ہے، بہت پُرجوش ہے لیکن وہ لپٹی ہوئی ہے گہرائی میں۔ جیسے وہ ہوتا ہے ناں آتش فشاں ۔ آتش فشاں کا سکوت اور اس کے اندر بھری ہوئی آگ کا طوفان تو یہاں جیسے ان کےیہاں (ہے) ۔ ان کا ہر تخلیقی تجربہ بھی اور اس کا اظہار بھی اِس طرح ہوتا ہے ۔ جوش اور گہری شانتی کے ساتھ۔ یہ گہرائی جو ہے ان کے جوش اور زور کو کم نہیں کرنے دیتی لیکن اس کا درجہ بلند کر دیتی ہے۔ یہ گہرائی ان کی ہر ہر کیفیت میں ہے یعنی تخیّل اور احساس میں ایک بڑے واقعہ کی طرح ہے۔ یہ جس جوش، passion، آتش فشانی کے ساتھ گزرے ہوئے ہیں جس تجربے سے، اس کے ساتھ ہی چُوں کہ یہ ہر تجربے سے بڑے ہیں تو یہ تجربے کو اپنی بڑائی میں کھپا لیتے ہیں۔ یعنی ہر تجربہ ان کے لیے اِن کے کُل میں سما جانے والا جزو ہے۔ وہ جو کُل ہے بہت گہرا، خاموش، اندھیرا، ٹھنڈا اور ایک پہلو سے ہیبت ناک ہے۔ یہ دونوں کو جب جوڑ دیتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ برف کی سِل میں لاوا بھرنے میں کام یا بی حاصل کر لیتے ہیں پھر ان کا ہرتجربہ، ہر خیال، وہ کوئی ثانوی حیثیت نہیں رکھتا۔ ان کے یہاں یہ بہت بڑی قوّت ہے ان کی کہ ان کے یہاں اگر پچاس احوال اور کیفیات ہیں بیان ہوئے ہیں تو ان میں سے ہر ایک مرکزی ہے۔ اس پہلو سے ان کے یہاں (اِس شے) کو میں کہہ رہا ہوں کہ گہری واردات میں ملفوف آتشِ جوالہ۔ وہ تخیّل میں بھی ظاہر ہے ایک بڑا دھماکا ہے اور احساس میں بھی ایک بڑا واقعہ ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی پڑھ کے دیکھ لے کہ احساسات و کیفیات میں sharp categorization ممکن نہیں ہے۔ یہ سرخوشی کا احساس، یہ غم کا احساس صرف کہنا مشکل ہے ان کے یہاں۔ یار، غم تو ہے، لیکن پتہ نہیں کچھ اور بھی لگ رہا ہے۔ اس طرح کا (احساس) پیدا کر دیتے ہیں اور سبب یہی ہے کہ ان کا تخلیقی سیلف، ان کے اندرجو ایک نظام ہے وہ اس طرح کا paradoxical ہے یا paradoxical نہ کہیں تو وہ ایک بڑے کُل کی تخلیق میں کام آنے کے لائق ہے۔ احساس میں (ہی ) کیا (بل کہ) تخیّل میں رنگینی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ آدابِ دید سیکھ جاتا ہے تخیّل۔کیوں کہ تخیّل نام ہے تربیت یافتہ آنکھ کا ۔ وہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ دیدہ (اور) نادیدہ، ان کے درمیان فرق جو ہے وہ صرف سرسری رہ جاتا ہے تخیّلی نہیں رہتا۔
یہ سب اِن کے ہاں ہے جو ہم رفتہ رفتہ دیکھیں گے ان شاء اللہ آگے۔
٭٭٭٭٭
اب جو ایک بہت ہی بنیادی بات عرض کرنی ہے ۔ کتاب کا نام ہے ’’ماہِ عریاں‘‘۔ یہ ترکیب شاید ہم نے پہلے کہیں نہ پڑھی ہو، نہ دیکھی ہو ۔ یہ تصور ہی نیا ہے ۔ مطلب، بعض ترکیبیں کسی زبان میں نئی ہوتی ہیں لیکن ان کا انگریزی میں ترجمہ کر دیں تو وہ انگریزی میں مستعمل ہوتی ہیں ۔ فارسی میں مستعمل ہوتی ہیں۔ اِس کا آپ کچھ بھی کر دیں (یعنی) ماہِ عریاں، ننگا چاند، naked moon، ماہِ بے لباس، (الغرض) کچھ بھی کر دیں، ہر ہر ترجمے میں یہ اس زبان میں بھی نادر ہو گا۔ بڑی بات ہے۔ اب اس میں (لفظِ) ’عریاں‘ (جو ہے، قدرے وضاحت طلب ہے)۔ کیوں کہ (آج) ہم لوگ شاعری اور لفظ اور شاعری کی مختلف روایتیں، اُس کے فیڈرز، اُن سب سے تو فارغ ہو چکے ہیں تو اب جیسے الف ب سے کہنا پڑتا ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کیوں کہ یہ (لفظِ) ’عریاں‘ دیکھتے ہی جسمانی عریانی کی طرف ذہن جانے اور وہی تک محدود رہنے کا قوی احتمال ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیوں کہ ’’ماہِ عریاں‘‘ (یعنی) اُس کی روشنی نے اسے عُریاں کیا ہے (مگر) اُس کے دھندلکے نے اسے ابھی بھی ڈھانپا ہوا ہے۔ لیکن اس کی روشنی اس کی عُریانی ہے۔ یہ گہری عُریانی ہے جو مَیں کہہ رہا تھا، وہ ہے۔
’عُریاں‘ کا مطلب ہے بالکل ہر چیز اور ہر ملاوٹ سے پاک ہونا یعنی as suchness (ذات جیسی کہ وہ ہے/ذاتِ محض) ۔ یہ’عُریاں‘ کا جو لفظ ہے ناں، اس سے بنا ہے (لفظ) ’’وصلِ عریاں‘‘۔ آج کل کسی کے سامنے کہہ دو ’’وصلِ عُریاں‘‘ تو وہ کہے گا کہ یار ، یہ تو بہت ہی بیہودہ کلام کرتا ہے۔ یہ تو اخلاق میں نہیں۔ حال آں کہ بااخلاق آدمی کو یہ نہیں معلوم کہ ’’وصلِ عُریاں‘‘ تصوّف کی ایک بڑی اصطلاح ہے۔ یہ سلوک اور معرفت کی انتہا ہے یعنی یہ آخری درجۂ قرب ہے جہاں اللہ صفات سے پاک، اسماء سے پاک، اپنی محضیت کے ساتھ، اپنی pure transcendence (خالص ورائیت) کے ساتھ، اور سالک اپنی pure negation (سلبِ کامل) کے ساتھ۔ اُس حالت کو کہتے ہیں ’’وصلِ عُریاں‘‘۔ یہ تصوف کی ایک عام اصطلاح ہے جہاں چاہے آپ دیکھ لیں اور اس کو بل کہ رومی نے باندھا بھی ہے اپنے شہرۂ آفاق شعر میں، جو اس مضمون کا حرفِ آخر ہےاور لگتا یہ ہے کہ رہے گا۔
میروم سوے نہایاتُ الوصال
من ز تن عُریاں شدم اُو از خیال
مَیں چلا جا رہا ہوں وصال کی منزلوں کی طرف، وصال کی انتہاؤں کی طرف (یعنی) ایک انتہا سے دوسری انتہا۔ اب اس چلنے میں کیا ہو رہا ہے وہ (دوسرے) مصرعے میں بتا دیا۔ (یعنی) میں جسم سے عُریاں ہو گیا یعنی جسم سے پاک ہوگیا اور وہ خیال سے پاک ہو گیا۔ وہ اپنے بارے میں ہر ہر خیال اور علم سے پاک ہو گیا، میں اپنے جسم سے آزاد ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے عُریانی۔
میں نے بھئی یہی دیکھا ہے کہ اُردوروایت میں عریانی نہیں آئی ہے۔ یعنی عریانی کا یہ پہلو اُردوشاعری میں مؔیر، غاؔلب وغیرہ کے یہاں بھی نہیں ہے۔ ہاں، شاید کسی صوفی شاعر کے ہاں نکل آئے۔ ورنہ یہ لوگ بھی اسی طرح کے ہیں۔ (بقول غالؔب)،
تھیں بنات النعشِ گردوں دن کو پردے میں نہاں
شب کو ان کے جی میں کیا آئی کہ عُریاں ہو گئیں
یہ عُریاں nudity (بے لباسی ) ہے محض اور کیا ہے!
یہ عجیب بات لگی کہ بھئی ایک ایسا آدمی ہم نے دیکھ لیا جو روؔمی کی روایت کو نبھا رہا ہے اُسی اصطلاح میں اور اس اصطلاح میں تن کا اثبات کرتے ہوئے۔ اب یہ بات ہوئی کہ روؔمی کے یہاں عُریانی تن سے پاک ہونا ہے۔ اِن کے یہاں عُریانی تن سمیت ہے لیکن اسی احوالی لطافت کے ساتھ ہے جس احوالی لطافت کا اظہار روؔمی کے شعر میں ہو رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنا اور اس کو سمجھنے کی (کوشش)، مطلب ، بڑا لطف آئے گا ان شاءاللہ۔
(اب) یہ جو ’’وصلِ عُریاں‘‘ ہے یہ تصوف میں سلوکِ عشقی اور مشربِ عرفانی دونوں کا انتہا ہے ۔ یہاں اللہ کی معرفت بھی تمام ہوجاتی ہے یعنی وہ سفر رک جاتا ہے اور یہاں اللہ سے آرزوئے وصل کی بھی انتہا درجے کی ایک universal (آفاقی) تکمیل ہو جاتی ہے۔
ایک تو ان کی پوری غزل ہی اس ردیف میں ہے وہ ہم ابھی دیکھیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، کم از کم اُردوکی جدید شاعری، دل چاہ رہا ہے کہ قدیم شاعری بھی کہہ دیں، اُس میں عُریاں کا متصوّفانہ، عارفانہ، مجذوبانہ اور قلندرانہ کیفیاتی کا جو دروبست ہے ناں، مدوجزر، وہ اگر کہیں اِس لفظ کے اوریجنل معنی سے متصادم اور مختلف حالت اور بالکل متضاد سیاق و سباق میں دکھائی دیتا ہے تو وہ یہ صاحب ہیں سرؔمد صہبائی صاحب۔
یہ تو بہت ہی بڑی انفرادیت ہے۔ یہ تو اچانک ہی نکل آئی مجھے نہیں اندازہ تھا۔
یہ جو عُریانی پسندی ہے ان کی، اسے میں عُریانی پسندی کی بجائے عُریاں پسندی کہنا چاہوں گا۔ یہ جو عُریاں پسندی ہے ان کے نام کی تاثیر ہے کہ یہ سرؔمد کی دین ہے عُریانی۔ مطلب، اس تجربے کی کیفیت سؔرمد سے ہے اور اس کی کیفیت و معنویت صہبائی سے ہے۔ سَر مست و عُریاں یہ ہے۔ خیر، یہ تو ایک ایسے ہی مذاق کی بات ہے۔
٭٭٭٭٭
پہلے خیال یہ تھا کہ ایک ہفتے کے وقفہ کے بعد دوسری نشست رکھ لیں گے، لیکن آج جیسے ایک تقاضا سا ہوا کہ اِس کو جلدی جلدی مکمل کر لیں۔ اِس لیے آج بھی وہی سلسلہ جاری رہے گا جو کل شروع ہوا تھا۔
جیسا کہ مَیں نے عرض کیا کہ اگر سرؔمد صاحب کی شاعری کو کوئی عنوان دیا جا سکے اِس اُمید کے ساتھ کہ اِس کا بیش تر content (مواد) بہ لحاظِ اُسلوب بھی اور بہ اعتبارِ کیفیت بھی cover (احاطہ) ہو جائے تو وہ عنوان ہے، ’’تقدیسِ بدن کا شاعر‘‘۔ پچھلی مرتبہ جو غزل صرف سنائی تھی آج اُس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اُس کی کیفیتوں میں سے گزرنے کی کاوش کرتے ہیں۔
سرؔمد صہبائی کی شاعری، کیفیات کی شاعری ہے جیسے کہ میں نے کل عرض کیا۔ ایسی کیفیات جن میں تخیّل اپنی تمام خلاقی کے ساتھ شریک ہے۔ ایسے شعرا کم ہوتے ہیں جن کے یہاں کیفیت کی تشکیل میں تخیّل یعنی imagery/imagination کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اِن کے یہاں یہ دونوں چیزیں جیسے لازم و ملزوم ہیں۔ یہ بھی عرض کیا تھا کہ اِن کے سارے اشعار/معانی واقعات کی طرح ہیں۔ کیفیات اور واقعات اور تصویروں کی طرح ہیں جن میں fixity (انجماد/جماؤ) کا عنصرنہ کیفیت میں ہے، نہ مفہوم میں ہے۔ اِتنا زیادہ fixity سے آزاد شاعر آج کل کم ملے گا۔
٭٭٭٭٭
اب وہ غزل شروع کرتے ہیں۔ یہ جو غزل ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہمیں بہت کچھ بتائے گی اور بعض گم شدہ ادراکات اور احساسات کو گویا بازیاب کروائے گی ہمارے اندر سے۔
کُھلا ہے سینۂ گُل، ہے چراغِ مُشک بُو عُریاں
کوئی پہلوئے شب میں ہو رہا ہے ہُو بہو عُریاں
(یہ) جیسے بہت علامتوں اور استعاروں سے بھرا ہوا شعر ہے اور اِس میں یوں لگتا ہے کہ ’’ہے‘‘کے علاوہ ہر چیز ایک symbolic value (علامتی قدر) رکھتی ہے۔ اِس شعر میں ایک بہت قیمتی بات یہ ہے کہ اس میں استعارے اور علامت کے درمیان پایا جانے والا بنیادی فرق دُھندلا گیا ہے۔ وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوا ۔ اب اِس کا جو پہلا مصرع ہے ’’کُھلا ہے سینۂ گُل، ہے چراغِ مُشک بُو عُریاں‘‘، اس مصرع یا اِس پورے شعر سے جو چیز، کیفیت یا معنی، برآمد ہو رہے ہیں / ہمارے اندر منتقل ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، وہ ہے sublime libido (ارفع شہوت) ، sublime working and version of libido (شہوت کی ارفع صورت اور سرگرمی) ۔ یہ اپنی جگہ ایک بڑا کارنامہ ہے اِس کو ہم آگے چل کر کھولیں گے کسی اور موقع پر ۔ یہ گویا جبلّت کو رفعت دی گئی ہے ۔ یہاں جبلّیات اور جبلّی استعاروں اور معاملات کو روحانی اور قلبی کیفیات میں بدل جانے کا راستہ فراہم کر دیا گیا ہے ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے ۔ یہ ہے sublime libido ۔ پھر یہ کہ اِسی مصرع کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جِسم یعنی میرا جِسم اور باہر موجود نیچر کا قانون، یہ (مصرع) اِن دونوں کو متحد کر رہا ہے کہ نیچر کا جو reproductive(تولیدی) نظام ہے وہ میرے ہی جِسم کے نمونے پر ہے ۔ تو نیچر اپنی ٹھوس تولیدی سرگرمیوں میں میرے جسم سے مستعار ہے یا میرے جسم سے مناسبت رکھنے والا ایک قانون ہے reproduction کا ۔ اِس کے علاوہ اِسی سے جو دوسرا پہلو برآمد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فطرت کو ، جو موجود نیچر ہے ، اِس کو humanize کیا گیا ہے ۔ جو لوگ نیچر والی شاعری ورڈزورتھ وغیرہ کی پڑھنے کا تجربہ رکھتے ہیں ، تربیت رکھتے ہیں وہ اِس بات کی اہمیت ان شاءاللہ سمجھتے ہیں کہ فطرت کی humanization کا کیا مطلب ہے۔ فطرت جسم ِ محض ہے اِس میں انسان کی جسمانیت سے اشتراک ایک شعور کا element بھی پیدا کر دیتا ہے ۔ اِس کو کہتے ہیں فطرت کی humanization اور اِسی کے ساتھ بدن کو نظامِ فطرت کا خلاصہ بنا دینا ۔ انسانی جسم نظامِ فطرت کا خلاصہ ہے ۔ یہ (چیز) اس مصرع ہی سے بالکل واضح ہے وہ رفتہ رفتہ (کھل جائے گا) جب ہم براہ راست جائیں گے اِس پورے شعر پر، تو ان شاءاللہ اِس کی تفصیل ہو گی۔ ابھی ہم نکات عرض کر رہے ہیں۔
تیسری چیز جو اِس مصرع سے چھلک کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جِنس محض انسانی نہیں ہے، یہ کائناتی passion (جذبہ) ہے ۔ کائناتی میکانزم اُسی جنس پر استوار ہے جس جِنس کو انسانوں کے درمیان اِن میں اضافہ کے لیے یا فرحت کے لیے یا لذّت کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو جِنس قانون ِ فطرت ہے اور یہ لازمًاانسانی نہیں ہے۔ جِنس کا مطلب واضح ہے ناں ۔ تو یہ کائناتی بھی ہے۔ یعنی کائنات کثرت کی کائنات ہے تو کثرت کہتےہیں جوڑے جوڑے کی ایک پوری دُنیا ۔ کثرت جوڑے سے بنتی ہے ۔ کثرت اپنی reproduction (افزائش) کے بغیر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی ، جسمانی سطح پر بھی اور آئیڈیا کے درجے میں بھی ۔ تو کثرت وجود کی لازمی ضرورت ہے۔ کثرت تصوّرِ وجود کا لازمی حصّہ ہے۔ تو اتنے بڑے model of existence کو ، اتنی systematized existence کو جو چیز سنبھالے ہوئے ہے، جو چیز اِس کی بنیاد ہے وہ interactive reproduction (تولیدی تعامل ) ہے ۔ جس طرح آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے جس بنیاد پر، اُسی اساس پر عالمِ کثرت اپنے میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ یہ جِنس اور اس کے پورے سابق اور لاحق اگر نہ ہوں، جِنس ایک بیالوجیکل فورس کے طور پر مجھے اور اِس دنیا ، کائنات اور عالمِ کثرت کو حاصل نہ ہو، تو ہم فنا کے قیدی ہیں ۔ ہم absurdity کا شکار ہیں ۔ ہم معطّل وجود ہیں ۔ یہ جو ہماری biological vitality ہے جو ہم میں اور کائنات میں مشترک ہے یہ vitality، idea of existenceکو قابلِ تصدیق بناتی ہے اور وجود کو اُس کے مظاہر ِ کثیر فراہم کرنے کا واحد ذریعہ ہے ۔ یہ اِس کی اہمیت ہے ۔
اِسی طرح اِس میں ایک principle (اصول) بیان ہوا ہے ۔ سرمد صہبائی صاحب کی ایک خوبی مجھے اچھی لگی کہ یہ منقطع نہیں ہیں ۔ محض جدید نہیں ہیں ۔ یہ قدامت پر قائم انفرادیت کے حامل ہیں ۔ اسی وجہ سے اظہار میں اِن کی انفرادیت جدید ہونے کی وجہ سے ہے۔ کیفیات، احساسات اور تخیل وغیرہ میں اِن کی جو انفرادیت ہے وہ اِن کے قدیم ہونے کی بدولت ہے۔ یہ دونوں کے بیچ میں ایک active برزخ کی طرح کردار ادا کرتے ہیں اُس کردار کے پیچھے جو اصول کارفرما ہے وہ جیسے چینیوں کی زبان میں یِن (Yin) اور یَانگ (Yang) ہے جو اُن کے اصولِ تخلیق ہیں کہ آسمان اور زمین مرد اور عورت ہیں اور ان کے ملاپ سے موجودات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک active principle ہے (یعنی ) آسمان اور ایک passive principle ہے یعنی زمین ۔ اِس سے سارا کارخانۂ وجود پیدا ہوا ہے۔ یِن اور یَانگ کی یہ جو theory of creation ہے یہ اِس مصرع میں جیسے کھپ گئی ہے۔ اِس مصرع کی اصل طاقت بن گئی ہے۔ اس مصرع میں پہلی مرتبہ اپنی vitality کے ساتھ express ہو رہی ہے گویا۔ وہ ابھی عرض کروں گا۔
اس (مصرع) میں ’’گُل‘‘ اور ’’چراغ‘‘، یہ یِن اور یَانگ ہیں ۔اسی طرح ’’ سینۂ گُل‘‘ دفینۂ جمال ہے ۔ یہ تخلیق کا، creation کا pole of passivity ہے ۔ ’’گُل ‘‘ creation کا passive pole ہے اور ’’چراغ‘‘ creation کا active agent ہے ۔ اِن دونوں کے ملاپ سے یہ (یعنی سینہ) ظرف ِ وجود پیدا بھی ہوا اور آباد بھی ہوا ۔ یہ واضح ہے بالکل، ابھی دیکھیے گا۔ اسی طرح اِس میں ایک تو ’’چراغِ مُشک بُو‘‘ خو د ایک بہت ہی نئی ترکیب ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں پڑھی۔ میں اتنا زیادہ تو پڑھا ہوا نہیں ہوں (لیکن) مجھے جیسے احساس سا ہے کہ یہ ترکیب اردو فارسی میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ یا چراغ کی یہ صفت (نہیں ملے گی) ۔ ’’چراغ ‘‘ جو ہے وہ ایک مستقل کردار ہے۔ شاعری کی سٹیج پر ایک مرکزی کردا رکی حیثیت رکھتا ہے ۔ (یعنی ) چراغ، بہار ، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو جو مرکزی کلمات ہیں poetic discourse کے ، اُن کو طرح طرح کے اوصاف بڑے بڑے شعرا دیتے رہے ہیں لیکن چراغ کا یہ وصف جو ہے یہ میرے خیال میں سرؔمد صہبائی نے دیا ہے۔ یہ الل ٹپ نہیں ہے جیسے آج کل وہ قرعہ اندازی کی طرح لفظ ڈال کے ڈبے میں (ہلا کر) اُسے پھینکتے ہیں۔ پھر جس سے جڑ جائے وہ استعمال کر لیتے ہیں ۔ ظاہر ہے وہ بھی نئے ہیں۔ تو یہ نیا پن تُکے سے نہیں ہے، بد سلیقگی سے نہیں ہے ۔ یہ محض نیا بننے کے مرض کا اظہار نہیں ہے ۔ یہ بہت بامعنی ہے، بہت پُر احوال ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں آگیا ۔ ابھی ان شاءاللہ یہ سب چیزیں دیکھیں گے۔ ابھی اِن کی نُدرت پر اور اِن کا جو معنوی جوہر ہے ناں (یعنی ) عناصر، جیسے اُن کو بیان کر رہے ہیں۔
پھر اِسی مصرع میں ’’چراغِ مُشک بُو‘‘، اس کا کیا مطلب ہوا۔ ابھی ’’چراغِ مُشک بُو‘‘ ہم نہ بھی کھولیں تو یہ (ٹکڑا) بتا رہا ہے کہ چراغ اپنی حقیقت کے ساتھ پہلی مرتبہ ظاہر ہے ۔ کیونکہ چراغ کو یہ مُشک بُوئی کا وصف کبھی نہیں ملا تھا۔ یہ وصف حاصل ہونےسے چراغ اپنے چھپاؤ میں سے نکل کر پہلی مرتبہ ظاہر ہوا ہے۔ یہ چراغ پہلے کبھی ظہور میں نہیں آیا تھا ۔اب جو چیز دوسروں کو ظاہر کرنے کے لیے ہے اس کے انہوں نے عجزِ اظہار کو ختم کیا ہے۔ بڑی بات ہے۔ یہ جو ’’چراغِ مُشک بُو‘‘جو ’’ عُریاں‘‘ہے یہ چراغ کی انتہائی صورت ہےیعنی جو اپنی حقیقت سے لفظی امتیاز تو رکھتی ہے یعنی لفظِ چراغ اور حقیقتِ چراغ میں لفظی امتیاز اور دوئی تو ہے لیکن وجودی دوئی نہیں ہے ۔ وجودی وحدت کے ساتھ لفظی دوئی ہے ۔ اب یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اگر ہم کسی بڑے ڈسکورس میں رکھ کر دیکھیں، کثرت کو پوری اٹھان کے ساتھ برقرار رکھتے ہوئے اُسے وحدت سے منسوب ہونے کے لائق بنائے رکھنا، یہ human perception (انسانی ادراک) کی سب سے بڑی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت ہے۔ جو شخص perception (ادراک) کے ایک اصول کو کیفیت اور احساس میں لا کر ایک تجربے کے طور پر بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو اُس کے جینوئن شاعر ہونے میں ظاہر ہے کہ شُبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ۔
اسی طرح اِس شعر کا جو دوسرا مصرع ہے ’’کوئی پہلوئے شب میں ہو رہا ہے ہُو بہو عُریاں ‘‘۔ اب یہاں جو ’’کوئی‘‘ہے اس کو ذرا سا focus کر کے دیکھیں ۔ا س کو سمجھنے کے لیے نہیں )بل کہ) اِس کو ڈھونڈنے کے لیے کہ میں اِس ’’کوئی‘‘ کو ذرا ڈھونڈوں تو سہی ، ذرا دیکھوں تو سہی ۔ پانے کی کوشش کروں یا اِسے نہ پا سکنے کا تجربہ حاصل کروں ۔ یہ ’’کوئی‘‘ اِس طرح کا چیلنج بن کر ہمارے سامنے آتا ہے ۔ یہ آپ کو آخرمیں یعنی ساری تگ و دو کے بعد کہ آپ اسے نہ دیکھ سکنے میں بھی ہوئے تو وہ بھی کام یابی ہے ۔ اسے دیکھنا بھی کام یابی ہے، اسے نہ دیکھ سکنا بھی بامرادی ہے۔ یہ ایسا ایک عجیب سا ’’کوئی‘‘ ہے کہ جس کو پانا اور نہ پانا یکساں درجے کی کام یابی ہو ۔ یہ ’’کوئی‘‘ معلوم سے زیادہ معلوم ہے ۔ یہ ’’کوئی‘‘ جو ہے ناں اس کی غرابت، اس کی اجنبیت، اس کا پوشیدہ پن غور سے دریافت ہوتا ہے۔ پہلی reading (پڑھت)، سرسری reading میں یہ ’’کوئی‘‘ جیسے نکرہ سا ہے لیکن یہ نکرہ نہیں ہے ۔ یہ نکرہ ہونے کی حالت میں رہتے ہوئے معرفہ بننے کی انتہا پر ہے ۔ یہ لفظ پر بڑی قدرت کی بات ہے ۔ اب یہ ’’کوئی‘‘معلوم سے زیادہ معلوم ہےاور اس کے ساتھ ساتھ نامعلوم سے زیادہ نامعلوم ہے۔ اِس جملے کو بس محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ میرا اَن دیکھا ، دیکھے ہوئے سے زیادہ دیکھا ہے (اور) میرا دیکھا ہوا میرے اَن دیکھے سے زیادہ چُھپا ہوا ہے ۔ اِن paradoxical کیفیات میں رہے بغیرہم اپنی موجودہ آدمیت کا دفاع نہیں کر پائیں گے کہ ہم آدمی بننے میں ناکام چلے آ رہے ہیں اور اِسی ناکامی میں اپنے خاتمے تک رہیں گے، اگر یہ سب ہم نے اپنے مقاصد کی حیثیت سے طے نہ کیے ۔ دوسرے پہلو سے یہ ’’کوئی‘‘ جو ہے ناں، کیوں کہ یہ پہلوئے شب میں ہے، یہ ’’کوئی‘‘ فطرت کا، حقیقت کا نسائی order (نظام) ہے/ نسائی ورژن ہے۔ entified idea of feminity ہے ۔ یعنی (اُس) چینی اصول پر اِس کو رکھیے ، ’’کوئی‘‘ وہ ہے ۔
اب ’’پہلوئے شب‘‘ (کا ٹکڑا)، یہ بھی بڑا نیا ہے یعنی شاعر کی قدرت جو ہے ناں، وہ اپنا naked اظہار نہیں کرتی۔ اُستادانہ کلام الگ ہوتا ہے ۔ بالکل عام سا لفظ معلوم ہو، عام سی ترکیب محسوس ہو اور وہ نئی ہو ۔ یعنی اُس کا نیا پن اُس کا qualified reader ہی دریافت کر سکتا ہے ۔ عام قاری اور شاعری کا average (اوسط) ذوق اور فہم رکھنے والا اُس سے مانوس حالت میں گزر جاتا ہے ۔ یہ ’’پہلوئے شب‘‘ اِسی طرح کی ایک ترکیب ہے ۔ ’’پہلوئے شب‘‘ (یعنی) رات کا پہلو/ رات کے برابر، یہ (لفظ) مَیں نے نہیں دیکھا۔
٭٭٭٭٭
’’پہلوئے شب‘‘ کو برتنے والے چند اشعار پیش خدمت ہیں، از حروف کار:
پہلوئے شب کل اسی چہرے سے روشن تھا مگر
جانے کتنے موسموں کی تلخیاں گنتے رہے (اشعر نجمی)
اے صاحب پر کیف بدن پہلوئے شب میں
ہاتھوں سے مرے کھلتے ہوئے بند قبا دیکھ (رونق حیات)
وہ جو رو رہا ہے پہلوئے شب
وہ صاحبِ نیاز ہوں (بشر امروہوی)
رند شب بیدار ، جا سو جا، سیاہی اوڑھ کر
خوابِ شیریں کے مزے لے پہلوئے شب چھوڑ کر (مخدوم محی الدین)
یہ تو ہے یا تھرکتی زندگی ہے پہلوئے شب میں
تری باتیں، ترا لہجہ، تری آواز، می رقصم (عبدالرحمن واصف)
٭٭٭٭٭
پھر یہ (ترکیب ’’پہلوئے شب‘‘) مفہوم بننے سے بھی منکر ہے۔ اِسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اِسے دیکھنے کی ، اِس میں جھانکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ بھئی، یہ جو لفظوں کا صحیح استعمال اور اس کی ایک mediocre (معمولی) روایت ہے تو اس کی روشنی میں اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ’’پہلوئے شب‘‘ سے مراد کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو یہ (کوشش) اناڑی پن ہے ۔ یہ اِس کی نُدرت کی ناقدری ہے۔ کیوں کہ دیکھے ہوئے کو سمجھے جانے سے بلند کر دینا ، یہ بڑے پینٹر/ بڑے شاعر کا کام ہوا کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بالکل عام سے لفظ ، بالکل عام سی دکھائی دینے والی ترکیب سے انھوں نے کتنی بڑی چیز برآمد کر کے دکھائی ہے۔
اسی طرح اِس شعر میں جو سب سے challenging بات ہے وہ ہے ’’ہُوبُہو عُریاں‘‘۔ یہ بھی بالکل نیا (لفظ) ہے ۔ کون کہتا ہے ’’ہُوبُہو عُریاں‘‘؟ کوئی یہ (کہے) کہ سر تا پا عُریاں/بالکل عُریاں لیکن’’ہُوبُہو عُریاں‘‘۔ یہ کیا چیز ہے؟ عریانی میں امتیاز نہیں ہوتا۔ سَو(100) ’’عُریاں‘‘ ایک ہی عریانی کے نمایندے ہیں (لہٰذا) اِس میں ’’ہُوبُہو عُریاں‘‘۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شعر کہاں سے صادر ہوا اور کہاں سے آمد ہوئی ہے اور کس طرف کو ہمیں یہ لے جا رہا ہے۔ اب اِس کو میں عرض کرتا ہوں۔ ’’ہُوبُہو‘‘کہا جاتا ہے کہ ایک اصول جو جانا ہوا ہے مانا ہوا ہے اور دیکھا ہوا ہے (یعنی) ایک مطلق اصول۔ تو اُس اصول سے مطابقت رکھنے کا دعوی رکھنے والی جو forms (بنتریں) ہیں اُن کو جب ہم تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو اُس permanent (مستقل) اور absolute principle (قطعی اصول) سے پوری طرح مشابہت اور مطابقت رکھتا ہے ۔ تو جو بھی forms (بنتریں) اپنے اُس essence (جوہر) سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہو گی، اُسے ہم کہیں گے کہ یہ’’ہُوبُہو‘‘ اصول ہے۔ یہ جُزو ’’ہُوبُہو‘‘ کُل ہے یا ’’ہُوبُہو‘‘ یہ جزو کے idea کے مطابق ہے۔ تو ’’ہُوبُہو‘‘ میں دوئی ضروری ہے۔ اِس میں دیکھیے کہ یہ دوئی کہاں سے قائم ہو گی۔ ’’ہُوبُہو‘‘ (یعنی) عَین اُسی طرح، عَین اُسی کی طرح، یہ ہے اِس کا مطلب۔ اب عَین اُسی طرح ’’عُریاں‘‘ / عَین اُسی کی طرح ’’عُریاں‘‘، یہ دونوں معانی یہاں مراد ہیں ۔
(اب ذرا) ’’اُس ‘‘ کو معلوم کر لیں پھر یہ شعر جیسے آدمی کو ایک نہایت نادر/نہایت productive تجربہ فراہم کا ضامن بن جاتا ہے۔ وہ ہے کہ idea of purity۔ ’’عُریاں‘‘ کا مطلب ہے کہ جس میں باطن نہ ہو یعنی جہاں باطن ظاہر بن جائے اظہار کی تمام بندشوں کو توڑ کر۔ سمجھیں اِس بات کو کہ باطن as such (جیسا کہ وہ ہے) ظاہر ہو جائے تو اس کے لیے ظہور اور اظہار کے جتنے بھی قوانین، حدود اور شرطیں ہیں وہ سب ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو جس ظاہر پر اظہار اور ظہور کی ساری شرطیں ٹوٹ گئیں، ساری تحدیدات ختم ہو گئیں، اور اُس کے پیچھے جھانکنے کو کچھ بھی نہیں رہ گیا، وہ عُریاں ہے۔ تو (سرؔمد صاحب) کہہ رہے ہیں کہ یہ اُس ’’عُریاں‘‘ کی طرح /اُس ظہور یافتہ باطن کی طرح ’’عُریاں‘‘ ہے۔
دوسرا، ’’عُریاں‘‘ کا مطلب ہوتا ہے pure as such یا thing-in-itself کا اظہار ۔ ایک idea of purity ہے ناں جو یوں کہہ لیں کہ خالص ہے ملاوٹوں سے پہلے، پھر اُس پر ملاوٹیں مسلط ہو جاتی ہیں اور اُسے ڈھانپ دیتی ہیں ۔ تو وہ خالص جسے ملاوٹوں نے ایسا ڈھانپ رکھا ہے کہ ہمارا ذہن، ہمارے حواس اُس کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں ۔ اُس کا تصور تو ہم رکھتے ہیں لیکن ہم اُس کا ادراک نہیں کر پاتے ۔ وہ (خالص) اگر اظہار پا جائے، تو اُس اظہار پانے کی حالت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے اندر پہلے سے موجود idea of purity کے عَین مطابق ہے ۔ اب ideal اور actual میں فرق ختم ہو گیا ہے۔ تو جہاں بھی ideaاور manifestation، جہاں بھی reality اور form ، جہاں بھی اِن کا فرق form سے مانوس perception کے لیے ختم ہو جائے، اُس سطح کو عُریانی کہتے ہیں۔ ’’عُریاں‘‘ as such ظاہر۔ تو یہ ہے ’’ہُوبُہو عُریاں‘‘۔ عریانی کی form، عریانی کے idea کا عَین ہے۔ اُس سے identical ہے۔ ’’ہُوبُہو‘‘ کا مطلب ہے عَین (identical)۔ کوئی دوئی وجودی نہیں ہے۔ اُن معنوں میں اب یہ form عریانی کا مظہر ہے یعنی اخلاص (purity) کا مظہر ہے۔ ملاوٹوں سے ہوئی صورت نہیں رہ گئی۔ بڑا زبردست ہے بھئی۔
اب اِس شعر کو جیسے ایک unit سمجھ کر فوکس کرتے ہیں ۔
’’سینۂ گُل کا کِھلا ہونا‘‘ تخلیقی order کے passive end (انفعالی نقطہ) کا تیار ہونا ہے ۔ تخلیقی آرڈر کے passive pole (انفعالی قطب) کا بیدار ہو جانا، conceive کرنے کے لیے وجود کو۔ ’’چراغِ مشک بُو‘‘ جس کو میں نے کہا کہ یہ active agent ہے تخلیق کا، اِس میں بڑی رعایتیں ہیں لفظوں میں ۔میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی نہیں آگیا ۔ چراغ کو مشک سے مناسبت دے رہے ہیں ۔ مشک اور مشک بوئی کو اس کا وصف بتا رہے ہیں ۔ یعنی چراغ مشک ہے اور اُس کا شعلہ اُس کی مہک ہے ۔ اب دیکھیے، کیسے کرنا ہے۔ مشک سیاہ ہوتا ہے ۔ مشک libido کا سمبل ہے ۔ مشک libido سے حاصل ہونے والی vitality کو کام میں لا کر ایک ecstasy میں بدل دینے کی علامت ہے۔ مشک ہرن کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اِس کی سیاہی وہی libido کی سیاہی ہے۔ اِس کی خوش بُو اپنے حامل / اپنے container کو بے حال رکھتی ہے /وارفتہ رکھتی ہے ۔ vitality کے ساتھ خود فراموشی میں رکھتی ہے ۔ یعنی اُس کی خودی کی طاقتیں جو ہیں جبلّت کی تحویل میں آکر وہ خودی کی ایک اعلیٰ درجے کی ضرورت پوری کر دیتی ہیں یعنی بے خودی کے تجربے سے گزار دیتی ہیں ۔ بے خودی کا کوئی بھی تجربہ libido کی کیفیت سے خالی نہیں ہو سکتا ۔ یعنی وصال کا کوئی بھی درجہ ہو، وہ ایک orgasmic state ضرور رکھتا ہے ۔ نشاط کا ہر end ایک orgasmic کیفیت ضرور رکھتا ہے چاہے وہ نشاطِ روحانی ہو چاہے نشاطِ جسمانی ہو ۔ اب مشک (کو) آپ سمجھیں کہ وہ center of libido ہے ۔ اُس کی بُو جو اندر ہی اندر ہے وہ باہر نہیں نکلتی ۔ ہرن کے پیٹ سے مشک کی بُو نہیں آتی لیکن وہ اُسے دیوانہ بنائے رکھتی ہے۔ اپنی basic biological drive اور vitality کے ساتھ روحانی طور پر بے خودی کے تُند احوال سے گزرنا، یہ ہے ’’چراغِ مُشک بُو‘‘ ۔ جس کا خمیر مُشک ہے اور شعلہ اُس مشک سے پیدا ہونے والا ایک ایسا passion جو Bio-centric ہے اور Bio-centric ہوتے ہوئے spiritual ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔
اب یہ کہ ’’چراغِ مشک بُو عُریاں‘‘ یعنی وہ تخلیقی vitality، جو کسی بھی سیاق و سباق/ کسی بھی ملاوٹ/کسی بھی تحدید، حتی کہ جبلّی جبلّت ہونے کے باوجود، جبلّی ہونے کے ماحول سے ماورا، وہ آج منکشف ہو گیا۔ یعنی libido نے اپنی حقیقت کو اُس کے میٹافزیکل سیاق و سباق اور اُس کی spiritual نشاطیہ کیفیات کے ساتھ اظہار دے دیا۔ چراغ کیا ہے کہ اُس کے شعلے میں حرارت ہے ۔ وہ حرارت جو اگر روح تک نہ پہنچے تو روح مر جائے گی ۔ اور اُس میں وہ روشنی ہے جو روشنی ذہن تک اگر نہ پہنچے تو ’ میں کیا ہوں‘کا جواب میسر نہیں آ سکتا ۔ تو اِس چراغ کی دیوانگی / اس چراغ کی سیلابِ جذب / اِس کا جو طغیانِ مجذوبی ہے وہ مجھے آج پہلی مرتبہ بلا کسی آمیزش کے دکھائی دیا ۔ یا وہ بلا آمیزش کے خود کو ظاہر کیے ہوئے ہے کسی سے بھی personify ہوئے بغیر ۔
اب یہ کہ اتنے بڑے تخلیقی ماحول میں /اتنے بڑے cosmological نشاطیہ سمفنی کی گونج میں، اب ہو کیا رہا ہے ؟ ’’کوئی پہلوئے شب میں ہو رہا ہے ہُوبُہو عُریاں‘‘۔ اب آپ وہ’’کوئی‘‘ جو میں نے عرض کیا تھا ، وہ ’’ کوئی ‘‘جو تخلیقِ وجود کے active منہج اور passive principle دونوں کو چلاتا ہے دونوں سے ماورائی کی حالت میں ۔ آج اُس نے شب کے پہلو میں خود کو اظہار دیا یعنی اُس نے غیب کے اندھیرے کو برقرار رکھتے ہوئے اُسے ’’ چراغِ مُشک بُو ‘‘کی روشنی میں ظاہر کیا ۔ خود کو ظاہر کیا ہوا ہے ۔ یہ شب، غیب کا اندھیرا ہے اپنے end meaning میں ۔ لیکن اپنے ابتدائی meaning میں اِس طرح کی شبِ وصل ہے جو آدمی کے اندر کے چاند اور سورج کو گویا چمکنے کی space دیتی ہے۔
اب آپ دیکھیں نا ں کہ کتنا بڑا (کینوس) ہے کہ سارا کارخانۂ تخلیق اپنے پاؤں سے سر تک متحرک حالت میں ہے، اُس کی پوری تصویر کھینچ دی اور اُس تصویر میں یہ بھی دکھا دیا کہ یہ سارا جو passionate نشاطیہ ہے، یہ سارا جو vitalityاور لذّت سے بننے والی کاسمک سچویشن ہے، یہ چلائی کہاں سے جا رہی ہے۔ وہ ہے ’’کوئی‘‘۔ اب یہ ’’کوئی‘‘ آپ اپنی مرضی کا رکھ لیں، میں اپنی مرضی کا رکھ لوں، بس اُس کی transcendence باقی رہے۔ بڑی بات ہے۔
٭٭٭٭٭
اسی طرح دوسرا شعر جو ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پر اتنے تجزیے کی ضرورت نہ ہو ۔ لیکن اُس میں بھی کوئی نہ کوئی حُسن ایسا ہے جس کی نشان دہی ضروری ہے۔ اِس لیے میں یہ تمام شعر اِس غزل کے پڑھ رہا ہوں ۔
کلی کے نرم تَالو میں کوئی نقشِ دمیدہ ہے
حجابِ نیم وا میں ہے کوئی شوقِ نمُو عُریاں
یہ شعر پہلے شعر کی طرح چُست اور بڑے passion اور بڑے تخیل کا آمیزہ تو نہیں ہے ۔ لیکن یہ بہت کثیر المعانی ہے، کثیر الجہات ہے، fixity سے پاک ہے ۔ اِس کا جو اصل حُسن ہے کہ اس نے احساساتی تضاد اور تنوع کو اپنے اندر سمو لیا ہے ۔ تو جو لوگ احساسات کو اور کیفیات وغیرہ کی شاعری میں اہمیت اور حیثیت اور معنویت جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں ۔ظاہر ہے کہ یہ کتنا بڑا وصف ہے کہ آپ متضاد کے ساتھ ہوں ان کے تضاد کے ساتھ ہوں ۔ ان کے تضاد کو مدہم کیے بغیر اُن کو ایک variety کے یونٹس میں بدل کے دکھا دیں ۔ یعنی تضاد کو تضاد رکھتے ہوئے تنوع بنا کے دکھا دیا گیا ۔ یہ بڑی بات ہے احساسات میں ۔ یہ خیالات اور افکار میں ہو، تو سمجھ میں آتی ہے لیکن احساسات میں ایسا کرنا کہ آدمی ادھر ٹھنڈک محسوس کر رہا ہے تو ٹھنڈک ہی میں کوئی نکتہ حرارت کا بن جاتا ہے ۔ تو حرارت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ حرارت جو ہے وہ نمی بن جاتی ہے۔ اِس طرح چل رہا ہے یہ شعر۔
اب اِس (شعر) میں دیکھیے کہ ’’کِلی کا نرم تَالُو‘‘ یہ بھی عجیب (ترکیب) ہے ۔ مَیں نے تو نہیں پڑھا کہیں ’’کِلی کا نرم تَالُو‘‘ ۔ یعنی کلی کا منہ کُھل رہا ہے ۔ کیونکہ وہ ابھی پھول بننے کے مرحلے میں ہے ابھی اس کا منہ کُھلنا شروع ہوا ہے ۔ اُس کا تَالُو ابھی نرم ہے اور اٗس نرم تَالُو جس کے نرم اور گداز باطن کے دروازے پر ایک ’’نقشِ دمیدہ‘‘ بنا ہوا ہے ۔ اب یہ ’’نقشِ دمیدہ‘‘بھی بالکل نئی ترکیب ہے۔ دَمیدہ کہتے ہیں دَمیدن، پُھولنا کِھلنا، نمو پانا۔ یہ دمیدن جو (فارسی) مصدر ہے اُس کا یہ مطلب ہے اور اُبھر آنا جیسے کوئی چیز اُبھر آئے تو اُس عمل کو بھی دمیدن کہتے ہیں۔ ’’نقشِ دمیدہ‘‘ تو ایسے ہے جیسے کوئی نقش بنایا جا رہا ہے۔ کوئی نقش ہے جس کے بننے کی حرکت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ متحرّک نقش ہے ۔ یہ بہت خوب صورت تصویر بندی ہے کہ کَلِی میں جھانک کے دیکھو ، تو اُس کے تَالُو میں یعنی جتنا اُس کا باطن فی الحال دکھائی دے رہا ہے اُس باطن کے دروازے پر کوئی نقشِ دمیدہ جو ہے وہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ نقشِ دمیدہ جب بننے کا عمل پورا کر لے گا ، تو کلی اپنی منزلِ وجود تک پہنچ جائے گی ۔ اب یہ ’’نرم تَالُو‘‘ کیا ہے ؟ دیکھیے کہ نرم تَالُو کو کیسا انھوں نے لفظی رعایت دی ہے۔ کلی کا نرم تَالُو کُھلتے ہوئے منہ سے فی الحال نظر آ سکنے والا تَالُو ، اُس کے پیچھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ، یہ ’’حِجابِ نِیم وَا‘‘ ہے ۔ یعنی کلی بند ہونے کی حالت میں حجاب میں ہے ۔ اب وہ کِھلنے کے ابتدائی مرحلے میں /درمیانی مرحلے میں اب ’’حِجابِ نِیم وَا‘‘ ہے ۔ نہ پورا دکھائی دے رہا ہے اور نہ پورا چھپا ہوا ہے ۔ تو اِس حجابِ نیم وَا یعنی تَالُو جو ہے اِس کو سمجھیں آپ کہ حجابِ نیم وَا ہے۔ تو حجابِ نیم وَا میں ہے کوئی شوقِ نُمو عُریاں ۔ یہ جو اِس کے کِھلنے کا عمل ہے یہ اِس کا شوقِ نمو ہے لیکن ہم نمو کو ایک عام سے انگونِ شگفتن کے تابع رکھنے کے عادی ہیں ۔ وہ سب botany وغیرہ پڑھ کے تو ہم اُس کیفیت کو یا اُس پورے نظام ِ نمو کو سمجھ نہیں سکتے جس کے پیچھے نمو پانے والوں کی خواہش کا زور دکھائی دے۔ نمو وہی پاتا ہے جو خواہشِ نمو ہوتا ہے ۔ اب یہ بڑی زبردست (بات ہے) یعنی نیا مفہوم بھی ہے ، نیا مضمون بھی ہے ۔ بہار اور شگفتن اور دِیدن وغیرہ کی ایک نئی تعبیر بھی ہے ۔ پھر کلی اور بہار کا جو پورا خانوادہ ہے اُس کو نئے زاویے سے دیکھنے کی کھڑکی بھی ہے اِسی میں چھپی ہوئی ۔ غرض ’’حِجابِ نِیم وَا‘‘ اور ’’عُریاں ‘‘میں تضاد کی نسبت ہے۔ یہ استادانہ بات ہے۔
اور پھر’’کوئی شوقِ نمو عریاں‘‘، یہاں بھی ’’کوئی‘‘ جوہے جو پہلے مصرع میں تھا ۔ یہاں بھی ’’کوئی ‘‘جو ہے وہ مشخّص نہیں ہے ظاہر ہے ۔ وہاں تو ’’کوئی’ ایک ذات کی طرح ہے ناں ۔ یہاں ’’کوئی ‘‘ ایک قسم کی طرح ہے ۔ ’’شوقِ نمو‘‘ کی کوئی قسم ہے یا ’’شوقِ نمو‘‘ as such ہے ۔ یہ ’’کوئی ‘‘جو ہے متعین بھی ہے اور غیر متعین بھی ہے۔یعنی fixed بھی ہے اور fixity سے پاک بھی ہے۔ یہ دونوں اوصاف ِ وجود ہیں ۔ یہ دونوں حضورِ علم ہیں ۔ اِن دونوں کو یک جا کرنا گویا تضادات کو ایک کرنے کا عمل ہے۔ یہ شاعرانہ منطق ہے جو تضادات کے جمع ہونے کو جسے عقل محال کہتی ہے، اُس محال کو خوب صورت بنا دیتا ہے۔ اُس محال کو جمالیاتی خلاقی سے ممکن بنا کے دکھا دیتا ہے جیسا کہ اِس شعر میں ہے۔
٭٭٭٭٭
ہُمکتی ہے بلوغت کی مہک اُس کُنجِ کم سن میں
خمِ زہرہ پہ ہوتا ہے غُبارِ سبز مُو عُریاں
ہر جگہ نئی نئی باتیں ہیں ۔ نئے نئے لفظ ہیں ۔ اب ’’کُنجِ کم سن‘‘ (ہی لیجیے) ۔ کم سن کوئی کردار بھی ہے ۔ فر ض کیا کہ کم سن انسان ہے۔ اب اسی کو ’’کُنجِ کم سن‘‘ کہہ کر گویا اسے اپنی اس حد سے رہائی دلوا دی ہے یعنی اُس کے ’’مَیں ‘‘ کو generalize کر دیا ہے ۔ اُس کا ’’مَیں ‘‘ اب generic ہو گیا ہے ۔بہرحال حُسن پیدا ہونےکے کئی اسباب ہیں جو ہم اپنے طور پر اپنے اپنے ذوق کے مطابق اِس سے منسوب کر سکتے ہیں ۔
اب جو آدمی شاعری کی روایت ، مائتھالوجی کی روایت کو نہ جانتا ہو ناں ، تو اُس کے لیے یہ (دوسرا) مصرع مشکل ہے ۔ ’’خمِ زہرہ‘‘ کیا ہوتا ہے اور ’’غُبارِ سبز مُو‘‘ کسے کہتے ہیں۔ اور پھر ’’عُریاں ‘‘ اور غیرِ عُریاں کی اس میں تقسیم کیا ہے ۔ زہرہ ایک سیارہ ہے ناں ، اس کے اوصاف ہیں حُسن و عشق والے ۔ وہ مُطربہ ہے ناں ۔ تو ’’خمِ زہرہ‘‘یعنی زہرہ کا خم ، بالکل اِس کو literal mind میں لیں ، یہ جو بربط /ستار وغیرہ بجا رہی ہے تو اِس کا خم ۔اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ خم ہم نے اِس معنی میں لے لیا تو ’’غبارِ سبز مُو‘‘ کا جواز اور جگہ نہیں بنتی ۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم خم کو عام مفہوم میں نہ سمجھیں ۔ اب یہاں خم کچھ اور ہے ۔ اب اپنے اپنے زہرہ کا خم ہر آدمی فرض کر سکتا ہے ۔ مطلب یہ کہ زہرہ میں جب لڑکپن سے ، کم سنی سے بلوغت آئی ، کم سنی سے بالغ ہونے کی حرکت نے اُسے جھکا دیا اور اِس جھکاؤ میں اس کے رخسار پر خط نمودار ہوا ۔ اب اس کو سمجھ رہے ہیں ناں کہ لڑکپن سے نوجوانی میں جانا ، یعنی چہرے پر کان کے پاس خط کے آثار پیدا ہو جانا ، یہ اس کا پورا locale ہے ۔ اس کا پورا دائرہ یہ ہے ۔ اب اس دائرے میں بات کتنی خوبصورتی سے کہی ہے یہ دیکھنا ہے ۔ اب یہ کہ ’’کُنجِ کم سن‘‘ اور ’’زہرہ‘‘ یہ ایک ہیں ۔ وہ کنج کم سن (یعنی) کم سنی کے کنج سے نکلا ہے تو خم پیدا ہوا ہے۔اب وہ نوجوانی کے آثار اُس میں بیدار ہو گئے ہیں (مگر) ابھی یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ اس نے جمالیاتی طور پر ترقی کی ہے کہ اِس کا تنزل ہے۔ خم ہونا خوبصورتی بھی ہے اور خم ہونا کمزوری بھی ہے۔ اب یہ شعر جیسے پڑھنے والے کے تخیل کو آزادی دیتا ہے کہ وہ جس زاویے سے چاہے دیکھ لے ، یہ شعر اُس کے لیے fulfilling ہو گا ۔ اب اس میں ’’غبارِ سبز مُو‘‘ ۔۔ جیسے وہ ہے ناں غالؔب کا شعر،
سبزۂ خط سے ترا کاکل سرکش نہ دبا
یہ زمرد بھی حریف دم افعی نہ ہوا
یا میؔر نے اور زیادہ اور طرح سے باندھا ہے ، ’’اُس کا رخِ مقطعت قرآن ہے ہمارا ‘‘۔ خیر وہ تو حد سے گزر گئے ۔
’’سبزۂ خط‘‘ میں غالب نے جو ایک رنگینی سی پیدا کی تھی اُس میں اضافہ انھوں (یعنی سرمؔد صہبائی ) نے کیا ہے ۔ وہ یہ کہ ’’سبزۂ خط‘‘ کو غبار سے تشبیہ دی ہے ۔ ’’غبارِ سبز مُو پیدا ‘‘ ، یہ ترکیب بھی یقیناً نئی ہے ۔ ’’غبار‘‘ یعنی غبار کی صفت ہے اُس کا سبز مُو ہونا ۔ (یعنی) غبار ایک character ہے جس کے بال جو ہیں سبز ہیں ۔ عجیب سا ہے مطلب یہ image کرنا بہت مشکل لیکن یہ مشکل بہت پُر لطف ہے ۔ تو ’’خمِ زہرہ‘‘پر’’غبارِ سبز مُو‘‘ جو ہے وہ اپنا انکشاف کر رہا ہے ۔ یہ ’’غبارِ سبز مُو‘‘ جسے حُسن کی غلط ترجمانی کے نظام نے ڈھانپ رکھا ہے اس نے اُن حجابات کو اپنے اوپر سے ہٹانے میں کامیابی حاصل کر لی ’’خمِ زہرہ‘‘ کی مدد سے ۔ تو ’’خمِ زہرہ‘‘ نے جب اِس کو اپنا لیا تو یہ گویا تمام ملاوٹوں، تمام حجابات سے آزاد ہو کر اِس کا حصہ بن گیا ۔ اِس کے لیے تسکینِ مزید کا سبب بن گیا ۔ بڑا مطلب کمال (شعر) ہے۔
٭٭٭٭٭
اسی طرح بھئی جلدی سے یہ غزل تو پڑھ لیں ورنہ بڑا وہ ہو جائے گا ۔
عجب اک خلوتِ دیدار میں گم ہو گئی آنکھیں
دمِ حیرت نہیں کھلتا کہ یہ میں ہوں کہ تُو عُریاں
’’خلوتِ دیدار‘‘ بھی نئی ترکیب ہے ۔ اب اس میں دیکھیں کہ ’’خلوتِ دیدار‘‘ میں آنکھوں کا گم ہو جانا ، مطلب یہ عجیب شاعر ہیں کہ شعر کو البم بنا دیتے ہیں ۔ وہ جیسے ایک تصویر نہیں ہوتی ، وہ البم کی طرح ہوتا ہے ۔ جیسے البم خود کو پلٹتا جا رہا ہے ۔ یہ ’’خلوتِ دیدار‘‘ کیا تصور ہے؟ یعنی جب دیکھنے اور دیکھے جانے والوں میں دوئی ختم ہو جائے تو آنکھیں بے جواز ہو جاتی ہیں ۔ آنکھیں اپنا کام بھول جاتی ہیں ۔ یہ مطلب ہے اِس کا ۔ تو پھر جب آنکھیں ہی فضول ہو گئیں ، جب آنکھوں ہی کی ضرورت ختم ہو گئی تو پھر purity کے اس ماحول میں پتہ نہیں چلتا کہ مَیں کون ہوں اور تُو کون ہے۔ جب دیکھنے والا اور دکھائی دینے والا ، دیکھنے اور دکھائی دینے کی سطح سے بلند ہو کر آپ کے سامنے ہیں یا ایک ہی سطحِ غیب اور ایک ہی دائرۂ ظہور میں ہیں تو پھر یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مَیں کون اور تُو کون ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مَن و تُو سے عریاں /پاک ، مَن سے پاک مَیں ، تُو سے پاک تُو ، مَن سے پاک تُو اور تُو سے پاک مَن ۔ یہ کیفیت اور یہ سچویشن تجربے میں آجائے تو کوئی پرانی یاد مَن و تُو کی ذہن میں ابھر بھی آئے تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ مَیں کہاں ہے اور تُو کہا ں ہے ۔ کون خالص ہو گیا ہے اپنی وجودی ملاوٹوں سے ؟ مَیں یا تُو ۔ کیا کہنے ، بہت خوب ۔
مَن و تُو جو ہیں ناں وہ حجابات ہیں ۔ یہ حجابات اگر اٹھ جائیں تو مَن و تُو کے درمیان امتیاز ظاہر ہے کہ ختم ہو جائے گا ۔ تو یہ حجابات جب اٹھ گئے تو مَن و تُو کی دھندلی سی یاد نے مسئلہ کھڑا کر دیا کہ مَیں کون تُو کون ۔
٭٭٭٭٭
اُسی چشمِ فسوں سے جسم و جاں کی رُت بدلتی ہے
کفِ دستِ حنا میں ہے گُلِ صد آرزو عُریاں
اب جیسے میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ ’’چشمِ فسوں‘‘ عجیب سا ہے ۔ قاعدے کے مطابق ٹھیک ترکیب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کا حُسن جو ہے وہ اس کے خلافِ قاعدہ ہونے کو قابلِ التفات بنا دیتا ہے ۔’’اُسی چشمِ فسوں سے جسم و جاں کی رُت بدلتی ہے ‘‘یعنی ایک افسوں ہے جو لذّتوں سے ، نشاط سے ، وفور سے ، جذب و مستی سے بھرا ہو اہے اور وہ کہیں سے آ اور کہیں جا نہیں رہا۔ بل کہ سب چیزیں اُس گردبادِ نشاط میں گویا چکر کھائے جا رہی ہیں ۔ اِسی میں جسم و جاں کی جیسے رُت بدل گئی ، موسم بدل گیا یعنی جسم و جاں کی تمام تحدیدات ٹوٹ گئیں اور جسم و جاں کو ابدیت دینے والا موسم نصیب ہو گیا اِس گردبادِ طلسمات سے ۔ اب اس میں ہے کہ لگ رہا ہے کہ اب یہ کیفیت جو مجھے میسر آئی ہے اس کیفیت میں بس ایک ہی چیز دکھائی دے رہی ہے اور وہ ’’ کفِ دستِ حنا میں ہے‘‘ یعنی مہندی لگے ہاتھوں کی ہتھیلی پر ’’گُلِ صد آرزو عُریاں‘‘ ہے ۔ اب تصویر کی طرح بس لذّت لیں اِس سے ۔ لیکن معنی اِس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر افسونی perception میں دستِ حنائی چراغِ آرزو نہیں پکڑتا ۔ محبوب کو آرزو نہیں ہے لیکن یہ جو ایک نئی کنڈیشن پیدا ہو گئی ہے اس میں آرزو محبوب کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ اس آرزو کو اپنا کر عاشق کے نظامِ آرزو کو بدل دے۔ اُس میں ہے کہ ’’کفِ دستِ حنا میں ہے گُلِ صد آرزو عُریاں‘‘۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سینکڑوں نئی آرزوؤں ، نئی مرادوں کا جمع ہو کر جیسے flowering کا عمل اب شروع ہوا ہے ۔ تو نئے امکانات ، نئی آرزوئیں ، جمال کے نئے perception ، وجود کے نئے نشاطیہ احوال ، ان سب کا خلاصہ “گلِ صد آرزو” یعنی سب آرزوئیں flower ہو رہی ہیں اُس ہاتھ میں، جو ہاتھ جمال کا ہاتھ ہے محبوب کا ہاتھ ہے ۔ کیونکہ چیزیں محبوب کے حوالے سے مل کر دوام پیدا کرتی ہیں ۔ تو اب جو آرزوئیں اِس نئے نظام میں پیدا ہو رہی ہیں وہ آرزوئیں پوری ہونے کی متمنی نہیں ہیں ۔ یعنی اُن آرزوؤں کا کوئی مقصود اُن سے باہر نہیں ہے’’ کفِ دستِ حنا میں ہے‘‘ میں ہونے کی وجہ سے۔
٭٭٭٭٭
بھئی، یہ تو سارا مضمون ساری کیفیت پوری روایت کو ایک آدمی بدل رہا ہے ناں ۔ کیفیات کی روایت کو، لفظ کی روایت کو ،تصویر بننےکی روایت کو ۔ اور کیا کیا تعریف کریں ۔ آج اتنا ہو گیا ۔ اب جو ہے اگلی مرتبہ پھر کوئی اور دیکھیں گے ۔
(ختم شد)