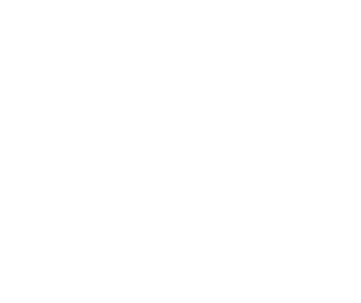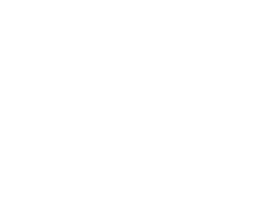کتابیں جو اِمسال پڑھی گئیں۔ تحریر: ذکی نقوی
ایک کتاب خواں کیلئے اپنی پڑھی گئی کتابوں کا تذکرہ کرنا یک گونہ مسرت کا باعث ہوتا ہے اور نئے پڑھنے والوں کیلئے اس میں یہ آسائش ہوتی ہے کہ اس مصروف زمانے میں کتاب پڑھنے کیلئے انتخاب کا کڑا مرحلہ بآسانی طے پا جاتا ہے۔ اس بات میں تو دوسری رائے ہو بھی سکتی ہے لیکن کتاب کا اور بالخصوص اچھی کتاب کا حق ہے کہ اسے تعارف ملے، اسے متعارف کروایا جائے۔ زیرِ نظر تحریر صاحبِ مضمون کی اس سال کی پڑھی جانے والی کتابوں پہ مختصر رائے اور تبصرے پر مشتمل ہے اور کوئی بڑا اکیڈمک ریویو تو شاید نہ ہو مگر تعارف کے لئے چند سطور پیش خدمت ہیں۔
”سندھو“ (ناولٹ) جیم عباسی: یہ ایسا فن پارہ ہے کہ اس پہ مجھ ایسا مبتدی کیا تنقید کرے گا؟ بس یہی کہوں گا کہ ”سندھو“ کی معصومیت اور پاکیزگی اور شفاف حُسن نے جس میں ایک تہذیب کا گم گشتہ عہد جھلکتا ہے، دل کو موہ لیا۔ ارون دھتی رائے نے اپنے ناول ”بے پناہ شادمانی کی ملکیت“ کے بارے میں کہا کہ اسے میں نے کئی زبانوں میں سوچا جس سے ایک اور زبان وجود میں آئی جس میں یہ ناول میں نے لکھا ہے۔ جیم عباسی نے بھی یہی کمال کیا کہ ایک اچھوتے موضوع کے لیے ایک نئی زبان تخلیق کی جو نئی ہو کر بھی آپ کے میرے دل میں اترنے والی ہے!
”آزادی“ (فریڈم، فاشزم، فکشن) ارون دھتی رائے: مضامین کا اردو ترجمہ سید کاشف رضا نے کیا ہے اور ہندوستان میں مذہبی انتہا پسندی، تنگ نظری، اقلیتوں کے مسائل اور وہاں کی شناخت کی سیاست پر ایک خوبصورت کتاب جس میں وہاں کے ادب پہ بھی بات ہوئی ہے۔ محترمہ نے ایک شاندار نکتہ بیان کیا ہے کہ ہندوستان ایک ملک نہیں تھا، ایک کانٹینینٹ تھا، یہی اس کی عظمت تھی، مودی جی اسے ایک ملک بنانے کے چکر میں ہیں اور وہاں بھی ایسے جہلاء کی کمی نہیں جو اسے عظمت سمجھتے ہیں۔
”اس شہر میں اک شہر تھا“ (ناولٹ) جیا جاودانی: سندھی سے اردو ترجمہ اجمل کمال صاحب نے کیا۔ ایک ناول جو دراصل سندھ سے بھارت ہجرت کر جانے والے ایک ہندو کی حقیقی کہانی ہے، جو یادوں کی بازآفرینی کیلئے دوبارہ سندھ جاتا ہے۔ نہایت خوبصورت کہانی۔ جذبوں سے بھی اور یادوں کی حسین بارات۔
”رولاک“ (ناول) رفاقت حیات: رفاقت حیات کا ناول ”رولاک“ ٹھٹھہ کے تاریخی شہر میں جنم لینے والے ایک عام لڑکے کی کہانی ہے۔ ایک فریم سازی کی دُکان والے کا بیٹا جس کی مختصر سی زندگی فقط دو شہروں کے محدود سے سیٹ پر گزری ہے مگر یہ کہانی ایک پوری نسل… نہیں، کئی نوجوان نسلوں کی زندگی کے اس پہلو کو اپنے کینوس پہ سمیٹتی ہے جسے ہر عہد کے بڑوں نے بڑی بے اعتنائی سے نظر انداز کیا ہے۔ ہمیں بیٹے چاہئیں، شاہ لطیف کے مزار سے مانگ کر لاتے ہیں، داتا دربار سے، امام بری سے، مکے مدینے سے، نجف اشرف سے، ہر جگہ سے مانگتے ہیں مگر جب یہ بیٹے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے وجود، ان کی شخصیت اور ان کی جداگانہ ہستی کا انکار کیوں؟ لال بخش ایک بدکردار، ہوس کا مارا اَن پڑھ باپ ہے جس کا بیٹا قادر بخش اس کہانی کا مرکزی کردار ہو کر بھی کسی کہانی کا مرکزی کردار نہ بن سکا کیونکہ اس کی زندگی سے جڑی ہر کہانی پر اس کے باپ نے قبضہ کر لیا ہے… اور ستم ظریفی دیکھیے، قادر نام کے لڑکے کے مقدور میں کچھ بھی نہیں… اسے تو محبت بھی نہ کرنے دی گئی!
پھر اس کہانی میں جو ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، جو عہد ہے، جو ثانوی بلکہ بظاہر غیر اہم کردار ہیں، وہ اتنی خوبصورتی سے تصویر کیے گئے ہیں کہ اپنی توجہ کھینچ لیتے ہیں۔ چھے سو انہتر صفحات کے اس ناول نے باوجود مصروفیت اور پڑھنے کی کم رفتار کے، اتنا کھینچا کہ پانچ دن بھی تو نہ لگے ہوں گے پڑھ ڈالنے میں۔ اور کہانی نے کہیں بوجھل بھی تو نہیں کیا! محاکات اور تفصیلات یا منظر نگاری کہیے کہ ان پونے سات سو صفحات میں ہم نے سات زمانوں کی سیر کی! سندھ دھرتی کے جادو سے کسے فرار ممکن ہے؟ مگر پھر کہوں گا کہ کہانی کا پلاٹ اتنا سادہ ہے کہ بظاہر قادر بخش کے بچپن، لڑکپن اور نوجوانی کا قصہ ہی تو ہے مگر جو نفیس تہیں ہیں، انہیں ساتھ ساتھ پلٹ کر دیکھیے تو ان میں بہت کچھ پڑھنے کو ہے۔
انسان کی نفسیات، زندگی اور وجود کی ناقابل برداشت اذیتیں، محبت کی لطافت، اس دنیا کی ہیئت، کتنے خوبصورت فلسفے ہیں جو بڑی سادگی سے عیاں ہیں اس کہانی میں۔ یہ بات رفاقت حیات کا تخلیق کردہ کردار قادر بخش ہی کہہ سکتا ہے کہ ”یہ دنیا جہنم کا وہ پچھواڑا ہے جہاں خدا انسانوں کو آوارہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے فراموش کر چکا ہے“ اور یہ کہانی کتنی خوبصورتی سے اس دعوے کو نبھاتی ہے، پڑھ کر دیکھ لیجیے! حقیت سے اتنا قریب تر ہے کہ بقولِ سلیم الرحمن صاحب ”حقیقت پسندی میں جدّت کے نام پر تمام قلابازیوں کے باوجود آج بھی بڑا دَم ہے“ اور یہ بڑی دَم دار کہانی ہے۔
اور ہاں، ایک لڑکا ہی کیوں، قادر بخش کی ماں کا کردار بظاہر ایک نہایت غیر اہم کردار ہے مگر مشرقی عورت، یا یوں کہہ لیں کہ یہاں کے عام آدمی کے طبقے میں جو ایک نظر انداز کیے جانے والی اکثریت ہے، یعنی گھریلو عورت، بھی اس کہانی میں جس طرح موضوع بنی ہے، اس میں ہاجرہ مسرور، خدیجہ مستور والی افسانوی بے چارگی ہے نہ پاپولر فکشن والی خوشحال عزت مآبی ہے جو غریب طبقے کی عورت کے مکمل خدوخال نہیں ہیں۔ ماروی، حسینہ، صغراں اور سومل جیسی لڑکیوں کے کرداروں نے بھی دھرتی کی عورت کے چہرے پہ لکھی کئی دُکھ کی داستانیں بیان کر دی ہیں اور اصل کہانی کی روانی کو متاثر نہیں کیا۔
زبان… جو میرا، اردو کا طالب علم ہونے کے ناتے ایک اہم کنسرن ہوا کرتی ہے، لاجواب! جان دار! بناوٹ سے پاک، ادبی زبان نہیں ہے بلکہ جدید دور کے معیاری ادب کی زبان ہے۔ ”رولاک“ سندھی زبان میں آوارہ گرد کو کہتے ہیں اور رفاقت حیات صاحب کے اس ’رولاک‘ کے ساتھ کی گئی آوارہ گردی میری فکشن اور مطالعے کی دنیا کی نہایت خوبصورت آوارہ گردی تھی۔
”یُونہی“– ”عشرے“ ادریس بابر صاحب کی شاعری کی کتابیں: میں شاعری کی کتابیں پڑھنا تقریباً ترک کر چکا ہوں ماسوائے اس کے کہ کبھی کبھی اساتذہ کے کلام سے ثواب کی نیت سے تلاوت کر لی۔ معاصر شعراء میں ادریس بابر صاحب کا دلدادہ ہوں۔ اردو نظم میں دس مصرعے کی صنف ’عشرہ‘ سماجی، سیاسی اور فرد کے دکھوں کو نظم کرنے کا خوب ذریعہ بنی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پڑنے کے بعد ہمیں ایک بالکل الگ دنیا میں جینا پڑ رہا ہے، معاشی عدم استحکام اور سیاسی تماش بینی کے اس عہد میں بہت سے موضوعات کی بادہء ناخوردہ رگِ تاک میں پڑی تھی مگر ادریس بابر اُن گنے چُنے اساتذہ میں ہیں کہ اس کی ساقی گری کی اور خوبصورتی سے کی۔ غزل میں بھی کیا خوبصورت اسلوب پایا ہے۔ بابر صاحب زبان کے ساتھ بھی منفرد تجربے کرتے ہیں جو اردو جیسی جاں بلب زبان کیلئے ’رسک‘ ہے مگر ان استاد کا کوئی نشانہ خطا نہیں جاتا۔
ہاتھ دنیا کا بھی ہے دل کی خرابی میں بہت
لیکن اے دوست تری ایک نظر سے کم ہے
خاک اتنی نہ اڑائیں تو ہمیں بھی بابر
دشت اچھا ہے کہ ویرانی میں گھر سے کم ہے
کچھ درخت اپنی جڑیں ساتھ لئے پھرتے ہیں
اس کو مجبوری سمجھ لیجئے، ہجرت کیسی؟
ایک گمنام سمندر ہی ملے گا تہِ خاک
یہ بھی نقشہ کسی معروف خزانے کا نہیں
”مقتل لہوف“ سید ابن طاؤس: بنیادی طور پر ایک تاریخی کتاب ہے جس میں سانحہ ء کربلا کے واقعات مختصراً بیان کردہ ہیں۔ کربلا کے بعد زمانی لحاظ سے قریب ترین لکھی گئی مقتل کی دو کتابیں قابل ذکر ہیں، ایک مقتل لہوف اور دوسری مقتل ابی مخنف جو کہ شہادتِ امام کے بعد غالباً نصف یا پون صدی کے اندر اندر لکھی گئیں اور اکثر حوالے بہت قریبی تھے۔ یہ کتاب جو میں نے پڑھی کسی اسلامی مطبعے کی کاوش تھیں لیکن اس وجہ سے نامکمل محسوس ہوئی کہ تعارف اور دیباچہ کسی اچھے تاریخ شناس کا نہ تھا لہذا اس کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھ نہ سکا۔ البتہ اس کے پڑھنے سے پہلے سو جانی گئی معلومات کی نوعیت واضح ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مقتل کی ان دونوں کتابوں سے تعارف مجھے آئرش صحافی پیٹرک کاکبرن کی ایک کتاب سے ہوا تھا۔ اس کتاب سے مسلم بن عقیل کا ایک قول نقل کرنا چاہوں گا جو ان کا شہادت سے پہلے کا آخری مکالمہ ہے۔ ”اگر تُو مجھے قتل کرے گا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ تجھ سے ذیادہ ناپاک لوگوں نے مجھ سے ذیادہ بہتر افراد کو قتل کیا ہے۔“
”وحشیوں کا انتظار“ (ناول) جے ایم کوٹزی: افریقہ اور انڈیا اس کرہء ارض کے وہ اعضائے رئیسہ ہیں جنہیں لالچی سفید فاموں نے نوچ نوچ کر کھایا ہے۔ پھر ان کی تہذیبوں کو پہلے وحشت قرار دیا اور پھر تہذیب کے نام پہ انہیں اپنی وحشت سکھانے کی کوشش کی۔ یہ ناول انگریز کے اس احساس کمتری اور اس تہذیب دشمنی کے ماحول میں، جنوبی افریقہ میں اپنی ڈھلتی عمر کے بحرانوں سے لڑنے والے ایک ادھیڑ عمر انگریز افسر کی کہانی ہے جسے صدیق عالم نے بہت خوبصورتی سے ترجمہ کیا ہے۔
”میرواہ کی راتیں“ (ناولٹ) رفاقت حیات: مختصر ناول ہے اور ابتدائی سطور میں ہی قاری کو جکڑ کر ایک نشست میں ناول مکمل کرنے پر مجبور کرنے والا ڈکشن اور کہانی۔ اسے پڑھ کر میعاری فکشن کا لطف آیا۔جنس کے موضوع پر لکھنا اور جنس ذدگی دو الگ چیزیں ہیں جو مبتدیوں کو سمجھانے کی بات ہے، رفاقت صاحب یہ فرق بہتر سمجھ کر اس موضوع کو نبھا گئے ہیں۔ چھوٹی بستیوں میں نوعمری کی کتنی محبتیں اور خواہشیں (بقول محمد حنیف) اپنے ہی اندر کے بھُوتوں سے لڑ لڑ کر ماری جاتی ہیں، اسکی بے کلی اور دکھ انہوں نے خوب بیان کیا ہے… وہ دکھ اور بے کلی یوسفی صاحب کے الفاظ میں بدن کا دکھ ہے ”اور یہ سب کچھ اس لیے کہ وہ ٹھوس حقیقت جو ماورائے روح ہے یعنی جسم، اسے صدیوں سے اپنا حق نہیں ملا ہے، اسی لیے انسان بے کل ہے، دُکھی ہے“ (”زرگزشت“)۔ نذیر نامی لڑکے کی سندھ کے چھوٹے سے شہر ٹھری میرواہ میں گزرنے والی راتوں کی بے کلی کی یہ کہانی رفاقت صاحب کی خوبصورت ادبی کاوش ہے جسے ذوق والے قارئین ہمیشہ یاد رکھیں گے۔
”ملتے ہیں اگست میں“ (ناول) گیبریل گارشیا مارکیز: نوبل انعام یافتہ، لاطینی امریکا کے قدآور لکھاری مارکیز نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے راڈریگو کو کچھ مسودے دیے کہ بیٹا انہیں تلف کر دینا۔ بیٹے نے باپ کی دسویں برسی پر ان میں سے ایک ناول نکال کر چھپوا دیا۔ مارکیز کا خیال یقیناً یہی ہو گا کہ وہ جس میعار کی کہانیاں چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ اس میعار کی نہ ہو گی لیکن اس ناول کو لاطینی امریکا میں اتنا سیلیبریٹ کیا گیا کہ جیسے کسی قوم میں کوئی ولی اللہ اتر آیا ہے اور سارے اس کے استقبال کے لئے بے قرار ہیں۔ اس ناول کے راتوں رات انگریزی تراجم ہوئے اور ملین کی تعداد میں چھپے اور ایک ماہ کے اندر اندر انعام ندیم صاحب نے اس کا اردو ترجمہ بھی پاکستان (جہلم) سے شائع کرا دیا، پری آرڈر کروانے والے ہزاروں لوگوں میں آپ کا فدوی بھی تھا اور اس کی اشاعت کی آفیشل تاریخ سے ایک رات پہلے مجھے موصول ہوا، اشاعت کی تاریخ کے دن ہی اسے پڑھ ڈالا۔ مارکیز کی کسی تحریر پہ ریویو لکھنا آسان نہیں۔ یہ کہانی ایک عورت کی ہے اور اس کی یادوں سے جڑی ایک دنیا کی جو اس کے گھر سے دور ہے جہاں اس کا بچپن گزرا اور جہاں وہ ہر سال یادوں کے تعاقب میں جاتی ہے۔ جنس اس کا موضوع ہے، اور جیسا کہ شاید کہیں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جنس پہ لکھنا آسان نہیں اور اس پہ ریویو بھی اتنا آسان نہیں۔ مارکیز کی اس کہانی میں اس کی فنی عظمت بہرحال جھلکتی ہے۔
”پرورشِ لوح و قلم“ لڈمیلا ویسیلیوا: فیض احمد فیض صاحب کی زندگی اور ادب پر ان کی روسی دوست لڈمیلا ویسیلیوا نے یہ مقالہ خوب لکھا ہے۔ فیض صاحب کے فن، سیاسی زندگی اور جدوجہد پہ ایک جامع اور مستند کتاب ہے۔ اسے پڑھ کر دل باغ باغ ہوا۔ بھاری بھرکم ریویو کیا لکھوں، فیض کو ایک انسان، بیٹیوں کے باپ، بھائیوں کے بھائی، ایک شوہر، ایک شاعر اور ایک مجاہد کے طور پر اور بھی قریب سے جانا تو ان سے محبت بڑھی۔ جیل کے بے رحم شب و روز میں بیٹیوں کے نام ایک خط لکھا، جس کے اختتام ان کے لیے ایک لطیفہ لکھ بھیجا کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان تھمنے کے بعد کنارے لگی تو جانور اتر رہے تھے تو ہاتھی نے چیونٹی سے غصے ہو کر کہا، صبر بھی کرو، کیا مجھے پیچھے سے دھکے دیے جا رہی ہو۔ اللہ اکبر، کیا پیارے لوگ تھے!
”آخرِ شب کے ہمسفر“ (ناول) قرۃالعین حیدر: بنگال کے موضوع پر پڑھنا ہمیشہ پسند رہا ہے اور قرۃالعین حیدر کو پڑھنا مجھے اکثر مشکل لگا ہے جیسا کہ ”آگ کا دریا“ پڑھنے کی دو کوششیں ناکام ہوئیں مگر یہ ناول ایک بار جو شروع کیا تو اس نے دامن دل پکڑ لیا۔ بیسویں صدی کی تیسری دہائی کے بنگالی معاشرے میں مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس کے ہندو، مسلمان اور کرسچن گھرانوں کی لڑکیوں کی زندگی، مسائل، اس عہد کا سیاسی شعور، اس عہد کا ہندوستان، بنگالی قوم کی بغاوت اور آزادی کی دھن اور آزادی کے بعد کی مایوسی من حیث القوم اور انفرادی طور پر ایک دلچسپ موضوع ہے، پھر ساٹھ ستر کی دہائی کی عالمی شعوری تحریکیں اس کہانی کا موضوع ہیں مگر خوب روانی سے کہانی بیان کی گئی ہے۔ پلاٹ سادہ ترین لفظوں میں یوں ہے کہ تیس کی دہائی کی چار لڑکیوں کی زندگی کی کہانی جو مختلف سمتوں میں بکھر گئی۔
”برما کے جنگلوں میں سَو دن“ لیفٹیننٹ ایان میک ہورٹن، ترجمہ ریاض شاہد: جنگی ادب اگر میعار کا ہو تو کہانی کا ایک دلچسپ روپ ہے، اردو میں اس صنف کا دامن کافی تنگ ہے،سو کوئی اچھا ترجمہ مل جائے تو کیا ہی لطف ہے۔ یہ کتاب ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران برما میں لڑنے، جاپانیوں کے ہاتھوں قید ہونے اور وہاں سے فرار ہونے کی سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی جو ایک نو عمر لیفٹیننٹ میک ہورٹن نے بیان کی ہے اور ریاض شاہد صاحب نے ترجمہ کی ہے جسے فکشن ہاؤس نے شائع کیا ہے۔ یہ وہ ریاض شاہد فلمساز نہیں ہیں جو فلم ”زرقا“ کے بعد خوبصورت نیلو کو لے اڑے بلکہ یہ دنیائے ادب کے وہ گوشہ نشین درویش ہیں جو فلسفی دیوجانس کی طرح ایک چٹان پر بیٹھ کر مزے سے دھوپ سینک رہے کچھ سالوں سے میری رہنمائی فرما رہے ہیں، لکھنے لکھانے کے معاملے میں رہنمائی کے علاوہ مجھے مطالعے کے لیے بھی کئی بڑے ناموں سے انہوں نے ہی متعارف کروایا ہے اور جب جب میرے اندر کے لکھاری کو ڈھیلا پڑتا دیکھتے ہیں تو خوب سے چابی مروڑنا بھی انہی کو آتا ہے۔
”تنہائی کے سو سال“ (ناول) مارکیز: مارکیز کا شہرہء آفاق ناول ”تنہائی کے سو سال“ پہلی بار وبا کے دنوں میں پڑھا تھا مگرصرف تین ابواب، جو ”آج“ کے کسی شمارے میں تھے۔ گاؤں سے باہر سیلابی گزرگاہ والی دلدلی جھیل کے کنارے ایک غیر آباد دربار کے پہلو میں صف پہ دراز ہو کر پڑھا تھا ۔ تب سے مارکیز کی کہانیوں کیلئے میں نے ایک صحیفے کا سا پروٹوکول چُن لیا، اسے پڑھنے کے مناسک طے کئے کہ اسے جدید تمدن کی آلائشوں سے دور ہی بیٹھ کر پڑھوں گا۔ سو ان تعطیلات سے پہلے ہی ”تنہائی کے سو سال“ کا زینت حسام والا ترجمہ منگوالیا اور پہلی فرصت میں اسے پڑھا، گاؤں سے باہر اسی سیلابی دلدل کے کنارے جال کے پیڑوں میں جو ایک بنا چھت کے دربار گھرا ہے جس کے ساتھ چِلے کا ایک مقفل کمرہ اور ایک چھپر مسافروں، زائرین کے لئے ہے مختص ہے، اسکی پہلو کی دیوار میں ایک بڑا سا شگاف ہے جو جنگل اور سیلاب کی دی ہوئی قدرتی جھیل کی طرف کھلتا ہے، اسی کے سامنے کھجور کی چٹائی بچھا کر بیٹھ جاتا تھا اور کہانیوں کا لطف لیتا تھا۔ جمعرات کے دن کے علاوہ یہ جگہ ویران ہوتی ہے ماسوائے اسکے کہ دورانِ مطالعہ دلدلی جھیل سے مچھلیوں کے متلاشی پرندے، گلہریاں اور آس پاس بکھری قدرتی چراگاہوں میں رزق تلاش کرنے والی بھیڑیں بکریاں اور گائیں آپ کی مزاج پرسی کیلئے لمحہ بھر کو رُک جائیں یا کوئی بھلا مانس سانپ حال چال پوچھے بغیر پاس سے گزر جائے۔ یہاں بیٹھ کر میں نے بوئیندیا خاندان اور انکے بزرگ حوزے آرکادیو بوئندیا کے بنا کردہ گاؤں ماکوندو کی تاریخ کے سو سال اس طرح گزارے ہیں جیسے اپنی کہانی ہو۔ ادب پارے کی آفاقیت یہی ہوتی ہے کہ زمانی لحاظ سے پانچ صدیوں کا فاصلہ ہو یا مکانی لحاظ سے پانچ بر اعظموں کا فاصلہ ہو، کہانی اور سامع کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔
لاطینی امریکا کی سو سالہ ثقافتی تنہائی کی اس کہانی میں مغربی قارئین کے لئے تو میجیکل رئیلزم کا تڑکا ہی ہو گا لیکن آپ ہم اسے خوب سمجھتے ہیں کہ کیوں مارکیز کی کہانی کے کردار، ماکوندو کے لوگ ڈیڑھ سو سال عمر کے تھےپارس دھات بنانے کے شوقین، ناستریدمس کی پیشن گوئیوں پہ یقین رکھتے تھے اور وہ بوڑھے کیوں اتنی سنجیدگی سے کہتے ہیں کہ محرمات سے جنسی تعلق نہ رکھو، سور کی دُم والے بچے پیدا ہوں گے، ماں پہ ہاتھ مت اُٹھاؤ، ہاتھ جل جائے گا (اور مارکیز بھی جانتا ہے کہ اس نے یہ باتیں طنزیہ لہجے میں بھی کہی ہیں تو اس میں طنز کا عنصر کتنا ہے) وہ ریل کے آنے سے اتنے خوف ذدہ کیوں تھے اور خانہ بدوش ملکیادیس کی لکھی سنسکرت میں کیسے ماکوندو کی تقدیر پنہاں تھی۔ یونائیٹڈ فروٹ کمپنی کی حکومت اور فوج نے مل کر جو ہزاروں مزدور مار دئیے ، آپ کے میرے ذیادہ قریب کی باتیں ہیں کیونکہ یونائیٹڈ فروٹ کمپنی کی بدولت ہی ’بنانا ریپبلک‘ کی اصطلاح مروج ہوئی اور مغربی سرمایہ دار استعمار کی کارپوریٹ اور ان کے مفادات کے محافظ جرنیلوں کے ہاتھوں آپ کی ہماری دھرتی نے جو دُکھ اٹھائے ہیں، یہ ماکوندو میں کیلے اُگانے کیلئے آنے والے گوروں کے اجمال سے کتنا ملتا جُلتا ہے، فرق یہ ہے کہ آپ ہم بس نتھنے پھلانے جوگے ہیں، کرنل اوریلیانو بوئندیا اور کرنل جیرینالدو مارکیز تلواریں اٹھانے والے دیہاتی اور سپاہی بچہ تھے۔ ریمیدیوس، میمی، امارانتا ارسلا، ربیکا اور سانتا صوفیہ دی لا پائداد کے نسوانی کرداروں کی محبتوں، رقابتوں، جنس زدگی، بکارت اور تنہائی کی کہانیاں بھی ہمارے آس پاس بکھری پڑی ہیں، ارسلا اگواران اور پیلارتر نیرا جیسی طویل العمر بوڑھیوں کی سو سال لمبی اخلاقی جنگ یہاں بھی سماج کے ہر کونے کھدرے میں لڑی جا رہی ہے۔ الغرض یہ ہماری نئی نسل کے پڑھنے کا ناول ہے اور ہماری ہر نسل کے پڑھنے کا ناول۔
نفسیات، معاشیات، تاریخ، لاطینی امریکا، غرب الہند اور کریبئین کے خطوں کی جیاگرافی اور نجانے کتنے علوم کے لوگوں کیلئے اس شہرہ آفاق ناول میں دلچسپی، تنقید اور تحقیق کے کتنے ہی در کھُلے ہیں جبکہ ہم ایسے درویش، سپاہی، آوارہ گرد ، عشاق دیہاتیوں کیلئے اس میں سرمستی اور نشے کی سی ایک کیفیت ہے جس کے سبب میں اس ناول کے پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔
”سخندانِ فارس“ مولوی محمد حسین صاحب: آزاد کی کتاب جو فارس سے ہندوستان تک فارسی زبان، اس کے دوسری زبانوں کے ساتھ ارتباطِ باہمی، بالخصوص سنسکرت سے مماثلت اور اس کی تاریخ کے موضوع پر کیا ہی خوبصورت کتاب ہے جو پڑھنے کی چیز ہے۔ اس میں ایک واقعہ درج کرتے ہیں جو کہ وسط ایشیا کے مسلمانوں کی جنگجویانہ طبیعت پر بھی ادب اور شعر کے غلبے کی خوبصورت مثال ہے۔ فتح علی شاہ قاچار کا عہد تھا، کسی علاقے کے دورے پر نکلے تو وزیر مختار نے بڑے فخر سے شہسواروں کا ایک دستہ دکھایا کہ خصوصی فوجی تربیت سے گزارا گیا ہے، لڑنے میں کمال ہے اور کیا کمال کا نظم و ضبط ہے۔ یہ سن کر ایک درباری شاعر پرے جا کر ٹیلے پہ چڑھا اور الحان میں یہ شعر پڑھا؛
اے جوانانِ لُرستان بشنوید از من کہ من
یاد دارم داستانہا از نیاگانِ شما!!
اس پہ تو دستہ فوراً برخاست ہوا اور اپنے نیاگان کی داستانیں سننے کو بے قرار اس جانب دوڑا۔ سو ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم بھی آزاد کے قصہ کہنے کے انداز سے مسحور ہو کر سپاہ چھوڑ کر اردو کی طرف آئے تھے، تو شاید ہمارا یہ دعویٰ کچھ غلط بھی نہیں۔
”شمال کی جانب ہجرت کا موسم“ (ناول): سوڈانی لکھاری طیب صالح کی شاندار کہانی جس میں اعلیٰ عالمی ادب کے سارے عناصر موجود ہیں۔ سعید مصطفیٰ نام لے ایک سوڈانی کی کہانی جو افریقہ سے یورپ گیا اور پھر کہاں گیا، اس مسٹری کے آس پاس گھومتی یہ کہانی یورپ اور افریقہ کے تاریخی ربط پہ بھی بات کرتی ہے، یہاں کے لوگوں کے احساسات کی ترجمانی بھی کرتی ہے اور وہاں والوں کی کرتوت بھی بتاتی۔ فرد کی کہانی ہے جسے شاید ادبی اصطلاح میں نفسیاتی ناول بھی کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ارجمند آرا نے کیا ہے اور بہت میعاری ترجمہ ہے، ارجمند آراء کے تراجم پہ کلام کی گنجائش نہیں۔
”بکربیتی“ (ناول) بن یامین: یہ ناول جن دنوں پڑھا ان دنوں اس بننے والی فلم کی دھوم نہیں ہوئی تھی یا شاید ہنوز بنی بھی نہیں تھی۔ خیر گزری کہ پہلے پڑھ لیا ورنہ شاید اس پہ فلم بن جانے کے بعد جی کھَٹا ہو جاتا۔ ناولوں پہ بننے والی فلم کے بارے میں ارنسٹ ہیمنگوے بہت سخت الفاظ استعمال کر چکا ہے۔ بس یہی کہوں گا کہ فلم کبھی اصل کتاب سے انصاف نہیں کر سکتی۔ یہ کہانی ہے ایک بھارتی شہری کی جو انیس سو نوے کی دہائی میں عرب سرزمین پر نوکری کی تلاش میں گیا اور وہاں اسے ایک سنگ دل عرب کے مویشیوں کے باڑے میں بکروں، بکریوں کی رکھوالی پہ متوین کر دیا گیا۔ شدید جبر اور جانوروں جیسی زندگی کے ان تجربات کو پڑھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ سرمایہ دار دنیا کس طرح تیسری دنیا سے آنے والوں کا استحصال کرتی ہے، اس میں عربی اور انگریزی بولنے والی اقوام کا الگ الگ انداز ہے، اس کہانی میں عربی بولنے والوں کا وہ بھیانک روپ ہے۔ اس ناول اور اس کی کہانی پہ بعد میں بہت اختلاف رائے اور دانتا کل کل ہوئی مگر کہانی بہت شاندار ادب پارہ ہے۔ ابتدائی طور پر ملیالم زبان میں لکھی گئی ہے اور اردو ترجمہ عاصم بخشی صاحب نے انگریزی سے کیا ہے اور نہایت رواں ترجمہ ہے۔
”بہائنڈ دا مِتھ آف تھری ملین“ (انگریزی) ڈاکٹر محمد عبدالمنعم: بنگالی پروفیسر عبدالمنعم جن کا نام مشرقی پاکستان میں پچیس مارچ انیس سو اکہتر کی رات ڈھاکا یونیورسٹی میں پاکستان آرمی کے ایکشن میں مارے جانے والے اساتذہ میں شامل کیا گیا تھا، انہوں نے اس بھیانک رات کے تقریباََ بیس سال بعد ایک کتاب لکھی ہے ، نہایت مختصر اور جامع جس میں مجیب حکومت کے اس جھوٹے دعوے کو پاش پاش کیا ہے کہ مشرقی پاکستان کی جنگ میں تین ملین بنگالی شہید ہوئے۔ چھپن ہزار سے زیادہ کا نمبر تو وہ کمیٹی بھی نہ بڑھا سکی جسے جنگ کے بعد شیخ صاحب نے مقتولین کی تعداد کا تعین کرنے کیلئے مقرر کیا تھا۔ اس جھوٹ کا منبع کیا تھا؟ بات کہاں سے شروع ہوئی، یہ ہوائی کس نے اڑائی، شیخ صاحب نے اسے کس طرح کیچ کیا اور کس کس طرح کیش کیا، یہ سب قصہ اس میں ملے گا۔ اسی طرح عصمت دری اور لوٹ مار کے معاملے میں بھی شیخ صاحب کے جھوٹے دعووں کی قلعی کھولی ہے۔ افسوس کی بات کہ بنگالی عوام نے قربانی بھی دی اور شیخ صاحب نے ایسے جھوٹ بول کر ان قربانیوں کو مذاق بھی بنایا۔
”سنٹرل چوک“ (فکشن، فیکشن، خاکے) نیر مصطفیٰ: نیر مصطفیٰ صاحب نے اپنی کتاب ”سنٹرل چوک“ ان دنوں میں بھیجی جب کتاب سے خواندگی کا رشتہ ٹُوٹ چکا تھا اور بہت دن ہو چکے تھے کہ کچھ نہیں پڑھا تھا (خواندگی کا رشتہ اس لئے کہا کہ سرہانے، میز پہ، اپنے ہینڈ بیگ میں کتابیں موجود تھیں لیکن پڑھنے کا دماغ رخصت ہو گیا تھا) لیکن اس سے فلیش فکشن پڑھا، روشنی کے چند جھماکے ہوئے اور طبیعت رواں ہوئی۔ کچھ کتابیں تصویرِ یار کی طرح ہوتی ہیں کہ جب ذرا گردن جھکائی، دیکھ لی۔۔۔ یعنی آرام سے پڑھیں، لطف لے کر پڑھیں، جہاں کام کاج کا وقفہ آیا، رکھ دیں کیونکہ وہ دامنِ دل تو پکڑتی ہیں، گریبان نہیں دبوچ لیتیں۔ مگر پھر بھی اپنی فضول اور غیر علمی مصروفیات اور دلچسپیوں کے باوجود اس کتاب کو پڑھا تو مجھے اس کے توسط سے فلیش فکشن کی صنف سے تعارف ہوا۔ عنوانات ہی کھینچے جا رہے تھے۔ یہ کتاب متعدد حصوں پر مشتمل ہے؛ فکشن، فلیش فکشن، افسانہ، انشائیہ، دیباچے، خاکے اور فیکشن (عنوانات کے اعتبار سے تین حصے ہیں، غلام باغ، پھندنے اور دھنک) ۔۔۔
مصروفیت یا بیکار مصروفیت کے اس عہد میں ہر انسان کو ادب کی کچھ ڈوز چاہیئے ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ افسانے کی طرح فلیش فکشن بھی ایک مصروف سماج کی محدود ادبی ضرورت کی پیداوار ہے۔ نیر صاحب نے اس محدود سپیس میں لامحدود تخیل اور فکر کو سمو دینے کی شاندار کوشش کی ہے، میں نئے قارئین کو اس کے مطالعے کی دعوت دوں گا۔ فیکشن اور خاکوں کا لُطف البتہ میں نے سب سے زیادہ لیا۔ اس میں خود نوشت کے عنصر کا لطف لیا۔ اور جہاں جہاں خود نوشت کا رنگ تھا، میں شرمایا کہ کیا کہوں، ’ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں‘۔ ہم پچھلی صدی کے آخری لمڈے ایک دوسرے سے اجنبی ہو کر بھی ایک دوسرے کے ہمراز ہوتے ہیں۔ اپنے پردے میں اُس نسل کے تجربوں پہ نیر صاحب نے جو لکھا، خوب لکھا۔ ان میں ایک جہان آباد ہے۔ ان کی تحریر میں جہاں جہاں خاکے کا رنگ آیا، یا ایک مکمل خاکہ لکھ ڈالا (نیر صاحب کونسا کسی ہیئت کے قیدی معلوم ہوتے ہیں؟) ان میں دلداری کا ایک ایسا رنگ ہے کہ رشک آتا ہے۔۔۔ دلداری اس عہد کے انسان کی سب سے بڑی پیاس ہے، کاش سارا ادب یہی خدمت کرے۔۔۔ جہاں جہاں انشائیے کا رنگ آیا وہاں فلسفے کی کارستانیوں کے باوجود ڈکشن کا لُطف لیا۔ کامیو، سارتر، ہومر، کافکا کی رفاقت میں بھی دونوں اسلوب مل سکتے ہیں، شُدھ روایت کی اُردو بھی اور ملتان یا بہاولپور کے کسی مرکزی چوک میں چائے خانے پر بیٹھے ایک انٹلکچوئل کی اردو بھی جو لڑکپن میں بھارتی فلمیں شوق سے دیکھتا تھا۔ سو جب وہ کہتے ہیں کہ ”ان کی طرح میری زندگی کا تمبو بھی مزاحمت کے بمبُو پہ کھڑا تھا“ تو ہم ہنس دیتے ہیں، تلمیح و استعارہ پا جاتے ہیں اور جب وہ کہتا ہے کہ ”میں فرہاد کو تیشے کے علاوہ کسی چیز سے مرنے کی اجازت دینے پر تیار نہ تھا“ تو اس روایت پسندی اور روایت کے اسلوب کا لُطف بھی ہمی لیتے ہیں۔۔۔ یہ کتاب ہاتھ آ جائے تو آپ بھی لیجئے شاگردانِ عزیز، یہ ہماری نسل کے آخری آخری لوگ ہیں۔
”اَن کہی جدوجہد“ (آپ بیتی) کرنل شریف الحق دالیم: مشرقی پاکستان کے المیے پر اکثر لوگوں نے پاکستانی لکھاریوں کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں یا گوروں کی۔ اس پہ بنگالیوں کو پڑھنے سے نئی باتیں پتہ چلیں گی، حتیٰ کہ وہ باتیں بھی جو ہمیں جب تک بنگالی نہ بتائیں، ہم خود بھی نہیں مانتے۔ شریف الحق دالیم صاحب بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کے صف اول کے مجاہد تھے اور وہ بنگلہ دیش کی تخلیق اور آغاز کی تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ان فوجی افسروں میں شامل تھے جن کے خیال میں جنرل نیازی کو بنگلہ دیش کے آرمی کمانڈر کرنل عثمانی کے سامنے ہتھیار ڈالنے چاہیئں تھے کیونکہ بنگلہ دیش ایک آزاد ملک کی حیثیت سے جنگ لڑ رہا تھا لیکن جنرل اروڑہ کے سامنے سرنڈر کروا کر پینسٹھ کی شکست اور تذلیل کا بدلہ لینے کیلئے بھارت نے یہ جو ڈرامہ رچایا یہ بھارت کے خبثِ باطن پر مبنی تھا اور مکتی باہنی کے لیڈروں اور آزادی کے تقریباََ سبھی مجاہدوں نے اس تقریب کا بائیکاٹ کیا تھا اور اس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ انہیں جنگ ختم ہونے کے بعد مشرقی پاکستان سے لوٹ کا مال بھارتی فوج کے ٹرکوں میں لادنے والے مجیب کے ٹولے پر بہت غصہ تھا اور انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھا کر شیخ مجیب کو ناراض بھی کیا تھا۔ان کی گواہی بہت اہم ہے کہ وہ شیخ مجیب کے قریبی عزیز اور تعلق دار تھے، فوج اور سیاست کی فیصلہ سازیوں کو قریب سے دیکھنے والے۔ جیسا کہ ان کا بتانا کہ آزادی کی تحریک مجیب کی جدوجہد ہرگز نہ تھی، مکتی باہنی اور عوامی لیگ کسی صورت بھی بنگال کے عوام کی ہردلعزیز جماعتیں تھیں نہ آزادی کے مجاہد۔ آزادی کے اصل مجاہدوں کو آزادی کے بعد کس طرح ذلیل کیا گیا، آزادی کے نام پہ شیخ مجیب نے کس طرح پاکستان اور بنگلہ دیش، دونوں سے غداری کی، یہ ایک دلچسپ قصہ ہے اور افسوس ناک بھی۔ آزادی کے بعد کے بنگلہ دیش کی تاریخ کے اولین سال بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، دیکھیے کس طرح ایک قوم کے جوشیلے اور مخلص جوان قربانیاں دے کر آزادی حاصل کرتے ہیں اور کس طرح ایک مخصوص اشرافیہ پہلے سے گدھ بن کر آزادی کے ثمرات پہ نگاہیں گاڑے بیٹھی ہوتی ہے۔ اوراس میں آج بھی ہمارے لیے اسباق ہیں۔
”صورت و معنیء سخن“ (تنقیدی مضامین) شمس الرحمان فاروقی: مجھے تنقید پڑھنے کا دماغ نہیں مگر فاروقی صاحب کی تنقیدی مضامین کی اس کتاب نے دل کھینچ ہی لیا۔ یہ کتاب بوجوہ جزوی طور پر پڑھی گئی ۔ اس میں سے لگ بھگ نَو مضامین پڑھے جن میں افسانے کی حمایت میں، نئی صدی میں افسانے کے اسکوپ پہ اور فکشن پہ لکھے گئے دیگر مضامین بہت دلچسپ ہیں اور تنقید کے عمومی خشک اور ناصحانہ انداز سے بہت ہٹ کر لکھے گئے ہیں۔
”خواہ مخواہ کی زندگی“ (افسانے) رفاقت حیات: رفاقت حیات صاحب سے جان پہچان تو اب پیدا ہوئی ہے لیکن ان کی جس تحریر نے پہلا نقش میرے ذہن پر کہیں چھوڑدیا تھا، وہ دس سال پہلے پڑھا گیا ان کا افسانہ ”چَریا ملک“ تھا۔ جنگ میں ایک ٹانگ کھو دینے والے ایک بوڑھے سپاہی کی کہانی پڑھتے ہوئے جب غُصے میں گرجتے ملک صاحب کی گالی میرے ذہن میں گونجی ”ساریاں نی ماؤ نا جُتھا!“ تو میں لمحے بھر کو ٹھہرا! یہ کہانی دس سال پہلے پڑھی تھی، مگر اب پڑھنے پر یاد آیا کہ یہ قصہ میرے لاشعور کے کسی نہاں خانے میں پڑا تھا مگر کہیں ایسا تو نہیں کہ اکہتر کی جنگ ، بلکہ ہر جنگ کے بعد کے نیم پاگل سپاہیوں پہ لکھا جانے والا میرا افسانہ ”شکست“ کہیں اس سے متاثر ہو؟ ممکن ہے! اگرچہ ”شکست“ لکھتے ہوئے یہ کہانی میرے حافظے سے محو ہو چکی تھی۔ اور اس مجموعے میں اس سے کہیں برتر افسانے ہیں، میں تو اپنی ڈفلی بجانے بیٹھ گیا۔
پہلے افسانے ”بچھڑی کونج“ نے ہی اثر دکھایا اور وہ اثر پذیری آخری افسانے تک چلی۔ آڑھتی کا بیٹا اور ریٹائرڈ سرکاری افسر جو لکھاری ہے، اس کی کہانی ٹھیک، مگر رفاقت حیات عام آدمیوں میں سے بھی عام تر بلکہ بقولِ فیض جو مردودِ حرم انسان ہیں، ان کی نفسیات پہ انہی لوگوں کےسے سادہ ڈکشن میں اُن کی اَن کہی کہانی بیان کرنا جانتے ہیں، قاری کو منظر اور کیفیت کی گہرائی تک لفاظی اور فلسفے کے غوطے کے بغیر پہنچانا ان کا فن ہے جس پہ مَرتا ہوں۔ ایک غریب کنڈیکٹر کو، جسے کبھی کسی نے ہنس کر نہیں بلایا، ایک مسافر سے انڈونیشی سگریٹ کا تحفہ ملتا ہے تو اس کی کہانی آپ کو رفاقت صاحب سُنا سکتے ہیں۔ کرائے کے مکان میں رہنے والے کی زندگی کس آزمائش کا نام ہے، آپ ہم اس پہ سینکڑوں باتیں کر لیں گے مگر ”ایک اور مکان“ جیسا افسانہ رفاقت صاحب لکھ سکتے تھے۔ ہمیں عورتوں کے نازک اور عمیق جذبات سمجھنے کا دعویٰ تو شاید نہیں ہو سکتا لیکن کچھ سمجھ بھی لیں تو عورت کے ان جذبات کی کہانی صیغہ واحد متکلم مؤنث میں لکھنا اور ”پیل دوج کی ٹھیکری“ جیسا افسانہ لکھنے کا فن ہم رفاقت صاحب سے سیکھیں گے۔ افسانے ”ہَرے دروازے والا مکان“ کے عقیل بیگ جیسے کردار آپ ہم ،سبھی میں چھُپے ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہیں لیکن ان کو کہانی حنوط کر کے رکھ لینے کا قرض ادیب پر ہوتا ہے، کس کس افسانے کی مثال دوں، اس افسانوی مموعے میں رفاقت صاحب نے سماج کے اُن اندھیرے گوشوں میں جھانکا ہے جو آپ کی ہماری نگاہوں کے سامنے ہو کر بھی اوجھل ہیں، پھر ذرا سُنیے انہوں نے ان گوشوں کے بارے میں ہمارے کانوں میں کیا میٹھی سرگوشی کی ہے، یہ کتاب پڑھیئے۔ لیکن ایک بات جملہء معترضہ کے طور پر ۔ آخر پہ ”افسانہ نگار کی کہانی“ کا جو ایک باب ہے، کاش کہ وہ اور بھی طویل اور تفصیلی ہوتا۔ اس کے پڑھنے کا لطف عروج پر تھا کہ کہانی کار کی بات مکمل ہو گئی۔ آپ کی اس اختصاپ پسندی کے قربان جاؤں میرے اچھے کہانی کار، یہ کہانی کچھ اور بھی بڑھا دیجیئے!
”انمول موتی“ (ترجمہ) جان اسٹین بیَک: نوبل انعام یافتہ لکھاری جان ارسنٹ سٹین بیک کا مختصر ناولٹ ”دَ پَرل“ مشہور ہے، مختصر ہے، سو یقیناََ آپ نے اسے پڑھ رکھا ہو گا۔ ریڈ انڈین یعنی اصلی امریکیوں کی زندگی کے توہمات، دُکھ سُکھ اور قسمے کے پھیر کی ایک خوبصورت مگر اداس کر دینے والی کہانی۔ کینو نامی ایک غواص کو ساحل کی ریت میں ایک صدف ملا جو کہ دنیا کا خونصورت ترین موتی تھا۔ یہ اس کی کہانی ہے جو کہ اس کے گاؤں میں اس کے بعد صدیوں تک گونجتی ہے، نسلوں کو یاد رہتی ہے۔ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔
”ٹُوٹے پھوٹے لوگوں کی فیکٹری“ (افسانے) از نیّر مصطفیٰ: نیّر مصطفیٰ کی کارگہِ فکر میں کبھی انجم بنتے ہیں تو کبھی شہابیے۔ ان کی یہ کتاب بھی انہی ٹوٹے ہوئے ستاروں کی کتاب ہے جو کہ آپ کے، ہمارے آس پاس کے روزمرہ کے کردار ہیں، وہ لوگ جو زمیں زاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے لیکن وہ ایک ٹوٹے ہوئے ستارے کی طرح روشنی کی ایک ادھ موئی کرن چھوڑ کر تاریکیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ نیّر مصطفیٰ روشنی کی ان لکیروں کو کہانی میں پرو دیتے ہیں۔ تبھی تو افسر حسین کلرک، بخاری صاحب، کامریڈ شاہد، چارلی مصور، سویرا، عمران مینگو اور ٹیچر عذرا شاہین جیسے ان گنت کرداروں کی کہانیاں اس افسانوی مجموعے میں در آئیں۔ یہ وہ ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں جو ہمارے آس پاس پائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی مکمل نہیں ہے، بقولِ نیّر مصطفیٰ گونگے وکیل، اندھے منصف، اپاہج کھلاڑی اور سرِراہے جس لڑکے سے دل کی بات کہنے کا سوچیے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے کان ہی نہیں ہیں۔ نیّر مصطفیٰ کے افسانوں میں علامت بھی ہے اور صاف اظہار بھی ہے۔ کچھ جذبے ادب آداب کے سانچوں میں ڈھلے تو نیّر انہیں علامت میں سمو کر کہہ گئے ہیں اور کچھ حقیقتیں بے شرمی کی حد تک عیاں اور برہنہ تھیں تو انہوں نے انہیں ایسے ہی صریح ڈکشن میں کہہ دیا مگر دونوں صورتوں میں کہانی کا چلن برقرار رکھا ہے کیونکہ وہ کہانی پہ اپنی پکڑ بھی ڈھیلی نہیں کرتے۔ نئی صدی کے انسان کے نئے دکھ نئے جاموں میں لپٹ کر آ رہے ہیں تو بظاہر ناسٹلجیا اور یادوں کے سحر میں گُم نیّر مصطفیٰ جدت کی جست لگاتے ہیں اور نئی تکنیک، نئے ڈکشن اور نئے نظامِ افکار کے ساتھ ان دُکھوں کو کہانی کرتے ہیں۔ ان کا اسلوب بے باک ہے، دلچسپ ہے اور پڑھنے کے لائق ہے۔ پڑھیے، تاکہ آپ بھی جانیں کہ جاننے کے کرب سے گزرنے والے لکھاری کیا جانتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں اور پھر مقدور ہو تو اس کرب کی آنچ کو محسوس کیجیے۔ نیّر مصطفیٰ ہی کی کہانی سے ایک ڈائلاگ: ”جانِ عزیزی! زندگی محض لاعلمی کے سہارے گزاری جا سکتی ہے! جان کر تو صرف متلی کی جا سکتی ہے، لہو تھوکا جا سکتا ہے، راکھ اڑائی جا سکتی ہے اور بس!“